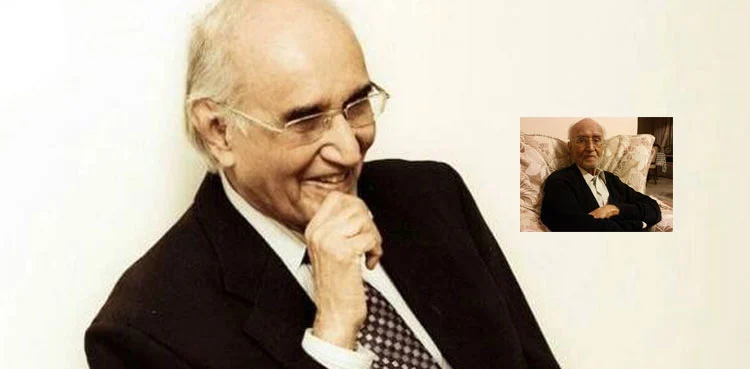اردو زبان میں رومانوی کہانیاں، تاریخی اور سماجی موضوعات پر ناولوں کے ساتھ جاسوسی ادب خوب لکھا گیا، اور اس میدان میں کئی نام گنوائے جاسکتے ہیں جن کو تقسیمِ ہند سے قبل اور بعد میں بڑی مقبولیت حاصل ہوئی، لیکن سائنس فکشن کا معاملہ کچھ مختلف رہا ہے۔ اگرچہ تقسیمِ ہند سے قبل بھی اردو زبان میں سائنس فکشن لکھا گیا اور مقبول بھی ہوا، لیکن اس میدان میں کم ہی نام سامنے آئے۔ انہی میں ایک خان محبوب طرزی بھی ہیں جن سے اردو ادب اور ناول کے قارئین کی اکثریت واقف نہیں ہے۔
خان محبوب طرزی کی حیات، ان کے فن اور نگارشات کی تفصیل میں جانے سے پہلے یہ جان لیں کہ وہ تقسیمِ ہند کے بعد چند برس ہی زندہ رہے اور اس وقت تک سائنس فکشن صرف تجسس اور مہم جوئی تک محدود تھا اور سائنسی نظریات یا کسی خاص تھیوری سے متأثر ہو کر بہت کم ناول لکھے گئے، لیکن دنیا بھر میں سائنس فکشن اور بامقصد ادب تخلیق ہو رہا تھا۔ اردو میں بہت بعد میں سائنسی نظریات اور ان کی بنیاد پر ہونے والی ایجادات پر کہانیاں لکھی گئیں۔ کچھ ادیبوں نے اپنے قاری کی دل چسپی اور توجہ حاصل کرنے کے لیے خاص طور پر سائنسی مفروضے، چونکا دینے والے آلات یا انوکھی مشینوں کو اپنے ناولوں یا افسانوں میں پیش کیا اور چند ایسے تھے جنھوں نے اپنے تخیل کے سہارے ایسی حیران کن کہانیاں لکھیں جن کا ایک عام آدمی اس زمانے میں تصور بھی نہیں کرسکتا تھا۔
خان محبوب طرزی کا سنہ پیدائش 1910ء ہے۔ وہ اردو کے ان اوّلین مصنّفین میں سے ہیں جو اپنے سائنس فکشن ناولوں کی بدولت مقبول تھے۔ اس کے علاوہ وہ کئی تاریخی، جاسوسی اور مہم جوئی پر مبنی ناولوں کے بھی خالق تھے۔ محبوب طرزی ہندوستان کے مشہور نسیم بک ڈپو، لکھنؤ سے وابستہ رہے۔
ان کا تعلق افغانستان کے تاتارزئی قبیلے سے تھا اور اسی نسبت سے وہ اپنے نام کے ساتھ طرزی لکھتے تھے۔ ان کے آبا و اجداد بعد میں ہجرت کر کے لکھنؤ چلے گئے تھے اور وہیں محلہ حسین گنج میں خان محبوب طرزی نے آنکھ کھولی تھی۔ انھوں نے ابتدائی تعلیم ویسلی مشن اسکول میں حاصل کی اوراس کے بعد اسلامیہ کالج سے ہائی اسکول کا امتحان پاس کیا۔ بعد میں وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی گئے جہاں سے بی ایس سی کی ڈگری حاصل کی۔ علی گڑھ میں ہی وہ لکھنے کی طرف مائل ہوئے اور افسانہ نگاری کا آغاز کیا۔ ان کے افسانے اپنے دور کے معروف ادبی پرچوں اور جرائد میں شایع ہونے لگے۔
خان محبوب طرزی کو ایک بسیار نویس کہا جاتا ہے اور اس کی ایک وجہ بڑے کنبے کی وہ مالی ضرویات بھی تھیں جن کو ایک سربراہ کی حیثیت سے محبوب طرزی کو بہرحال پورا کرنا تھا۔ سو، انھوں نے کئی کہانیاں دوسروں کے نام سے بھی لکھیں۔ انھوں نے کچھ عرصہ کے لیے قفل سازی کے ایک کارخانے میں سپر وائزر کے طور پر کام کیا۔ فوج میں اسٹور کیپر رہے، فلم سازی اور ہدایت کاری میں بھی خود کو آزمایا۔ کلکتہ کی کار دار کمپنی میں اسسٹنٹ کے طور پر کام کیا اور آر پی بھارگو کے ساتھ رقص و موسیقی کا پروگرام’’پرستان‘‘ کے نام سے پیش کیا۔ کچھ مدت تک لکھنؤ ریڈیو اسٹیشن سے وابستہ رہے۔ دوسری عالمی جنگ کے اختتام پر انھوں نے سائنیٹون فلم کمپنی میں ملازمت کی۔ پھر 1948ء میں خود فلم کمپنی قائم کی مگر کام یابی نے ان کا ساتھ نہ دیا۔ نسیم انہونوی ان کے ایک ایسے شناسا تھے جو سمجھتے ہیں: "طرزی صاحب میرے خیال سے جس کام کے لیے پیدا ہوئے تھے وہ انھیں نہ مل سکا۔ وہ کام تھا فلم کا ڈائریکشن۔ میں نے طرزی صاحب سے بار بار کہا کہ طرزی صاحب ایک بار بال بچّوں کو بھول کر گھر سے راہِ فرار اختیار کیجیے اور بمبئی کی فلم کمپنیوں میں رسوخ حاصل کرنے کی کوشش کیجیے۔” طرزی صاحب یہ نہیں کر سکے اور اخراجات کی فکر سے ہلکان ہوتے رہے۔
خان محبوب طرزی کی علمی اور ادبی دل چسپیوں میں ترجمہ نگاری اور صحافت بھی شامل تھی۔ انھوں نے روزنامہ اودھ، روزنامہ اردو اور بعض دیگر اخبارات میں بھی کام کیا۔ یہاں بھی آسودگی ان کا مقدر نہ بنی۔ اور پھر وہ ناول نگاری میں پوری طرح مشغول ہوگئے۔ امین سلونوی جن سے خان محبوب طرزی کا بہت قریبی تعلق رہا، وہ کہتے ہیں: "وہ کہیں بھی رہے ناول نگار ہی رہے۔
اگر اسے طرزی صاحب کا امتیازی وصف کہنا غلط نہ ہو تو وہ ایک ساتھ کئی ناول لکھنے والے بسیار نویس تھے۔ مائل ملیح آبادی کے بقول: "وہ بے پناہ لکھنے والے تھے۔ ان کا ہاتھ ٹائپ رائٹر تھا۔ لکھنے لگتے تھے تو لکھے ہوئے کاغذوں کا ڈھیر لگا دیتے۔ سب لوگ باتیں کرتے رہیں لیکن طرزی صاحب وہیں بیٹھے لکھتے رہیں گے اور کاغذ کے بعد کاغذ قلم کے نیچے سے نکلتا رہے گا… انہوں نے گھنٹوں کے حساب سے بھی دو تین سو صفحات کے ناول لکھے ہیں۔ لگ بھگ بارہ سو صفحات کا ناول مہینہ ڈیڑھ مہینہ میں کسی دوسرے مصنّف کے نام سے لکھ ڈالا۔ پھر اس کے بعد ہی سترہ اٹھارہ سو صفحات کسی اور مصنّف کے نام سے لکھ دیے۔”
طرزی کی ناول نگاری کے بارے میں سلامت علی مہدی کہتے ہیں: "دنیا کی کسی زبان میں ایسا کوئی ناول نگار نہیں ہے جو تاریخی ناول بھی لکھے اور جاسوسی ناول بھی۔ جو دن کے ابتدائی حصے میں کسی سائنسی ناول کا مسودہ لکھے، دن کے آخری حصّہ میں کسی معاشرتی ناول کا حصّہ پورا کرے اور رات کو کسی رومانی ناول میں عورت کے حسن اور اس کے محبت بھرے دل کی کوئی نغمگیں کہانی بیا ن کرے۔”
بیک وقت تین چار مختلف موضوعات پر کہانیاں بُننا بھی طرزی صاحب ہی کا کمال تھا۔ ہندوستانی ادیب احمد جمال پاشا نے لکھا ہے: ’’بات لکھنے لکھانے پر آئی تو عرض کرنے دیجیے کہ وہ دو تین دن میں چار پانسو صفحات کا ناول لکھ لیتے تھے جب کہ دوسرا محض لکھا ہوا ناول اس مدت میں نقل بھی نہیں کر سکتا۔ لطف یہ ہے کہ ان کے روز مرہ کے معمولات میں بھی فرق نہ آنے پاتا۔ خود بقول ان کے وہ لکھتے کیا تھے، اپنی تھکن اتارتے تھے۔ اسی کے ساتھ ساتھ سائنسی موضوعات و اسلامی سیاست پر مضامین بھی لکھتے رہتے۔ تقریباً تین سو کتابیں وہ ہیں جو خود ان کے نام سے چھپیں اور کتنے ناول لوگوں نے خرید کر اپنے نام سے چھپوا لیے اور مصنّف کہلائے۔‘‘
خان محبوب طرزی کے قلم سے سیکڑوں ناول نکلے اور بڑی تعداد میں فروخت بھی ہوئے، لیکن بحیثیت ایک قلم کار وہ آسودگی ان کا مقدر نہیں بن سکی جس کے لیے وہ دن رات لکھنے میں مشغول رہے۔ اس مقبول ناول نگار نے 25 جون 1960ء کو یہ دنیا ہمیشہ کے لیے چھوڑ دی تھی۔
ان کا ایک ناول "اڑن طشتری” 1952 میں شایع ہوا تھا جس میں انھوں نے مسلمانوں کی شان دار تاریخ اور اسلاف کے کارناموں کو رجائیت پسندی کے ساتھ پیش کیا۔ اس ناول کا مرکزی خیال یہ تھا کہ نویں صدی عیسوی کے آخر میں اندلسی مسلمانوں کی سائنسی ایجادات سے دنیا ششدر رہ گئی ہے۔ اور موجودہ دور کے سائنس داں بھی ان ایجادات پر دنگ ہیں۔ ایک اندلسی انجنیئر اڑن طشتری بناتا ہے اور اپنے چالیس ساتھیوں کے ساتھ اس کے ذریعے ایک نئی دنیا میں جا کر آباد ہوجاتا ہے۔ پھر دورِ حاضر کا ایک سائنس داں ٹیلی ویژن کی مدد سے اس سیارہ کا پتہ لگا کر اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو لے کر وہاں پہنچتا ہے۔ ان کے اس ناول کے زیادہ تر کردار مسلمان ہی ہیں۔ ان کا یہ ناول ان کے مذہبی تشخص اور اس تفاخر کو اجاگر کرتا ہے جس کا بحیثیت مسلمان وہ شکار رہے کہ دوسرے سیارے پر بھی مسلمان ہی غالب ہیں اور بڑی فصیح و بلیغ عربی بولتے ہیں۔ اس ناول کے اہم کرداروں میں ایک مولوی، مولوی عبدالسلام بھی ہیں جو خلا نوردوں کی راہ نمائی کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ اس میں خلائی سفر کے دوران بلکہ دوسرے سیارے پر باجماعت نماز بھی انہی مولوی کی اقتداء میں پڑھی جاتی ہے۔ ناول میں جابجا عربی مارکہ اردو اصطلاحات بھی ہیں جو اکثر مضحکہ خیز اور عام قاری کے لیے ان کو سمجھنا مشکل ہے۔ اس ناول کی چند کم زوریوں اور خامیوں کو نظر انداز کر دیا جائے تو یہ اس دور کا ایک دل چسپ ناول تھا، اور مزے کی بات یہ کہ ناول نگار نے خواتین خلا نوردوں کو بھی اس میں پیش کیا ہے مگر روایتی ملبوس اور بناؤ سنگھار میں مصروف دکھا کر خاصی حد تک مضحکہ خیزی پیدا کردی ہے۔
محبوب خان طرزی سے متعلق اس تحریر میں اب ہم اردو کے ممتاز نقاد، ادیب اور شاعر شمسُ الرحمٰن فاروقی کے مضمون سے چند اقتباسات شامل کررہے ہیں جو ان کے فن اور تخلیقات پر روشنی ڈالتا ہے۔ فاروقی صاحب لکھتے ہیں: "آج کا زمانہ ہوتا تو خان محبوب طرزی پر دو چار رسالوں کے نمبر نکل چکے ہوتے، یا نمبر نہ سہی گوشے ضرورہوتے۔ ایک دو کتابیں بھی ان پر آچکی ہوتیں۔ لیکن وہ زمانہ اور تھا، اردو معاشرے میں تمول کی اتنی فراوانی نہ تھی، اور ہمارے ادیبوں کو بھی اپنی تشہیر سے زیادہ اپنی تحریر کی فکر تھی، کہ اچھے سے اچھا لکھا جائے۔ شہرت تو حاصل ہوتی رہے گی۔
خان محبوب طرزی ہمارے ان ادیبوں میں تھے جنھوں نے قلیل معاوضے پر اپنی صلاحیتیں قربان کر دیں۔ اردو کا مفلوک الحال ادیب، کا یہ فقرہ ان پر صادق آتا ہے۔ وہ زمانہ بھی ایسا ہی تھا، اردو کو پوچھنے والے کم تھے اور کم ہوتے جارہے تھے۔ ایسے حالات میں اردو فکشن کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنانے والے خان محبوب طرزی کو داد دینی پڑتی ہے۔ اردو میں سائنس فکشن کا انھیں موجد کہا جاسکتا ہے، اور اس میں تو کوئی شک ہی نہیں کہ خان محبوب طرزی جیسا سائنس فکشن اردو میں پھر نہ لکھا گیا۔ اسرار اور مہم جوئی بھی ان کا ایک میدان تھا۔ پھر بچارے کو وہی وہانوی کے نام سے فحش یا نیم فحش افسانے اور مختصر ناول بھی لکھنے پڑے۔ مجھے وہی وہانوی کا کوئی ناول یاد نہیں آتا، لیکن اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ ان ناولوں میں کوئی شاق انگیز بات نہ تھی اور آج کے معیاروں سے انھیں فحش شاید نہ بھی قرار دیا جائے۔
طرزی صاحب کا پہلا ناول جو مجھے یاد ہے، "برق پاش” تھا۔ اس میں ایک تھوڑے سے جنونی سائنس داں نے لیسر کی طرح کی شعاعوں کو دور سے مار کرنے والے ہتھیار کی شکل میں تبدیل کر دیا تھا۔ تفصیل ٹھیک سے یاد نہیں، لیکن لیسر کا اس میں ذکر شاید نہ تھا، ہاں فاصلے سے بجلی کی طرح گرنے اور ہدف کو بے دریغ ہلاک کرنے کا مضمون ضرور تھا۔ اس سائنس داں نے کچھ طریقہ ایسا ایجاد کیا تھا کہ وہ لیسر کی قوت کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلی میں مرتکز کر کے انگلی کے اشارے سے قتل کی واردات انجام دیتا تھا۔ ایک طرح سے اسے انگریزی کے ایک فرضی لیکن مقبول کردار "دیوانہ سائنس داں” کا نقشِ اول کہا جا سکتا ہے۔ پھر میں نے تلاش کر کے، اور کبھی کبھی خود خرید کر کے خان محبوب طرزی کے کئی ناول پڑھے۔ان میں سائنسی ناول "دو دیوانے” مجھے خاص طور پر یاد ہے کیونکہ اس کے مرکزی سائنس داں کردار نے دعویٰ کیا تھا کہ میں اپنے خلائی جہاز میں ابدُ الآباد کائنات کا چکر لگاتا رہوں گا اور سورج کی شعاعوں سے اپنی غذا حاصل کروں گا۔ اس کا انجام مجھے یاد نہیں، لیکن یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ سورج کی شعاعوں سے غذا حاصل کرنے کا تصور اس زمانے میں بالکل نیا تھا اور سائنس نے شاید اس وقت اتنی ترقی بھی نہ کی تھی کہ ایسا ممکن ہوسکے۔ اس ناول میں ایک خاص بات یہ بھی تھی کہ خلا کے سفر کے دوران اس سائنس داں کو یہ بات معلوم ہوئی کہ آواز کبھی مرتی نہیں، مختلف طرح کی اور مختلف زبانوں کی تقریریں اور خطاب کائنات کے مختلف گوشوں میں اب بھی سنے جا سکتے ہیں۔ یہ خیال بھی، جہاں تک میں جانتا ہوں، بالکل نیا تھا۔ ایک اور ناول "سفرِ زہرہ” کا عنوان میرے ذہن میں رہ گیا ہے لیکن اس کے بارے میں اور کچھ مجھے یاد نہیں آتا۔
"شہزادی شب نور” ناول میں مہم جوئی، اسرار اور جستجو کے کئی عنا صر موجود تھے۔ پورے ناول پر ایک خاموش، پر اسرار فضا چھائی ہوئی محسوس ہوتی تھی جن ناولوں کا میں ذکر رہا ہوں، انھیں میں نے آج سے کوئی ستر بہتر برس پہلے پڑھا تھا۔ ان کا دل کش نقش اب بھی باقی ہے، اگرچہ مطالعے کا ذوق مجھے جلد ہی انگریزی ادب کی طرف لے گیا۔
میں سمجھتا تھا کہ طرزی صاحب کو آج کوئی نہیں جانتا اور مجھے اس کا رنج بھی تھا کہ اس زمانے میں اردو نے کئی مقبول ناول نگار دنیا کو دیے تھے: رشید اختر ندوی، رئیس احمد جعفری، قیسی رامپوری، اے۔ آر۔ خاتون، اور ان سے ذرا پہلے منشی فیاض علی اور ایم۔ اسلم۔ اِن میں کوئی ایسا نہ تھا جو خان محبوب طرزی کی طرح کا ابداع اور تنوع رکھتا ہو۔”
دوسری طرف طرزی صاحب کے بارے میں ایک رائے یہ بھی ہے کہ بسیار نویسی نے ان کے ناولوں کو معیار سے دور کر دیا تھا۔ اس ضمن میں سید احتشام حسین لکھتے ہیں: ’’ یہ ہمیشہ سے ہوتا چلا آیا ہے کہ بعض مصنفوں کو تاریخ اپنے دامن میں جگہ نہیں دیتی لیکن اس کے پڑھنے والے اس کی تحریروں کے منتظر رہتے ہیں۔ ادبی تنقید کا یہ بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے اور ادیب کی وقتی مقبولیت اس کی کام یابی ہے یا تھوڑے سے ایسے لوگوں کا متاثر ہونا جو ادب پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ محبوب طرزی اعلیٰ ادبیات سے دل چسپی لینے والوں میں مقبول نہیں تھے لیکن ان کی کتابیں چھپتی اور بکتی تھیں اور بعض کتابیں اتنی مقبول تھیں کہ ان کے کئی کئی اڈیشن شائع ہوئے۔