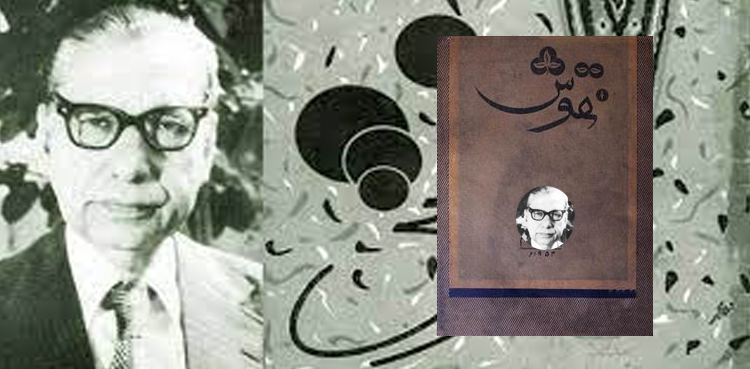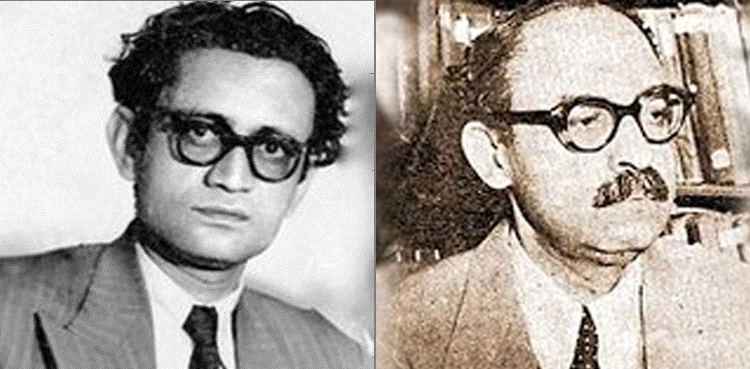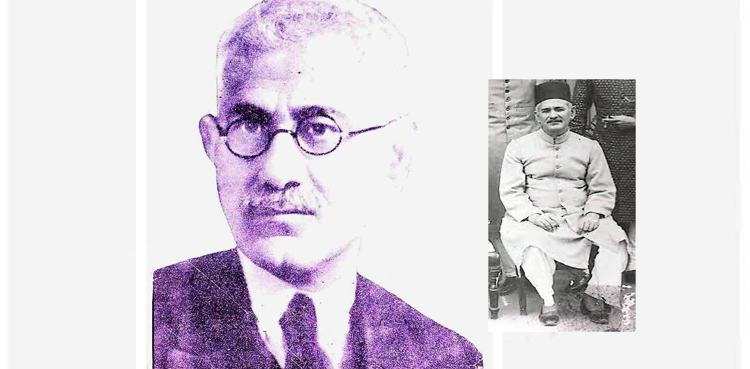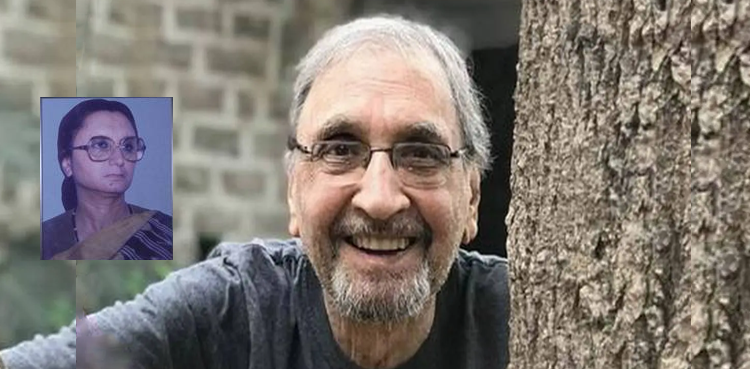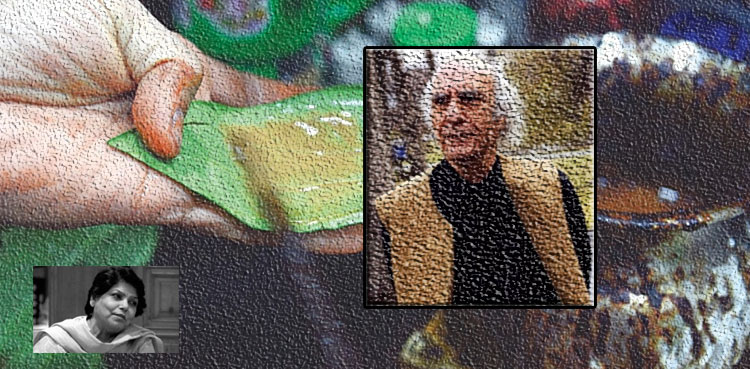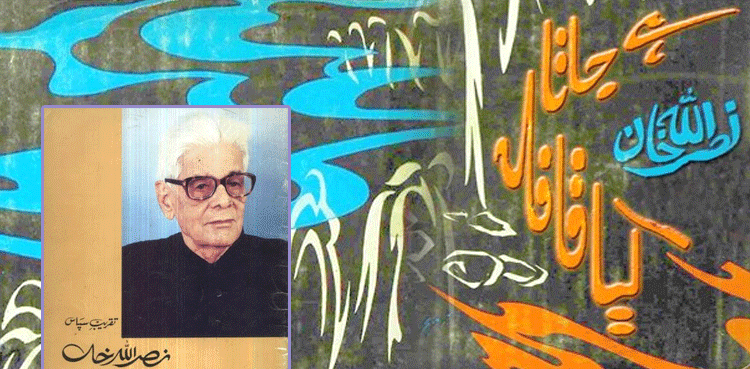بھارتی فلموں کے مکالمہ نویس اور کہانی کار جاوید صدیقی نے اپنے فنی سفر کا آغاز ستیہ جیت رے کی شہرۂ آفاق فلم شطرنج کے کھلاڑی سے بطور مکالمہ نویس کیا تھا۔ یہ بات ہے 1977 کی۔
فلم ‘دل والے دلہنیا لے جائیں گے’ کو شاید ہم سرحد پار کی فلم انڈسٹری کی، پڑوسی وڑوسی ملک کی کہانی کہہ کر ہم آسانی سے آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ محبّت کے جنون اور جذبے پر یہ فلم جاوید صدیقی کے قلم ہی سے نکلی تھی۔ اس کے علاوہ امراؤ جان، بازی گر، ڈر، غدار، ہم دونوں، چاہت، بازو، دِل کیا کرے، تال، زبیدہ، ہم کسی سے کم نہیں، کوئی مِل گیا جیسی معروف فلمیں بھی جاوید صدیقی کے کریڈٹ پر آئیں۔
جاوید صدیقی محض 17 سال کی عمر میں ممبئی چلے گئے تھے جہاں فلم نگری میں اپنی قسمت آزمائی۔ جاوید صدیقی زندگی کی اسّی سے زائد بہاریں دیکھ چکے ہیں۔ جاوید صدیقی فلمی دنیا سے قبل اردو صحافت سے وابستہ رہے۔ بھارتی فلم انڈسٹری کے اس سینئر قلم کار اور مصنّف نے کئی شخصیات کے خاکے بھی تحریر کیے جن پر مشتمل کتاب "روشن دان” کے نام سے شایع ہوئی تھی۔ اس کتاب میں انھوں نے اعتراف کیا کہ نوّے فلمیں لکھنے کے باوجود ان کے اندر کہیں نہ ادب کے تئیں تشنگی باقی تھی اور ایک تخلیقی کسک موجود تھی جس نے یہ کتاب لکھنے کے لیے انہیں مہمیز کیا۔
جاوید صدیقی کی اس کتاب سے ہم ایک دل چسپ قصّہ یہاں نقل کررہے ہیں۔ یہ قصّہ جاوید صدیقی نے اک بنجارہ کے نام سے نیاز حیدر کا خاکہ قلم بند کرتے ہوئے بیان کیا ہے۔ انہی کی زبانی سنیے:
بابا کا ایک مزے دار قصہ ہری بھائی (سنجیو کمار) نے مجھے سنایا تھا۔ جب تک وشوا متر عادل بمبئی میں رہے ہر سال اپٹا کی ’’دعوت شیراز‘‘ ان کے گھر پر ہوتی رہی۔ ہر نیا اور پرانا اپٹا والا اپنا کھانا اور اپنی شراب لے کر آتا تھا اور اس محفل میں شریک ہوتا تھا۔ ساری شراب اور سارے کھانے ایک بڑی سی میز پر چن دیے جاتے، جس کا جو جی چاہتا کھا لیتا اور جو پسند آتا وہ پی لیتا۔ یہ ایک عجیب و غریب محفل ہوتی تھی جس میں گانا بجانا ناچنا، لطیفے، ڈرامے سبھی کچھ ہوتا تھا۔ اور بہت کم ایسے اپٹا والے تھے جو اس میں شریک نہ ہوتے ہوں۔ ایسی ہی ایک ’’دعوتِ شیراز‘‘ میں ہری بھائی نیاز بابا سے ٹکرا گئے۔ اور جب پارٹی ختم ہوئی تو اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئے۔ ہری بھائی دیر سے سوتے تھے اور دیر سے جاگتے تھے، اس لیے وہاں بھی صبح تک محفل جمی رہی۔ پتہ نہیں کس وقت ہری بھائی اٹھ کے سونے کے لیے چلے گئے اور بابا وہیں قالین پہ دراز ہو گئے۔
دوسرے دن دوپہر میں ہری بھائی سو کر اٹھے اور حسبِ معمول تیّار ہونے کے لیے اپنے باتھ روم میں گئے۔ مگر جب انھوں نے پہننے کے لیے اپنے کپڑے اٹھانے چاہے تو حیران ہو گئے، کیوں کہ وہاں بابا کا میلا کرتا پاجامہ رکھا ہوا تھا اور ہری بھائی کا سلک کا کرتا اور لنگی غائب تھے۔
ہری بھائی نے نوکر سے پوچھا تو تصدیق ہو گئی کہ وہ مہمان جو رات کو آئے تھے صبح سویرے نہا دھوکر سلک کا لنگی کرتا پہن کے رخصت ہو چکے ہیں۔ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔
اس کہانی کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ کچھ دو مہینے بعد ایک دن اچانک نیاز بابا ہری بھائی کے گھر جا دھمکے اور چھوٹتے ہی پوچھا: ’’ارے یار ہری! پچھلی دفعہ جب ہم آئے تھے تو اپنا ایک جوڑ کپڑا چھوڑ گئے تھے وہ کہاں ہے؟‘‘
ہری بھائی نے کہا: ’’آپ کے کپڑے تو میں نے دھلوا کے رکھ لیے ہیں مگر آپ جو میرا لنگی کرتا پہن کے چلے گئے تھے وہ کہاں ہے؟‘‘ بابا نے بڑی معصومیت سے اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرا، سر کھجایا اور بولے: ’’ہمیں کیا معلوم تمھارا لنگی کرتا کہاں ہے؟ ہم کوئی ایک جگہ کپڑے تھوڑی بدلتے ہیں؟‘‘
ہری بھائی جب بھی یہ قصہ سناتے تھے بابا کا جملہ یاد کر کے بے تحاشہ ہنسنے لگتے تھے۔‘‘
نیاز حیدر کی پہلو دار شخصیت کو عیاں کرتے ہوئے جاوید صدیقی ایک جگہ یہ واقعہ بیان کرتے ہیں: جوہو کولی واڑہ اور اس کے آس پاس بہت سی چھوٹی موٹی گلیاں ہیں، بابا ایسی ایک گلی میں گھس گئے۔ دور دور تک اندھیرا تھا، دو چار بلب جل رہے تھے مگر وہ روشنی دینے کے بجائے تنہائی اور سناٹے کے احساس کو بڑھا رہے تھے۔ بابا تھوڑی دور چلتے پھر رک جاتے، گھروں کو غور سے دیکھتے اور آگے بڑھ جاتے۔ اچانک وہ رک گئے، سامنے ایک کمپاؤنڈ تھا جس کے اندر دس بارہ گھر دکھائی دے رہے تھے۔ ان میں سے کوئی بھی گھر ایک منزل سے زیادہ نہیں تھا اور بیچ میں چھوٹا سا میدان پڑا ہوا تھا جس میں ایک کنواں بھی دکھائی دے رہا تھا۔ بابا نے کہا یہی ہے اور گیٹ کے اندر گھس گئے۔ میں بھی پیچھے پیچھے تھا مگر ڈر رہا تھا کہ آج یہ حضرت ضرور پٹوائیں گے۔ بابا کمپاؤنڈ کے بیچ میں کھڑے ہو گئے۔ چاروں طرف سناٹا تھا۔ کسی گھر میں روشنی نہیں تھی۔ بابا نے زور سے آواز لگائی: ’’لارنس…‘‘
کہیں سے کوئی جواب نہیں آیا۔ میرا خوف اور بڑھنے لگا۔ کولیوں کی بستی ہے وہ لوگ ویسے ہی سرپھرے ہوتے ہیں آج تو پٹائی یقینی ہے۔
بابا زور زور سے پکار رہے تھے: ’’لارنس… لارنس!…‘‘ اچانک ایک جھوپڑے نما گھر میں روشنی جلی، دروازہ کھلا اور ایک لمبا چوڑا بڑی سی توند والا آدمی باہر آیا، جس نے ایک گندا سا نیکر اور ایک دھاری دار بنیان پہن رکھا تھا۔
جیسے ہی اس نے بابا کو دیکھا ایک عجیب سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر پھیل گئی: ’’ارے بابا! کدھر ہے تم؟ کتنا ٹائم کے بعد آیا ہے؟‘‘ یہ کہتے کہتے اس نے بابا کو دبوچ لیا اور پھر زور زور سے گوانی زبان میں چیخنے لگا۔ اس نے بابا کا ہاتھ پکڑا اور اندر کی طرف کھینچنے لگا: ’’آؤ آؤ اندر بیٹھو… چلو چلو‘‘ پھر وہ میری طرف مڑا: ’’آپ بھی آؤ ساب! آجاؤ آ جاؤ اپنا ہی گھر ہے۔ ‘‘ ہم تینوں ایک کمرے میں داخل ہوئے جہاں دو تین میزیں تھیں، کچھ کرسیاں اور ایک صوفہ، اندر ایک دروازہ تھا جس پر پردہ پڑا ہوا تھا۔ بابا پوچھ رہے تھے: ’’کیسا ہے تُو لارنس؟… ماں کیسی ہے؟… بچہ لوگ کیسا ہے؟‘‘
اتنی دیر میں اندر کا پردہ کھلا اور بہت سے چہرے دکھائی دینے لگے۔ ایک بوڑھی عورت ایک میلی سی میکسی پہنے باہر آئی اور بابا کے پیروں پر جھک گئی۔ بابا نے اس کی خیر خیریت پوچھی، بچوں کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور جب یہ ہنگامہ ختم ہوا تو لارنس نے پوچھا: ’’کیا پیئیں گے بابا؟‘‘
’’وہسکی…‘‘ بابا نے کہا۔ لارنس اندر گیا اور وہسکی کی ایک بوتل ٹیبل پہ لا کے رکھ دی۔ اس کے ساتھ دو گلاس تھے، کچھ چینی کچھ نمک سوڈے اور پانی کی بوتلیں۔ بابا نے پیگ بنایا، لارنس الٰہ دین کے جن کی طرح ہاتھ باندھ کر سامنے کھڑا ہو گیا: ’’اور کیا کھانے کاہے بابا؟… ماں مچھّی بناتی، اور کچھ چہیئے تو بولو… کومڑی (مرغی) کھانے کا موڈ ہے؟‘‘ بابا نے مجھ سے پوچھا: ’’بولو بولو بھئی کیا کھاؤ گے؟‘‘
میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بابا کی اتنی آؤ بھگت کیوں ہو رہی ہے۔ اگر ایسا بھی ہوتا کہ وہ لارنس کے مستقل گراہکوں میں سے ایک ہوتے تو بھی رات کے دو بجے ایسی خاطر تو کہیں نہیں ہوتی۔ یہاں تو ایسا لگ رہا تھا جیسے بابا اپنی سسرال میں آ گئے ہوں۔
تھوڑی دیر میں تلی ہوئی مچھلی بھی آ گئی، ابلے ہوئے انڈے بھی اور پاؤ بھی۔ بہر حال مجھ سے برداشت نہیں ہوا، کھانا کھاتے ہوئے میں نے بابا سے پوچھا: ’’بابا اب اس راز پر سے پردہ اٹھا ہی دیجیے کہ اس لارنس اور اس کی ماں سے آپ کا کیا رشتہ ہے؟‘‘
کہانی یہ سامنے آئی کہ برسوں پہلے جب بابا اپنی ہر شام لارنس کے اڈے پر گزارا کرتے تھے تو ایک دن جب لارنس کہیں باہر گیا ہوا تھا اس کی ماں کے پیٹ میں درد اٹھا تھا، درد اتنا شدید تھا کہ وہ بیہوش ہو گئی تھی۔ اس وقت بابا اسے اپنے ساتھ لے کر اسپتال پہنچے، پتہ لگا کہ اپینڈکس پھٹ گیا ہے، کیس بہت Serious تھا آپریشن اسی وقت ہونا تھا ورنہ موت یقینی تھی۔ بابا نے ڈاکٹر سے کہا آپ آپریشن کی تیاری کیجیے اور نہ جانے کہاں سے اور کن دوستوں سے پیسے جمع کر کے لائے، بڑھیا کا آپریشن کرایا اور جب لارنس اسپتال پہنچا تو اسے خوش خبری ملی کہ اس کی ماں موت کے دروازے پہ دستک دے کے واپس آ چکی ہے۔ تھینکس ٹو نیاز بابا….
اس کہانی میں ایک خاص بات یہ ہے کہ لارنس اور اس کی ماں کے بار بار خوشامد کرنے کے باوجود بابا نے وہ پیسے کبھی واپس نہیں لیے جو انھوں نے اسپتال میں بھرے تھے۔
صبح تین بجے کے قریب جب میں بابا کو لے کر باہر نکل رہا تھا تو میں نے پلٹ کر دیکھا تھا، لارنس کی ماں اپنی آنکھیں پونچھ رہی تھی اور لارنس اپنے ہاتھ جوڑے سَر جھکائے اس طرح کھڑا تھا جیسے کسی چرچ میں کھڑا ہو۔‘‘