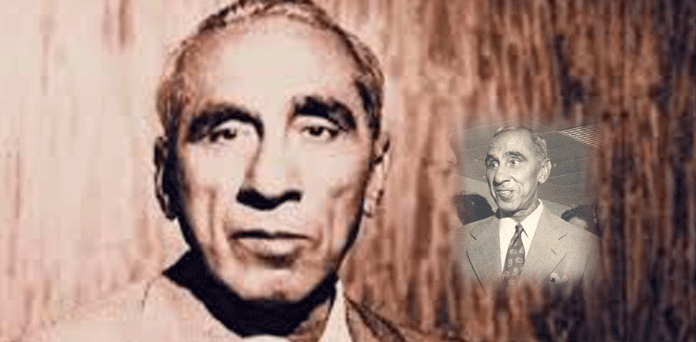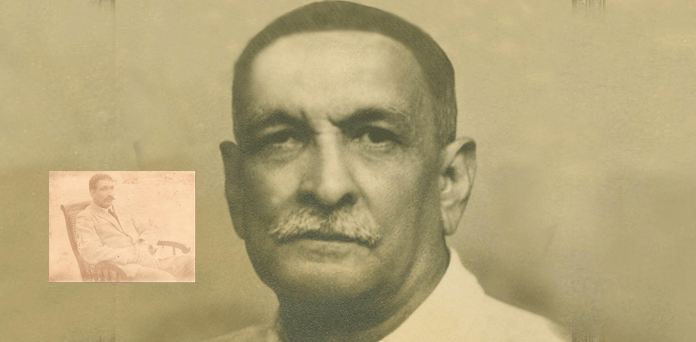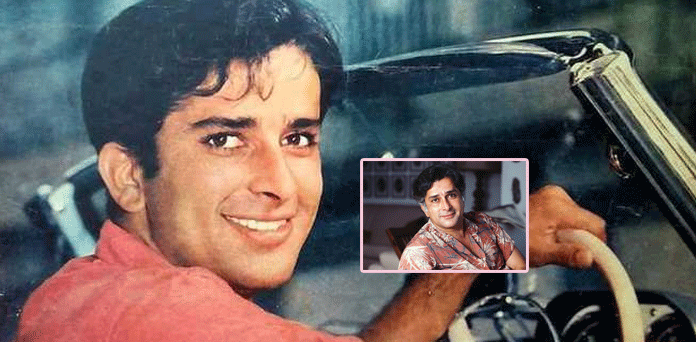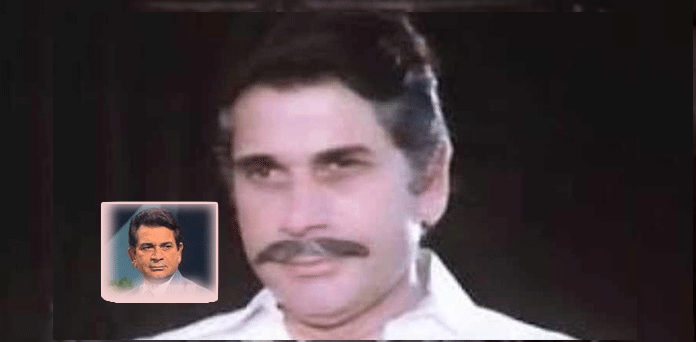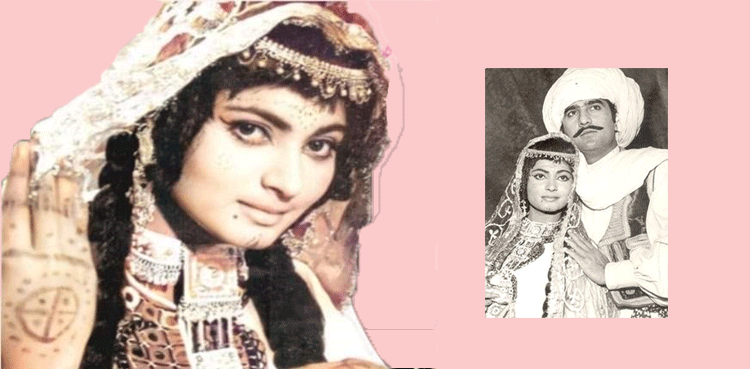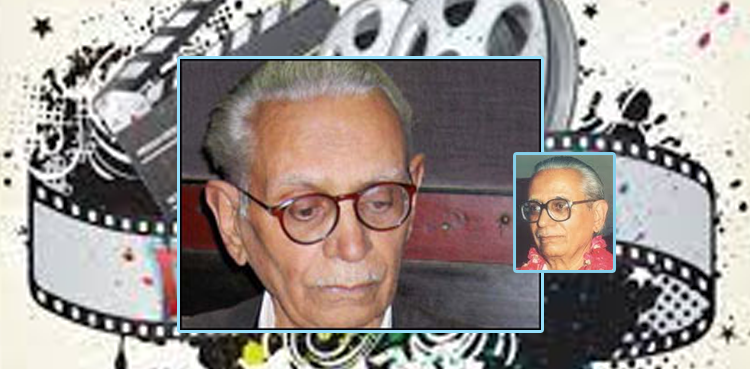علی عباس جلالپوری کا ذکر پاکستان کے ایک بلند پایہ مفکر، فلسفی اور خرد افروزی پر مبنی کتابوں کے مصنّف کے طور پر کیا جاتا ہے۔ ان کا وقیع علمی سرمایہ اُس تحقیقی کام پر مشتمل ہے جس میں تاریخ و فلسفہ، مذہب و معاشرت بہم نظر آتے ہیں۔
پاکستانی معاشرے میں فکر و دانش کے موتی لٹانے والے جلال پوری ایک عالم فاضل، نہایت قابل اور وسیع المطالعہ شخصیت تھے جو تصنیف و تالیف کے ساتھ تدریس کے شعبہ سے منسلک رہے۔ علی عباس جلال پوری نے فارسی اور اردو دنوں زبانوں میں ایم اے کیا۔گورنمنٹ کالج، لاہور کے پروفیسر رہے۔ ان کا موضوع فلسفہ، تاریخِ فلسفہ، تاریخ اور مذہبیات رہا اور اردو زبان میں ان کے کئی مضامین اور چودہ سے زائد کتابیں شایع ہوئیں۔
جلال پوری نے جس ماحول میں آنکھ کھولی وہ اس بارے میں کہتے تھے: ”خوش قسمتی سے میں ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہوا جہاں علم و حکمت کا چرچا تھا۔ ہمارے ہاں کم و بیش تمام ادبی رسائل آتے تھے۔ میں ساتویں جماعت میں تھا کہ بچّوں کے رسالے ” پھول“ کے ساتھ ساتھ “ ہمایوں”، “زمانہ” وغیرہ میں چھپے ہوئے افسانے بھی پڑھنے لگا تھا۔ ان کے علاوہ خواجہ حسن نظامی، راشد الخیری اور نذیر احمد دہلوی کی کتابیں بھی میری نظر سے گزرنے لگی تھیں۔ اس زمانے میں ایک دن اپنے کتب خانے کو کھنگالتے ہوئے دو نایاب کتب مرے ہاتھ لگیں جن کے مطالعے نے مجھے دنیا و مافیہا سے بے خبر کر دیا۔ ان میں، ایک ” داستان امیر حمزہ“ اور دوسری ” الف لیلیٰ، “ تھی۔”
1914ء میں پیدا ہونے والے علی عباس جلال پوری نے 1931ء میں سندر داس ہائی اسکول ڈنگہ سے میٹرک کا امتحان پاس کیا اور گورنمنٹ انٹر کالج گجرات میں پڑھنے لگے۔ 1934ء میں انھوں نے گورنمنٹ کالج لاہور میں بی اے میں داخلہ لیا۔ بعد ازاں بی ٹی کا کورس کر کے بطور مدرس ملازمت کا آغاز کیا۔ جلال پوری کچھ عرصہ انسپکٹر اسکولز بھی رہے۔ 1945ء میں شہزادی بیگم سے رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے۔ دورانِ ملازمت 1950ء میں اردو میں ایم اے کیا تھا اور بطور لیکچرار ایمرسن کالج ملتان میں تعینات ہوگئے۔ بعد میں فارسی میںایم اے فارسی میں کام یابی پر گولڈ میڈل کے حق دار ٹھہرائے گئے لیکن ان کا اصل موضوع فلسفہ تھا۔ 1958ء میں جلال پوری نے فلسفے کا امتحان بھی امتیازی حیثیت سے پاس کیا۔
6 دسمبر 1998ء کو وفات پانے والے علی عباس کو جلال پور شریف میں سپرد خاک کیا گیا۔
محمد کاظم جو ایک قد آور علمی و ادبی شخصیت تھے اور قدیم اور جدید عربی ادب پر گہری نظر تھے انھوں نے اس نادرِ روزگار شخصیت سے متعلق اپنی یادیں اس طرح بیان کی ہیں۔ ملاحظہ کیجیے۔
"سیّد علی عباس جلال پوری سے میرا غائبانہ تعارف اردو رسالے ”ادبی دنیا“ کے صفحات پر ہوا۔”
”ادبی دنیا“ ابھی اپنے آخری دور میں تھا کہ ادھر جناب احمد ندیم قاسمی نے اپنا ادبی رسالہ ”فنون“ جاری کیا۔ (رسالے کا اجرا یقیناً کسی ساعتِ سعید میں ہوا ہو گا کہ بہت سے نشیب و فراز اور مالی دشواریوں کے باوجود یہ اللہ کے فضل سے ابھی تک زندہ ہے۔) اب شاہ صاحب ”فنون“ میں لکھنے لگے اور زیادہ عرصہ نہ گزرا کہ ”فنون“ کے دفتر میں ان سے گاہے بگاہے ملاقات بھی رہنے لگی۔ ”
"میں نے جب ان کو پہلی بار دیکھا تو ان کی شخصیت مجھے ان کے مقالات کی طرح سنجیدہ، رکھ رکھاؤ والی اور گمبھیر لگی۔ وہ عموماً کوٹ پتلون پہنتے اور ٹائی لگاتے اور سَر پر گہرے چاکلیٹی رنگ کی قراقلی ٹوپی رکھتے تھے۔ گندمی رنگت اور موزوں ناک نقشے کے ساتھ وہ جوانی میں خاصے قبول صورت رہے ہوں گے۔ ان کے نقوش میں سب سے نمایاں ان کی غلافی آنکھیں تھیں جو ان کے چہرے کو پُرکشش تو بناتی ہی تھیں، اس کے ساتھ ان کے وقار میں بھی اضافہ کرتی تھیں۔ نکلتے ہوئے قد اور اکہرے تنے ہوئے جسم کے ساتھ وہ تیر کی طرح سیدھا چلتے تھے۔ ان کی آواز میں نئے سکّے کی سی کھنک تھی اور ان کے بات کرنے کے انداز میں ایسا تیقّن اور اعتماد ہوتا تھا کہ ان کے منہ سے نکلی ہوئی کوئی بات بھی ہلکی یا بے مقصد نہیں لگتی تھی۔ وہ اگر روزمرہ کی گپ شپ بھی کر رہے ہوتے تو یوں لگتا جیسے ان کی بات سوچ کے عمل سے گزر کر باہر آئی ہے۔”
"مدیر ”فنون“ کی ایک بڑی سی جہازی میز کے بائیں طرف کرسیوں پر سید علی عباس جلال پوری، رشید ملک، راقمُ الحروف، محمد خالد اختر اور کبھی کبھی پروفیسر شریف کنجاہی بیٹھے ہوتے۔ میز کے سامنے بھی آٹھ دس نشستیں ہوتی تھیں، جن پر شعراء و ادباء کی نئی نسل کے افراد ٹکے رہتے۔ ادیبوں اور شاعروں کی اس محفل میں ہر طرح کے موضوع زیرِ بحث آتے، جدید و قدیم ادب پر اظہارِ خیال ہوتا۔”
"ہمارے اس ملک میں صحیح معنوں میں کثیرُالمطالعہ لوگ انگلیوں پر گنے جاسکتے ہیں۔ ان میں سے کچھ کو ہم جانتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا انکشاف ہمیں ان کی تحریریں پڑھ کر ہوتا ہے۔ کوئی شک نہیں کہ سیّد علی عباس جلال پوری ان کثیرُ المطالعہ لوگوں کی اقلیت سے تعلق رکھتے تھے۔ انہوں نے بہت پڑھا تھا اور جو پڑھا تھا اس کے بارے میں سوچ بچار کیا تھا اور اس کو ہضم کر کے اپنی ذہنی و فکری وجود کا جزو بنایا تھا۔”
علی عباس صاحب نے اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کے ساتھ کائنات اور انسان، خرد نامہ جلال پوری، رسوم اقوام، میرا بچپن اور لڑکپن، پریم کا پنچھی پنکھ پسارے(ناولٹ)، پنجابی محاورے اور سبد گل چیں مکمل کیں۔ یہ ان کی یادگار کتابیں ہیں۔