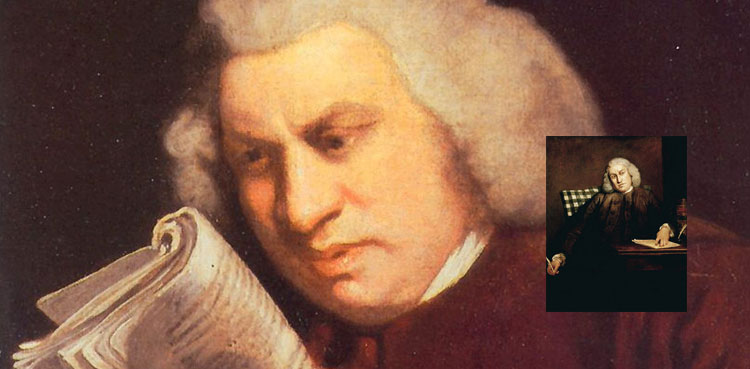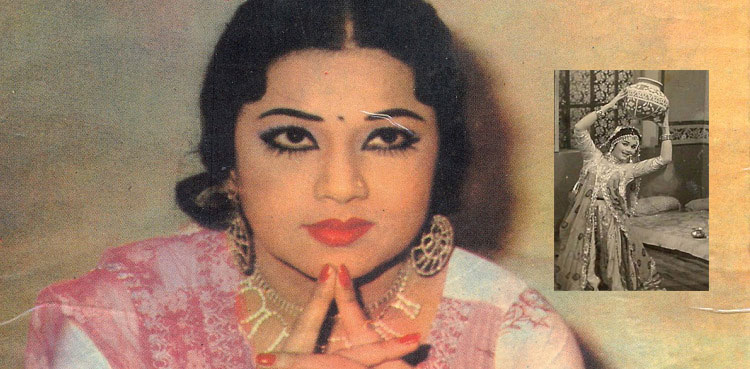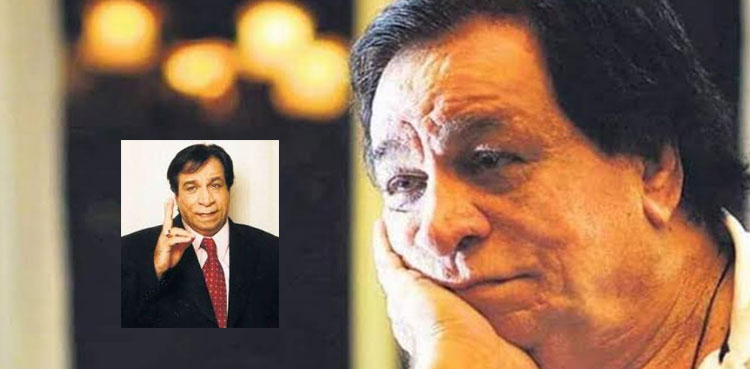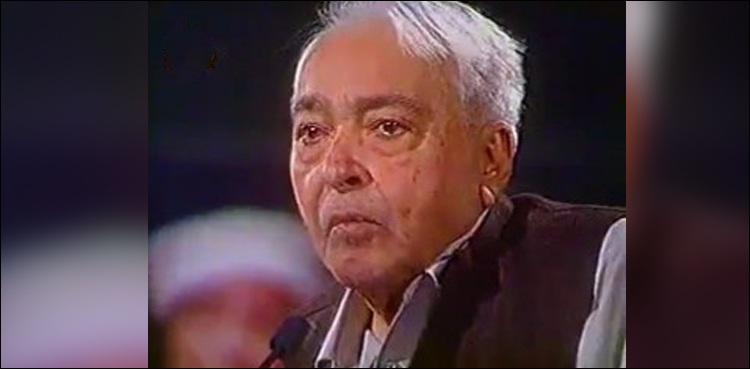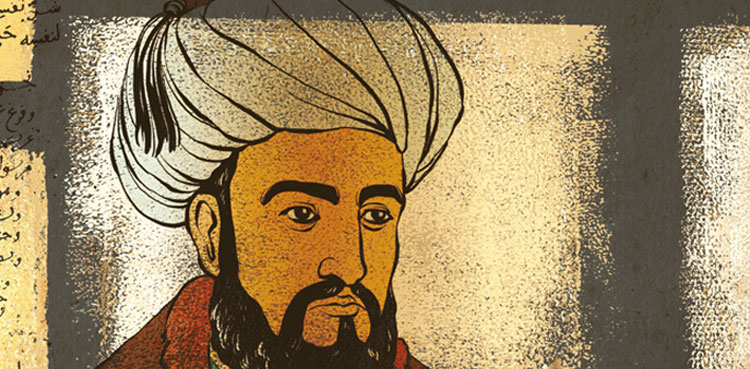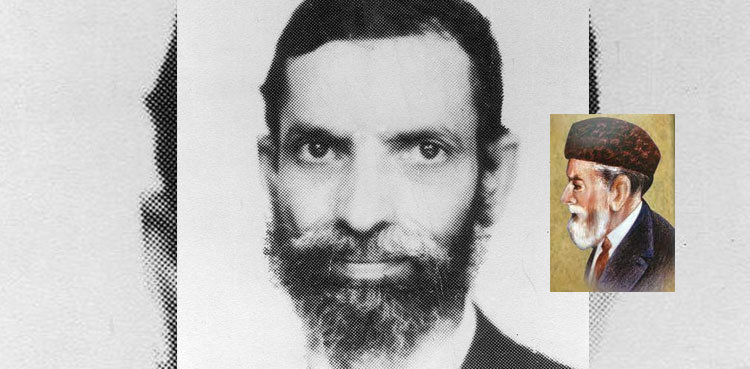مشہور ہے کہ جونسن نے ’’تواریخِ راسلس‘‘ صرف ایک ہفتے میں قلم برداشتہ لکھا۔ اس ناول کی تخلیق کا پس منظر توجہ طلب اور غم آگیں بھی ہے۔ کہتے ہیں یہ ناول اس نے اپنی ماں کے کفن دفن اور چھوٹے موٹے قرضے اتارنے کے لیے لکھا تھا۔
سیموئل جونسن ایک انگریز ادیب اور لغت نویس تھا جسے ادب میں اس کی تنقیدی بصیرت اور نکتہ سنجی کے لیے بھی پہچانا جاتا ہے، لیکن وہ ایسا ناول نگار تھا جو افسانوی تخیل سے دور رہا۔ یہاں ہم جونسن کے جس ناول کا ذکر کررہے ہیں وہ افسانوی رنگ نہ ہونے کے سبب بالخصوص ناول نگار کے افکار اور حقائق پر مبنی مباحث کی وجہ سے بظاہر روکھا پھیکا نظر آتا ہے۔ اس پر تنقید بھی کی گئی ہے، لیکن ناقدین کا یہ بھی کہنا ہے کہ تواریخِ راسلس کا پلاٹ خوب گٹھا ہوا ہے۔ اس کی نثر متانت آمیز ہے اور اس میں افکار کی صراحت قابلِ توجہ ہے۔
ہفتے بھر میں ایک ناول لکھ کر ناشر کے حوالے کر دینے سے متعلق انگریزی ادب کے ناقدین قیاس کرتے ہیں کہ کہانی کا پلاٹ یا اس کا کوئی ہیولا ضرور جونسن کے ذہن میں پہلے سے رہا ہو گا۔
ناول کی کہانی
اس ناول کا مرکزی کردار حبشہ کا ایک شہزادہ ہے۔ وہ اور اس کے دیگر بہن بھائی عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتے تھے، لیکن ایک وقت آیا جب راسلس اس عیش و عشرت اور تن آسانی کی زندگی سے بیزار ہو گیا۔ شہزادے کا معلّم اس سے افسردگی کا سبب دریافت کرتا ہے اور اُسے سمجھاتا ہے کہ تم اس خوش حالی اور عیش و عشرت سے محض اس لیے اکتا گئے ہو کہ تم نے دنیا کے رنج اور مصائب نہیں دیکھے، ورنہ تمھیں اس عیش کی قدر ہوتی۔ تب، شہزادہ دنیا کے رنج اور مصیبتیں دیکھنے کے لیے سب کچھ چھوڑ کر سیر کے لیے نکل جاتا ہے۔ ناول میں بتایا گیا ہے کہ کیسے یہ شہزادہ اپنی سیاحت کے دوران لوگوں سے باہمی میل جول رکھتا ہے اور لوگوں سے تبادلۂ خیال کرتے ہوئے زندگی کے مختلف پہلوؤں اور مسائل کو سمجھتا ہے اور اپنے خیالات اور مشاہدات کو بیان کرتا چلا جاتا ہے۔ وہ متعدد لوگوں سے ملتا ہے۔ بادشاہوں، امیروں، غریبوں اور مختلف پیشہ ور افراد سے ملاقات کرنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ امیر ہو یا غریب، شاہ ہو یا گدا، کوئی بھی اپنی زندگی سے مطمئن نہیں ہے۔ دراصل اس کردار کے ذریعے جونسن نے ناول میں زندگی اور مسائل پر اپنے افکار کا اظہار کیا ہے۔ ناول میں اس طرح کے مباحث کئی مقام پر آتے ہیں، جس سے یہ روکھا پھیکا معلوم ہوتا ہے، لیکن یہ جونسن کی اُفتادِ طبع کی عکاسی کرتا ہے جس میں وہ نکتہ سنج اور صاحبِ فکر نظر آتا ہے۔ ناول نگار نے افسانہ طرازی سے دور رہتے ہوئے معلومات اور حقائق کو اہمیت دی ہے۔
ناول کی تخلیق کا درد انگیز پس منظر
کہتے ہیں ناول نگار نے اپنی ماں کی وفات کے بعد اس کی تجہیز و تکفین اور زندگی میں ان پر واجبُ الادا رقم چکانے کے لیے ایک ناشر سے رجوع کیا اور سو پاؤنڈ کے عوض صرف ایک ہفتے میں ”تواریخِ راسلس” لکھ کر کے اس کے سپرد کر دیا۔ یہ ناول غیرمعمولی طور پر بہت مقبول ہوا اور اس کے فرانسیسی، جرمن، اطالوی اور ڈچ زبان میں تراجم شایع ہوئے۔
جونسن کے حالاتِ زندگی اور علمی و ادبی کارنامے
سیموئل جانسن وسطی انگلستان کے ایک چھوٹے سے قصبے لیچفیلڈ میں 1709ء کو پیدا ہوا۔ ابتدائی عمر میں اس کے والدین کو معلوم ہوا کہ ان کی اولاد کی بینائی کم زور ہے۔ اس کا باپ ایک تاجر تھا، تاہم اس کا خاندانی رتبہ اونچا نہ تھا اور حسب نسب میں وہ جونسن کی ماں سے کم تھا۔ اُس نے پڑھ لکھ کر ایک دکان کھول لی تھی جس میں وہ کتابیں اور دوائیں فروخت کرتا تھا۔ جونسن کی ماں اپنے خاندان اور نام و نسب پر فخر کرتی تھی اور اپنے شوہر کو ہمیشہ حقیر اور خود سے کم تر جانتی تھی۔ اسی باعث ان کی آپس میں نہیں بنتی تھی۔
جونسن کی یادداشت بچپن سے ہی قابلِ رشک تھی جس کا اظہار وہ اکثر اس خوبی سے کرتا کہ سامنے والا دنگ رہ جاتا۔ اپنی اس غیرمعمولی ذہانت کی وجہ سے وہ اپنے علاقے میں بہت مشہور ہوا اور اسے دعوتوں میں بلایا جانے لگا۔ اسٹیشنری کے سامان اور دکان پر موجود کتابوں سے وہ شروع ہی خاصا مانوس تھا۔ والد کا انتقال ہوا تو کچھ عرصے ایک اسکول میں بہ طور مدرس خدمات انجام دیں، لیکن پھر اس کا دل نہ لگا اور اس نے ادبی سرگرمیوں کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اس کی پہلی کتاب ایک پرتگیزی پادری کے فرانسیسی سفرنامے کا انگریزی ترجمہ تھا۔ اس ترجمے کا اُسے پانچ گنا معاوضہ ملا۔ بعد میں وہ تلاشِ معاش کی غرض سے لندن پہنچا اور وہاں ایک رسالے ”جنٹل مینز میگزین” میں معاون مدیر کی حیثیت سے کام کرنے لگا۔ اس کی آمد کے بعد رسالے کی مانگ اور مقبولیت تو بڑھ گئی لیکن وہ رسالے کے مالک اور مدیر کی خصاصت کی وجہ سے مالی طور پر آسودہ نہ ہوسکا۔
”جامع انگریزی لغت” جانسن کا نمایاں علمی کام ہے۔ اس کی مرتب کردہ لغت کے لیے اسے بڑے ناشروں نے تین سال کی مدت کے لیے ایک ہزار پانچ سو پچھتّر پاؤنڈ معاوضہ دینے کا وعدہ کیا تھا۔ تاہم یہ کام طوالت کے باعث آٹھ سال میں مکمل ہوسکا اور زیورِ طباعت سے آراستہ ہوا۔ جونسن کی اس لغت سے پہلے اس پائے کی لغت انگریزی زبان میں موجود نہ تھی۔ یہاں سے جونسن کی شہرت کا صحیح معنوں میں آغاز ہوا۔ یہ اعلیٰ درجے کا علمی کام تھا جس پر آکسفورڈ نے جونسن کو سند بھی دی تھی۔
والدہ سے جدائی کے 19 برس اور وفات
1759ء میں جونسن کو جب اپنی ماں کی شدید علالت کی اطلاع ملی تھی تو وہ غربت اور تنگ دستی سے لڑرہا تھا۔ پچھلے انیس برس میں اس نے لندن سے گھر لوٹ کر اپنی ماں کا چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ اور اسی جدائی میں وہ ہمیشہ کے لیے دنیا سے چلی گئی۔ جونسن دکھی تھا اور تبھی تواریخِ راسلس تخلیق کیا۔
1762ء میں جونسن کی مالی مشکلات میں خاطر خواہ فرق پڑا اور اس کی ادبی خدمات کے صلے میں حکومت نے اسے پینشن کی پیش کش کی۔ انگریزی کی لغت کے علاوہ جونسن نے شیکسپیئر کے ڈراموں کا ایک ایڈیشن بھی مرتب کیا تھا جسے مستند مانا جاتا ہے۔ اس نے سوانح اور تنقید بھی لکھی جو اس کی شہرت کا سبب بنا۔
انگریزی زبان کے اس ادیب اور لغت نویس کا انتقال 1784ء میں ہوا۔