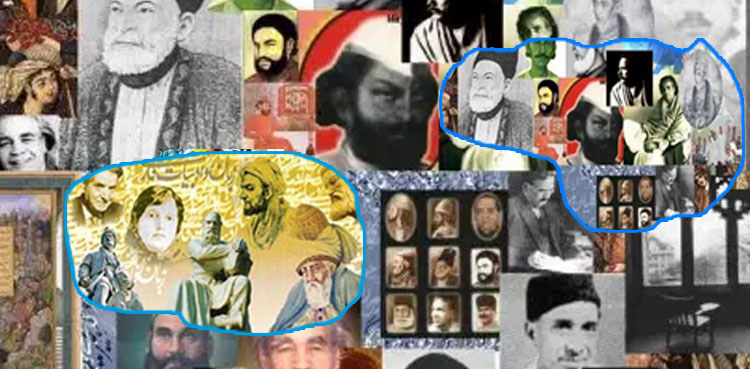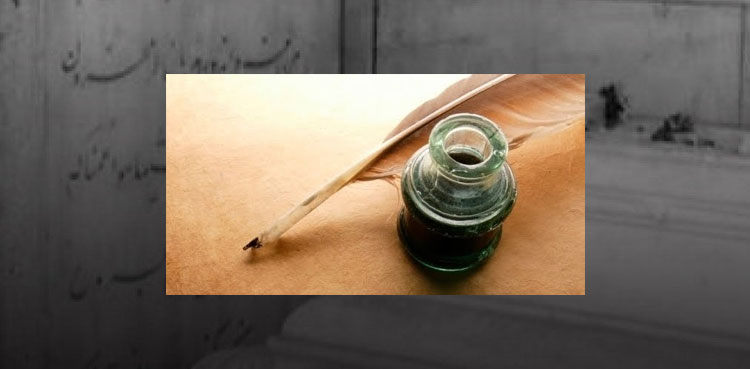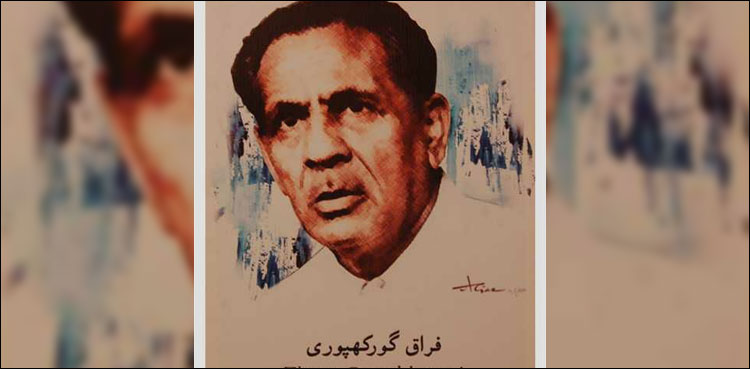فارسی اگرچہ ایران (فارس) کی زبان تھی، تاہم فتحِ دلّی کے بعد سے ہی بادشاہوں، علما، صوفیا اور شعرا نے اس زبان کو اپنا لیا اور اسے خوب فروغ دیا۔
غیر ملکی زبان فارسی کو ہندوستانی نسل کے فارسی شعرا نے جس قدر عزّت بخشی تھی تو انہیں بھی اس بات کا حق حاصل تھا کہ ایرانی النّسل فارسی علما و شعرا اُن کی اس علمی اور شعری رواداری کا خیر مقدم کریں لیکن ایرانی النسل علما و شعرا تو ابتدا ہی سے یعنی عہدِ سلاطین ہی سے ہندوستانی النّسل فارسی علما و شعرا کو طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے چلے آ رہے تھے اور جن کے وار سے امیر خسرو بھی بچ نہیں سکے تھے۔ تاریخ میں اس کی کئی مثالیں دیکھنے کو ملتی ہیں مثلاً عبید زاکانی کا امیر خسرو پر پھبتی کسنا، عراقی کا فیضی کے متعلق اہانت آمیز بات کہنا، شیخ علی حزیں کی دریدہ دہنی وغیرہ۔
یہاں یہ بھی عرض کر دینا چاہتی ہوں کہ بعض معروف ایرانی النّسل شعرا مثلاً عبدالرّحمٰن جامی، حافظ شیرازی اور جمال الدّین عرفی نے امیر خسرو کی زبان دانی کی تعریف کی ہے اور حافظ شیرازی نے تو انہیں ’’طوطیٔ ہند‘‘ کے لقب سے بھی یاد کیا ہے، تاہم ہندوستانی النّسل فارسی علما و شعرا کے تعلق سے ایرانی النسل علما و شعرا کا عام رویّہ وہی تھا جس کا ذکر میں نے اوپر کیا ہے۔ اس سے یہی اندازہ ہوتا ہے کہ ایرانی شعرا کے نزدیک ہندوستانی نژاد فارسی شعرا ثقہ کی حیثیت نہیں رکھتے تھے۔
میرے خیال میں اس کی دو بڑی وجوہات تھیں۔ اوّل یہ کہ ایرانیوں کا ملکی و قومی عصبیت رکھنا، جس کی واضح صورت پورے اسلامی تاریخ میں نمایا ں ہے۔ دوم وہ حریفانہ چشمک جو عام طور پر علما و شعرا میں پایا جاتا ہے۔ اس حریفانہ چشمک کے طویل سلسلے کی روک تھام اور نفسیاتی گرہ کشائی کے لیے دلبرداشتہ ہو کر دہلی کے بزرگ سعد اللہ گلشن نے پہل کی تھی اور انہوں نے ولی دکنی کو یہ مشورہ دیا تھا کہ فارسی کو ترک کر کے ریختہ (اردو) میں اشعار کہیں۔ اُس کے بعد سراج الدّین علی خان آرزو نے اس پر بھرپور عمل کیا اور ریختہ میں شاعری کرنے کو تحریک کی صورت عطا کی۔
جب شیخ علی حزیں 35-1734 میں ایران سے ہندوستان آئے تو انہوں نے اپنی ایک خود نوشت ’’تذکرۃُ الا حوال‘‘ لکھی جس میں اپنی عصبیت اور نفرت کا بَرملا اظہار کیا۔ اس میں ہندوستانی فارسی شعرا کے خلاف نہ صرف سخت نکتہ چینی کی بلکہ اہانت آمیز ہجویں بھی لکھیں۔ ’’محاکماتُ الشّعرا‘‘ میں محسن نے لکھا ہے کہ ’’کسی ہندوستانی کی طرف سے حزیں کا دل نہ دکھائے جانے کے باوجود انہوں نے ’تذکرۃُ الاحوال‘ میں بادشاہ سے لے کر گدائے بے نوا تک کے خلاف زہر اگلا اور اس خیال کی اشاعت کی کہ ہندوستان فضل و کمال کے لیے زمینِ شور کا حکم رکھتا ہے۔ انہوں نے یہ اعلان بھی کر دیا کہ انہیں تمام دارُالخلافت میں ایک شخص بھی ایسا نظر نہیں آیا جو رتبۂ فضیلت رکھتا ہو۔‘‘ (بحوالہ اردو ادب کی تاریخ از تبسم کاشمیری)
سراج الدّین علی خان آرزو جو اپنے وقت کے بڑے عالم، استاد اور بڑے شاعر تھے، انہوں نے’’ تذکرۃُ الاحوال ‘‘کا حرفاً حرفاً عالمانہ جواب ’’تنبیہ الغافلین‘‘ لکھ کر دیا اور حزیں کی خود سری اور غرور کو توڑنے کے لیے اُس میں پوشیدہ خامیوں اور غلطیوں کی طرف واضح اشارے کیے۔ آرزو کی اس کوشش نے انہیں ہندوستانی شعرا کے درمیان ہیرو بنا دیا۔ اس تاریخی معرکہ آرائی کے بعد ہندوستانی شعرا کو یہ احساس ہو گیا کہ فارسی میں خواہ وہ کتنی بھی دست گاہی حاصل کر لیں، ایرانی النّسل فارسی شعرا انہیں زبان داں تسلیم نہیں کریں گے۔ لہٰذا آرزو نے جو انہیں فارسی کی جگہ ریختہ (اردو) میں شاعری کرنے کی رغبت دلائی تھی، اُس نے اس دور کے نوجوان شعرا کو اِس طرف مائل کر لیا اور یہی دلّی دبستانِ شاعری کا نقطۂ آغاز تھا۔
اُس دور کے نوجوان شعرا جن میں بیش تَر آرزو کے شاگرد تھے، انہوں نے ریختہ میں شاعری کرنا شروع کر دی۔ اُن کے اتباع میں دیگر استاد شاعروں کے شاگردان نے بھی ریختہ کو اپنا لیا۔ اِس طرح ریختہ کی تحریک وجود میں آئی۔
(بھارت سے تعلق رکھنے والی ڈاکٹر عطیہ رئیس کے علمی و تحقیقی مضمون سے انتخاب، یہ تحریر تصوف، اردو شاعری اور اُس کا پیش و پس کے عنوان سے شایع ہوئی تھی)