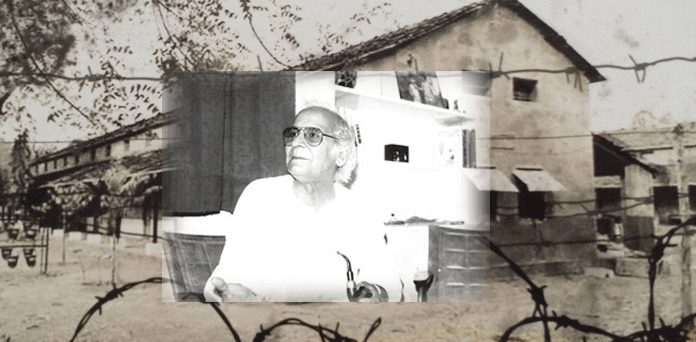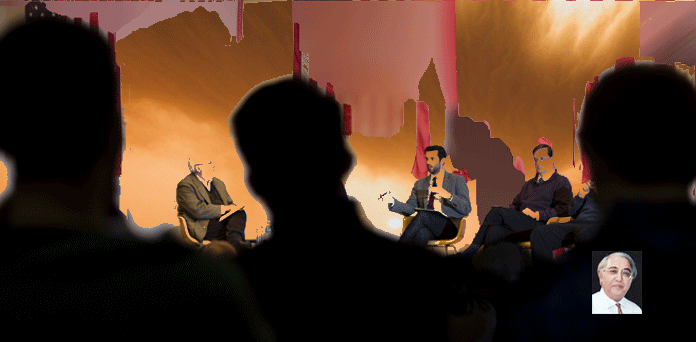کسی ملک میں دانشور حضرات کی اہمیت کو زیادہ نہیں بیان کیا جا سکتا۔ دانشور، اپنے کردار کی وجہ سے اکثر اپنے اپنے ممالک کے شناختی نشان بن جاتے ہیں۔ انھیں پورے معاشرے میں سنا جاتا ہے۔ وہ باقی دنیا کے سامنے اپنی قوم کی سچائیوں کے معیار کے علمبردار بن کر ابھرتے ہیں۔ معاشرے اپنے ارتقاء کے دوران، اپنے دانشوروں کے خیالات اور افکار سے بہت زیادہ اخذ کرتے ہیں۔ دانشوروں کے کردار میں تبدیلی کے عمل کو بتدریج متاثر کرنے والی قوتوں کی تفہیم بھی شامل ہے۔
یہ ذہین طبقہ معاشرے کے اہم حصے کو تشکیل دیتا ہے اور سماجی تبدیلی کے رجحان میں ایک محرک قوت کے طور پر کام کرتا ہے۔ معاشرے بحرانوں کے دور میں رہنمائی کے لیے ان کی طرف دیکھتے ہیں۔ وہ عام طور پر سماجی اور سیاسی اداروں کی ناراضی کا سامنا بھی کرتے ہیں، لیکن جرأت مندی سے فرسودہ نظام پر سوال اٹھاتے رہتے ہیں۔
ایک دانشور کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ کچھ خصوصیات رکھتا ہے جیسا کہ حقیقی اور آزاد فکر، کثیر الشعبہ علمی بنیاد، سماج سے متعلقہ خیالات اور تصورات کا علم ہونا، معاشرے سے منسلک ہونا،اور اگر وہ کسی تعلیمی ادارے سے منسلک ہیں، تو ان کی اسکالر شپ کلاس رومز اور پیشہ ورانہ علمی و تحقیقی تحریروں سے آگے بڑھنی چاہیے، اور، آخر میں، انھیں تمام سماجی اور سیاسی مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے ثابت قدم رہنا چاہیے۔
امریکہ کو آج ایک سپر پاور سمجھا جاتا ہے جس کے پاس مالی اور عسکری طور پر چھوٹے ممالک کو متاثر کرنے کی غیر معمولی صلاحیت ہے لیکن یہ نوم چومسکی کی اینٹی اسٹیبلشمنٹ آواز کے لیے بھی جانا جاتا ہے۔ ان کے علاوہ وہاں، ایڈورڈ سعید، رابرٹ فِسک، انجیلا ڈیوس اور بہت سے ایسے دیگر افراد رہے ہیں جو پوری تاریخ میں معاشروں کے لیے علامتی نشان بنے ہوئے ہیں۔
ہندوستان آج ہندوتوا کی طرف اپنی جنگجو وطن پرست تبدیلی کے لیے جانا جاتا ہے جس نے ریاست اور سماج میں گہرا اثر ڈالا ہے، پھر بھی اس میں رومیلا تھاپر، عرفان حبیب، امریتا سین اور ارون دھتی رائے جیسے دانشور موجود ہیں۔ انگلینڈ میں ایرک ہوبسبوم، ای پی تھامسن، اور بائیں بازو کے نئے مفکرین کا ایک پورا گروپ، اسی طرح جرمن امریکی مفکر ہربرٹ مارکوس 1960 کی دہائی کی کیمپس بغاوتوں میں بحر اوقیانوس کے اس پار طلباء کی بغاوتوں کے بڑے رہنماؤں میں سے ایک شمار ہوتے تھے۔
اس پس منظر کو جاننے کے بعد ہمارے اندر بھی یہ سوال انگڑائی لیتا ہے کہ کیا پاکستان کے پاس بولنے کے قابل کوئی دانشور موجود ہے۔ اگر ہاں، تو یہ کہاں ہے، اور اس کا کردار کیا ہے؟ اگر نہیں تو غائب کیوں ہے؟ یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ ہمارے ہاں بامعنی اور مؤثر فکری گفتگو کی بہت مضبوط روایت کبھی نہیں رہی۔ ہمارے پاس جو کچھ تھا، لگتا ہے کہ وقت کے ساتھ ختم ہو گیا ہے۔ ہماری یونیورسٹیوں کے حوالے سے بات کی جائے تو کیا یہ تضاد نہیں ہے کہ ان کی تعداد گزشتہ سالوں میں کئی گنا بڑھ گئی ہے، لیکن ان کی فکری پیداوار انتہائی کم رہی ہے؟
ہماری تاریخ میں افسانہ نگاروں اور شاعروں کی طرف سے بہت زیادہ مزاحمت سامنے آئی۔ اس طبقے میں ادبی نقاد بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ ممتاز حسین اور مجتبیٰ حسین جیسے ترقی پسند نقادوں کے علاوہ، وہ لوگ تھے جو روایتی بیانیے کے حامی تھے، جیسے محمد حسن عسکری، ایم ڈی تاثیر، ممتاز شیریں اور سلیم احمد۔ یہ نظریات کی جنگ تھی جو ادب کے میدان میں لڑی گئی۔ ہمارے ہاں شاذ و نادر ہی ایسے مصنفین تھے جن کا تعلق سماجی علوم سے تھا، جو پاکستانی سماجی و تاریخی حقائق کے بارے میں لکھتے تھے اور ملک کو افقی اور عمودی تنازعات سے نکالنے کے طریقے تجویز کرتے تھے۔ سیاسی جدوجہد کے لیے ایسا تجزیہ اور وژن کبھی دستیاب نہیں ہوا جو بڑے پیمانے پر دور اندیشی پر مبنی ہو۔ ایسی فکر اور تجزیہ کی عدم دستیابی کی وجہ ہم ملک کو اعلیٰ جمہوری اہداف کی طرف لے جانے میں ناکام رہے ہیں۔
سماجی و اقتصادی تجزیہ کی عدم موجودگی نے سیاسی تحریکوں کے حامیوں کو جوش دلانے کے لیے شاعری پر بہت زیادہ انحصار کرنے پر مجبور کیا، لیکن اس سے وہ مقصد پورا نہیں ہو سکا جس کو حاصل کرنے کے لیے یہ تحریکیں شدت سے کوشش کر رہی تھیں۔ معروف ماہر عمرانیات حمزہ علوی نے رائے دی کہ تنقیدی سماجی تجزیہ کی عدم موجودگی میں، شاعری افیون کا کام کرتی ہے: عام لوگوں کو عارضی سکون اور ایک عارضی فروغ۔ علوی اور دیگر — جیسے اقبال احمد، فیروز احمد، صغیر احمد وغیرہ، جنہوں نے پاکستان کے سماجی و اقتصادی حقائق کے بارے میں لکھا اور ٹھوس حل پیش کیے، وہ تقریباً سبھی بیرون ملک مقیم تھے: ایک وجہ شاید یہ بھی تھی کہ وہ ایسا کرنے کے قابل ہوئے جو انھوں نے کیا۔ ملک کے اندر ایسا کام ہمیں بہت زیادہ نظر نہیں آتا تھا، یا قابل عمل بھی نہیں تھا۔
سبط حسن ایک قابل ذکر اسکالر تھے، جنہوں نے نہ صرف تاریخ اور پاکستانی خطے اور مشرق وسطیٰ میں تہذیب کے ارتقا کے بارے میں لکھا، بلکہ ساتھ ساتھ کچھ بنیادی سیاسی اور نظریاتی مسائل پر بھی توجہ دی، جیسے ریاست اور مذہب کے درمیان تعلق اور اس کے ساتھ ریاستوں کے تاریخی سلوک، جسے اسلامی ریاست کے طورپر نام دیا جاتا ہے۔ علی عباس جلالپوری نے اپنی متعدد کتابوں میں فلسفیانہ، تاریخی اور سیاسی مسائل کو عقلی انداز میں پیش کیا ہے۔صفدر میر (زینو) نے ملک کی متنوع ثقافتوں کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے ثقافتی مسائل پر وسیع پیمانے پر لکھا۔خواجہ مسعود نہ صرف ریاضی کے پروفیسر تھے بلکہ تاریخ، سماجیات اور ثقافتی امور کے بھی ماہر تھے۔ ان کی تحریریں تقریباً ایک چوتھائی صدی تک رہنمائی کا ذریعہ بنی رہیں۔ ابراہیم جویو نے نظریات کی تاریخ اور تاریخ میں ثقافتی تبدیلیوں پر انگریزی اور سندھی دونوں زبانوں میں لکھا۔ اس سے آگے دیکھتے ہیں تو وارث میر نے خاص طور پر جنرل ضیاءالحق کے مارشل لاء کے دوران اسٹیبلشمنٹ کو اس کے آمرانہ سرکاری بیانیے پر آڑے ہاتھوں لیا۔ آئی اے رحمان بھی آئینی، سیاسی اور انسانی حقوق کے مسائل پر مستقل مصنف اور مقرر رہے ہیں۔ مبارک علی نے سرکاری تاریخ نویسی کی خامیوں پر روشنی ڈالی اور اپنے قارئین کو تاریخ نویسی کی نئی اور متنوع جہتوں سے روشناس کرایا، جیسا کہ یہ دوسرے ممالک میں تاریخ دانوں اور محققین کو تازہ نتائج کی طرف لے جا رہے ہیں۔ شاہ محمد مری نے بلوچ تاریخ اور دیگر تاریخی موضوعات پر بہت زیادہ لکھا ہے۔
یہ فہرست ان مذکورہ چند افراد یا بعض دوسرے ایسے نامور حضرات سے زیادہ آگے نہیں جاتی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں دانشوروں کی کمی ہے کیونکہ ملک میں فکری روایت محدود ہو چکی ہے۔ دانشوروں کا وہ حصہ جو سماجی اسکالر ہونے کی وجہ سے اپنی اہمیت حاصل کرتا ہے وہ اس سے بھی چھوٹا ہے۔ وہ لوگ جو معاشرے سے براہ راست جڑ سکتے ہیں اور سماجی، اقتصادی اور سیاسی مسائل پر بات کر سکتے ہیں ان کا اثر زیادہ ہوتا ہے، لیکن یہ ایک زیادہ مشکل کام بھی ہوتا ہے۔ ایسے دانشور حضرات کو لوگوں کے لیے قابل فہم زبان بولنے کی ضرورت ہے اور عوام کے لیے مشکل موضوعات کو واضح کرنے کے لیے مواصلات کی مہارت حاصل کرنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ سبط حسن، مبارک علی، قاضی جاوید، حسن ظفر عارف، اشفاق سلیم مرزا اور پرویز ہود بھائی نے یہ کام کیا ہے۔
ہماری یونیورسٹیوں نے اتنے کم فکری نتائج اور اتنے کم دانشور کیوں پیدا کیے ہیں، اس کی کئی وجوہات بیان کی جا سکتی ہیں۔ سرکاری یونیورسٹیوں نے سخت سرکاری کنٹرول میں کام کیا ہے۔ ان کی خود مختاری صرف کاغذوں پر رہ گئی ہے۔ نظام تعلیم، خاص طور پر اعلیٰ تعلیم، براہ راست اور مؤثر طریقے سے مرکزی حکومت کے زیر کنٹرول ہے:یہاں تک کہ نصاب بھی سرکاری طور پر وضع کیا جاتا ہے۔اس سے فیکلٹی کی اکثریت کے پاس کوئی آپشن نہیں رہ جاتا ہے کہ وہ اپنی آزادی کو بروئے کار لانے اور اصل خیالات کے ساتھ آگے بڑھنے کے بجائے یونیورسٹی کی جانب سے عائد شرائط کی پابندی کرے۔
مزید یہ تعلیمی نظام ایسا ہے کہ تحقیق کے کلچر کو جڑ پکڑنے اور پنپنے نہیں دیتا۔ برسوں سے رائج اس انتظام کے نتیجے میں سیلف سنسرشپ کا ایک گھٹیا کلچر نکلا اور جو لوگ اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں وہ حکام کی طرف سے ان کی ‘نافرمانی’ کے لیے نشان زد ہیں۔ ایک حقیقی محقق کے لیے ایسی تحقیق کرنا بہت مشکل ہے جو سرکاری طور پر منظور شدہ پیرامیٹرز کے اندر نہ ہو، کیونکہ اس کے نتیجے میں گرانٹس اور ریسرچ فنڈز سے انکار ہوتا ہے۔اگر کچھ لوگ اب بھی بیڑیاں توڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہمت سے لکھتے اور بولتے ہیں تو وہ مشکل آزمائشوں سے گزرتے ہوئے ایسا کرتے ہیں۔
ماضی میں اختلاف کرنے والے نامور اساتذہ کی ایک بڑی تعداد کو یا تو یونیورسٹیوں سے نکال دیا گیا یا انھیں معطل کر دیا گیا۔ یہ ضیاء کے فوجی دور میں زیادہ ہوا، جب قائداعظم، پنجاب اور کراچی یونیورسٹیوں سے اساتذہ کو نکال دیا گیا۔ تنقیدی فکر اور تحقیق کے قریب المرگ ہونے کے نتیجے میں، اینٹی اسٹیبلشمنٹ اسکالر شپ کا خاتمہ بھی ہوتا دکھائی دے رہا ہے، یہاں تک کہ اب روایتی اور سرکاری بیانیے کو بھی اپنے آپ کو برقرار رکھنے کے لیے پیشہ ور اسکالرز نہیں ملتے ہیں۔
(ماہر تعلیم اور مصنّف ڈاکٹر سید جعفر احمد کے مضمون سے اقتباسات)