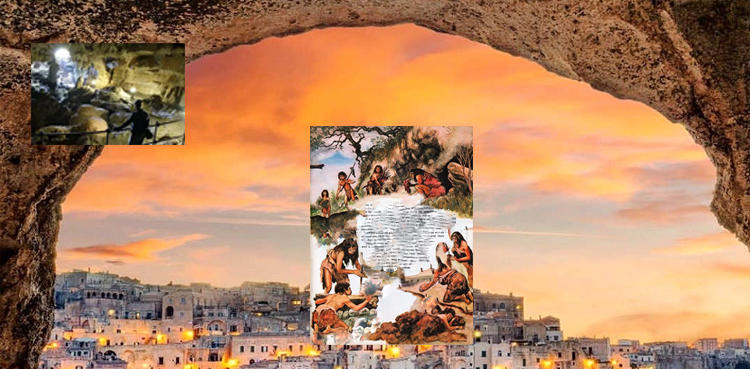انسان کے تمام افعال اور ارادے، اس کا ہاتھ پاؤں ہلانا، اس کا دیکھنا، بولنا، کھانا پینا، غرض اس کا ہر جسمانی اور ذہنی عمل دماغ ہی کے تابع ہوتا ہے اور اگر دماغ اپنا عمل ترک کر دے تو انسان جیتے جی انسانیت سے محروم ہو جاتا ہے۔ وہ زندہ لاش بن جاتا ہے۔
خیال پرست فلسفیوں نے شاید دماغ کی انہیں خصوصیتوں سے متاثر ہو کر یہ دعویٰ کیا تھا کہ موجوداتِ عالم ہمارے دماغ کا عکس ہیں۔ دماغ سے باہر ان کا کوئی حقیقی وجود نہیں ہے لیکن یہ باتیں اب پرانی ہو چکی ہیں کیونکہ جدید سائنس نے ثابت کردیا ہے کہ یہ کرۂ ارض نہ صرف انسان اور اس کے دماغ سے کروڑوں برس پہلے سے موجود ہے بلکہ خود انسان زمین ہی کے مادّوں کا ترقی یافتہ پیکر ہے، اور اس کا دماغ بھی زمین ہی کے مادّی اجزا سے بنا ہے۔ ایسی صورت میں جو مقدم ہے وہ مؤخر کا عکس کیسے ہو سکتا ہے۔ اب علمُ الاجسام نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ دماغ کی ساخت اور اس کا طریقہ کار کوئی پُراسرار معمہ باقی نہیں رہا، جس کو فلسفیانہ قیاس آرائیوں سے حل کیا جائے۔ اب تو معمولی ڈاکٹر بھی بتا سکتا ہے کہ ہمارا دماغ خارجی دنیا سے کس کس طرح اثر قبول کرتا ہے۔ نیز یہ کہ دماغ کے خلیوں اور شریانوں کا بقیہ جسم سے کیا تعلق ہے۔
ہمارے اعصابی نظام کا محور دماغ (ریڑھ کی ہڈی) ہے۔ دماغ میں دس ارب سے سو ارب تک اعصابی خلیے ہوتے ہیں اور ہر خلیہ دوسرے خلیوں سے ایک ہزار ریشوں کے ذریعہ جڑا ہوتا ہے۔ جسم کے اندر اور باہر کی تمام اطلاعیں انہیں پیچ در پیچ راہوں سے شعور کی مختلف سطحوں تک پہنچتی ہیں۔ چنانچہ ہمارے علم، حافظے اور خیال کی لاکھوں کروڑوں شکلیں انہیں اعصابی خلیوں کی مرہون منت ہیں۔ مثلاً آنکھ جس سے ہم دیکھتے ہیں اس کے بالائی پردے (RETINA) میں تیرہ کروڑ خلیے ہوتے ہیں جو خارجی اثر قبول کرتے ہیں۔ یہ بالائی پردہ دس لاکھ سے زائد اعصابی ریشوں کے ذریعہ دماغ سے جڑا ہوتا ہے۔
دماغ اپنا فریضہ انہیں اربوں اعصابی خلیوں کے ذریعہ سر انجام دیتا ہے۔ مثلاً فرض کیجئے کہ آپ کو چوٹ لگتی ہے۔ آلۂ ضرب جیوں ہی آپ کی کھال کو چھوئے گا کھال کے خلیوں میں ہیجان اٹھے گا۔ یہ ہیجان آپ کے مرکزی اعصابی نظام (دماغ اور ریڑھ کی ہڈی) میں دوڑ جائے گا اور آپ چوٹ کو آناً فاناً محسوس کر لیں گے۔ اگر آپ کو آلۂ ضرب کی نوعیت کا تجربہ ہے تو آپ کا دماغ یہ بھی بتا دے گا کہ چوٹ کس چیز سے لگی ہے۔ اور یہ ساری اطلاع تار برقی سے بھی کم وقت میں پل جھپکتے موصول ہو جائے گی۔ کسی اطلاع کی دماغ تک رسائی کی نوعیت برقی اور کیمیاوی ہوتی ہے۔
سب سے پہلے انسان کے حسی اعضا آنکھ، کان، ناک، زبان اور کھال میں برقی ہیجانات پیدا ہوتے ہیں۔ ان ہیجانات کی بے شمار قسمیں ہوتی ہیں اور وہ بے حد پیچیدہ ہوتے ہیں، تب اعصابی خلیوں کو آپس میں ملانے والے ریشوں کے جوڑوں پر جو جھلی چڑھی ہوتی ہے یہ برقی لہر ان پر دوڑنے لگتی ہے۔ اس عمل سے ایک بہت ہی مختصر سا کیمیاوی ٹرانس میٹر خارج ہوتا ہے جو دوسرے خلیوں میں ہیجان پیدا کرتا ہے۔ اس طرح ایک اعصابی خلیے کا عمل دوسرے پر اور دوسرے کا تیسرے پر ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ اطلاع دماغ تک پہنچ جاتی ہے۔
انسان کو سب سے پہلے اپنے حسی ماحول کا شعور ہوا، یعنی اس ماحول کا جو بالکل ہی اس کے گرد و پیش تھا۔ پھر اس کو اس محدود رشتے کا شعور ہوا، جو اس کو دوسرے افراد یا اشیا سے قائم کرنے پڑے۔ اسی کے ساتھ اسے تھوڑا بہت اپنی ذات کا شعور بھی ہوا اور تب اسے موجودات عالم۔۔ ۔ نیچر۔۔ ۔ کا شعور ہوا لیکن اس وقت تک نیچر سے انسان کا رابطہ دراصل حیوانی رابطہ تھا۔ البتہ جب انسان کی ضرورتیں بڑھیں۔ اس نے ان ضرورتوں کی تسکین کے لئے آلات و اوزار بنائے، تقسیم کار نے رواج پایا اور جسمانی اور دماغی محنت کی تقسیم ہوئی تو اس غلط فہمی کی بنیاد پڑی کہ شعور گرد و پیش کے ماحول اور سماجی حالات زندگی سے الگ کوئی آزاد یا وجود بالذات حقیقت ہے۔ حالانکہ شعور ہمیشہ انسانوں کے ذہن سے باہر کی حقیقتوں کا شعور ہوتا ہے۔ خواہ یہ حقیقتیں مادی ہوں یا غیر مادی (انصاف، مساوات، جمہوریت وغیرہ) اور سماجی حالات کا پابند ہوتا ہے۔
ہر تہذیب کا مخصوص نظام فکر و احساس ہوتا ہے۔ یہ نظام اس رشتے کی نوعیت کو ظاہر کرتا ہے جو معاشرے کے افراد اور موجودات میں استوار ہوتا ہے۔ چنانچہ انسان کے حالات وجود جس سطح پر ہوں گے اس کے شعور کی سطح بھی وہی ہو گی۔ جمادات، نباتات، حیوانات اور دوسرے انسانوں سے اس کا رابطہ جس قسم کا ہو گا، اس کے سوچنے اور محسوس کرنے کا انداز، اور اس کے عقائد و رجحانات بھی اسی کے مطابق ہوں گے۔ جنگلی دور کے انسان میں خدائے واحد کا یا جنت دوزخ کا، یا یوم حشر کا شعور پیدا نہیں ہو سکتا تھا اور نہ قرون وسطیٰ کا انسان ارتقا، اضافیت، اور جوہری توانائی کے نظریے دریافت کر سکتا تھا۔
یہ تغیرات آلات و اوزار اور سماجی روابط میں تبدیلی کی وجہ سے آتے ہیں۔ دراصل نظام فکر و احساس کی تبدیلی خود اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ معاشرے کی تخلیقی اساس اب وہ نہ رہی جو پہلے تھی۔ مثلاً پتھر کے زمانے کی تہذیب کو لیجئے۔ اس وقت انسان تیر کمان، بلم بھالے سے شکار کر کے یا خود رو درختوں کے پھل پھول کھا کر ہی اپنی ضرورتیں پوری کرتا تھا۔ وہ مادے کی ہیئت (پتھر کی نکیلی انیاں، کمان وغیرہ) اور کیفیت (لکڑی سے آگ) میں تھوڑی بہت تبدیلی کر لیتا تھا۔ اس نے اپنی روز مرہ کے سماجی تجربوں سے (قوتِ گویائی کی مدد سے) گرد و پیش کی چیزوں کے خواص معلوم کر لئے تھے اور ان کے نام بھی متعین کر لئے تھے لیکن وہ مظاہر قدرت کی حرکت کے اسباب و علل سے بالکل واقف نہ تھا اور نہ اس کو طبعی تبدیلیوں کے قوانین کا شعور تھا۔ مثلاً وہ تمام موجودات، دریا پہاڑ، سورج چاند، زمین آسمان، جانور درخت، آندھی، طوفان، سیلاب زلزلہ، اولے، بارش کو اپنی طرح فعال اور با ارادہ شخصیتیں سمجھتا تھا۔ چونکہ ان چیزوں سے اس کو ہر وقت سابقہ پڑتا تھا بلکہ اس کی زندگی کا انحصار ہی ان کے ’’طرز عمل‘‘ پر تھا۔ لہٰذا جو چیزیں اس کو سکھ دیتی تھیں ان کو وہ پسند کرتا تھا اور جو چیزیں اسے دکھ پہنچاتی تھیں ان سے وہ ڈرتا تھا (بعد میں یہی نیکی اور بدی، خیر و شر کی قوتیں قرار پائیں۔)
چنانچہ ان کی تسخیر کے لئے وہ جادو منتر سے کام لیتا تھا یا ان کی رضا جوئی کے لئے عبادت اور ریاضت کرتا تھا۔ وہ حیات اور موت میں بھی تمیز نہیں کر سکتا تھا اور نہ اس کے ذہن میں موت کا کوئی تصور تھا۔ اس کا نظام فکر و احساس افزائش نسل اور اور افزائش خوراک کی ضرورتوں کے محور پر گھومتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ مادہ جنس کو نَر جنس پر فوقیت دیتا تھا۔ کیونکہ اس کا مشاہدہ یہی کہتا تھا کہ انسان ہو یا جانور مادہ ہی کے پیٹ سے نئی نسل پیدا ہوتی ہے۔ اسپین اور فرانس کے غاروں میں پتھر کے زمانے کی جو دیواری تصویریں اور مجسمے ملے ہیں، ان سے اس دعویٰ کی پوری پوری تصدیق ہوتی ہے۔
جہاں تک تحفظ ذات کا تعلق ہے، دور حاضر کے انسان نے بیشتر بیماریوں پر قابو پا لیا ہے اور علاج کے امتناعی و شفائی طریقوں نے بھی بہت ترقی کر لی ہے، لیکن ابتدائی انسان نہ تو بیماریوں کے اسباب سے واقف تھا اور نہ اس کو علاج کے طریقے آتے تھے۔ اس کو جڑی بوٹیوں، نمکوں اور دوسری نباتات و معدنیات کی شفا بخش تاثیر کا علم لاکھوں برس کے تجربے کے بعد ہوا ہے۔ اس تجربے کے کارن نہ جانے کتنوں کی جانیں گئی ہوں گی تب کہیں علم طب کی بنیاد پڑی ہو گی۔ اس بات کو ابھی پانچ چھ ہزار برس سے زیادہ عرصہ نہیں گزرا ہے۔ چنانچہ کانسے کے زمانے میں بھی عام عقیدہ یہی تھا کہ بیماری کا باعث کسی رب النوع، کسی دیوی دیوتا یا جن بھوت کی خفگی ہے۔ اسی لئے لوگ دوا دارو کے بجائے جھاڑ پھونک، دعا تعویذ، نذر نیاز کو زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ یہاں تک کہ انجیل مقدس کے مطابق حضرت عیسیٰؑ بیماروں کے بدن سے بد روحیں نکال کر اپنی مسیحائی کے معجزے دکھاتے تھے۔
عقائد کی سخت گیری کا عالم یہ ہے کہ آج بھی جب کہ سائنس نے تجربے سے ثابت کر دیا ہے کہ تمام ذہنی اور جسمانی بیماریوں کے اسباب مادی ہوتے ہیں اور کوئی مافوق الفطرت طاقت ان خرابیوں کی ذمہ دار نہیں ہے، ہمارے ملک کے لاکھوں کروڑوں باشندوں کا ایمان ہے کہ پیروں فقیروں کے مزار پر منت ماننے یا دعا تعویذ سے بیماریاں دور ہو سکتی ہیں۔ بالخصوص پاگل پن، مرگی اور ہیسٹریا جیسی نفسیاتی اور اعصابی بیماریاں، جن کے باقاعدہ علاج کا ابھی تک ہمارے ملک میں مناسب انتظام نہیں ہے۔ شعور کی یہ پستی اس بات کا ثبوت ہے کہ یہاں کے بیشتر علاقوں کے سماجی حالات اور پیداواری آلات میں کانسے کے زمانے سے اب تک بہت کم تبدیلی ہوئی ہے۔ زندگی پرانے ڈگر پر بدستور چل رہی ہے اور حاکم طبقوں کی برابر یہی کوشش ہے کہ لوگ سائنسی علم کی روشنی سے محروم رہیں اور توہم پرستیوں میں بدستور مبتلا رہیں۔
کانسی کی تہذیبوں کا انداز فکر و احساس زیادہ ترقی یافتہ تھا۔ کیونکہ کانسے کے دور میں پیداواری آلات و اوزار بہتر ہو گئے تھے۔ پیداوار اور آبادی بڑھ گئی تھی۔ کاموں کی تقسیم میں اضافہ ہو گیا تھا۔ پتھر کے زمانے کا معاشرہ سفری اور شکاری معاشرہ تھا۔ کانسے کا معاشرہ حضری اور زرعی معاشرہ تھا۔ مصر، یونان، وادی دجلہ، وادی سندھ، وادی گنگ و جمن اور ایران کی پرانی تہذیبیں کانسے کی تہذیبیں تھیں۔ ان کے عظیم الشان تخلیقی کارناموں کو بیان کرنے کے لئے دفتر درکار ہوں گے۔ کانسے کے زمانے کا انسان ہل بیل کی مدد سے کھیتی باڑی کرتا تھا۔ اسے تجربے سے معلوم ہو گیا تھا کہ جو بوؤ گے وہی کاٹو گے۔
زمین کو جوتنے والے ہل، کمہار کا چاک، پہیہ دار گاڑیاں، سوت اور اون کاتنے کے چرخے اس دور کے پیداواری آلات و اوزار تھے۔ مٹی کے برتنوں کو آگ میں پکانا، دھاتوں کو پگھلانا، کپڑے بننا، عمارتیں بنانا، شہر بسانا اور مٹی کی لوحوں یا درخت کی چھالوں یا جانور کی کھالوں پر صوتی علامتوں کے نقوش بنانا (فن تحریر کی ایجاد) ان کے ہنر تھے۔ مختصر یہ کہ انسان پہلی بار کانسے کے دور ہی میں قسم قسم کی مادی تخلیقات پر خود قادر ہوا تھا۔ گویا پہلی بار صحیح معنی میں انسان بنا تھا۔
اس مضمون میں گنجائش نہیں ہے ورنہ ہم تفصیل سے بتاتے کہ کانسے کے زمانے کی تخلیقی سرگرمیوں کا اس دور کے نظام فکر و احساس سے کیا رشتہ ہے۔ اور اس دور کے عقائد، ذہنی رجحانات، علم و ادب اور فنونِ لطیفہ کس کس طرح اپنے سماجی حالات یعنی طرز معاشرت کی عکاسی کرتے ہیں۔ مثلاً جب معاشرے میں طبقات قائم ہوئے اور ذاتی ملکیت نے رواج پایا اور معاشی اور سیاسی اقتدار مطلق العنان بادشاہوں، دربار کے امیروں اور پروہتوں کے ہاتھ میں آیا تو ان طبقوں نے اپنے معاشرتی نظام سے ملتا جلتا اور اس کے متوازی پوری کائنات کے نئے نئے عقیدوں نے رواج پایا۔
جس طرح زمین پر بادشاہوں کی مطلق العنان حکومت تھی، اسی قسم کی مطلق العنان حکومت آسمان پر بھی قائم کی گئی۔ جس طرح زمین پر عام انسانوں کی زندگی اور موت بادشاہ کے اختیار میں تھی اور اس کی تقدیر کا فیصلہ حاکم وقت کرتا تھا، اسی طرح کا اختیار کائنات کے قادر مطلق خداؤں زیوس، رَع، مردوک، بَعل، اہومزوا، ایشور وغیرہ سے منسوب کیا گیا۔ جزا سزا، دوزخ جنت، ملائکہ اور مقربین، شیاطین اور بھوت پریت، حساب و کتاب، حشر و نشر، میزان اور عدالت، غرض کہ افکار و عقائد کا ایک باقاعدہ نظام مرتب ہو گیا، جو غور سے دیکھا جائے تو اس دور کی مطلق العنان بادشاہوں کا ہوبہو چربہ نظر آئے گا۔ شعور کی کمی کے باعث انسان عالمِ موجودات کی سائنسی توجیہ و تشریح نہیں کر سکتا تھا۔ لہذا اس نے کائنات کے نظام عمل کو بھی اپنے سماجی نظام کے حوالے سے دیکھا۔ سماجی نظام کے چربے یا عکس کو اصل خیال کیا اور جو اصل حقیقت تھی، اسے نظام کائنات کا چربہ یا عکس سمجھا۔
اسی طرح کانسی کے دور کی نظموں اور داستانوں میں، گیتوں اور گانوں میں، مجسموں اور رنگین تصویروں میں غرضیکہ تمام ذہنی اور حسی تخلیقات میں لوگوں کی طرز زندگی کا، جذبات و خواہشات کا، ان کے غموں اور خوشیوں کا، پسند اور ناپسند کا، عادات و اطوار کا، عشق و محبت کی قلبی واردات کا، اخلاق اور آداب کا بڑا دلکش اور خیال آفریں نقشہ ملتا ہے۔
ہر معاشرے کا نظامِ فکر و احساس سماجی شعور کے تابع ہوتا ہے اور یہ سماجی شعور سماجی حالات کے مطابق ہوتا ہے۔ مثلاً انسان ہزاروں سال سے یہی یقین کرتا چلا آتا تھا کہ کائنات کا مرکز و محور زمین ہے اور چاند سورج زمین کے گرد گھومتے رہتے ہیں۔ دوسرا عقیدہ یہ تھا کہ زمین فرش کی طرح بچھی ہوئی ہے۔ ہماری آنکھیں بھی اس عقیدے کی تصدیق کرتی ہیں بلکہ اس عقیدے کی بنیاد ہی ذاتی مشاہدہ پر تھی۔ اگر کوئی دانشور ان عقائد سے اختلاف کرتے ہوئے کہتا تھا کہ سورج چاند کی گردش ہماری نظر کا دھوکا ہے۔ دراصل زمین گھومتی ہے تو اسی پر کفر و الحاد کے فتوے لگائے جاتے تھے۔ اس کو آگ میں زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ البتہ جب دور بین، خورد بین اور اسی نوع کے دوسرے آلات ایجاد ہوئے تو ثابت ہو گیا کہ یہ سارا نظام بطلیموسی جس کی صداقت مقدس کتابوں سے ثابت کی جاتی تھی، واقعی قیاس آرائی اور نظر کا دھوکہ تھا۔
پھر رفتہ رفتہ اور آلات ایجاد ہوئے اور انسان نے اپنے تجربے سے معلوم کر لیا کہ بارش سیلاب، آندھی طوفان، بجلی زلزلے، خشک سالی سب کے مادی اسباب ہیں اور ان کی بابت وثوق سے پیشن گوئی کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح یہ بھی پتہ چل گیا کہ زمین، چاند، سورج اور دوسرے مظاہر قدرت مادے کی مختلف شکلیں ہیں۔ ان کی حرکت کے مادی قانون ہیں اور یہ کہ مادہ فنا نہیں ہوتا بلکہ جون بدلتا رہتا ہے۔ ان انکشافات و ایجادات سے انسان کے افکار و عقائد میں جو عظیم انقلاب آیا وہ اظہر من الشمس ہے۔
یہی حال تخلیق کے عقیدے کا ہے کہ ہر مذہب کی اساس اس پر قائم ہے۔ عقیدۂ تخلیق کے اہم نکتے دو ہیں۔ اوّل یہ کہ موجوداتِ عالم مخلوق ہیں یعنی وہ از خود عدم سے وجود میں نہیں آئے بلکہ ان کا کوئی خالق ضرور ہے۔ دوم یہ کہ یوم تخلیق سے آج تک یہ تمام اشیاء- جانور، انسان، نباتات، جمادات، جوں کی توں موجود ہیں۔ ان میں ابد تک کوئی تبدیلی نہیں ہو گی۔ یوں تو عہد قدیم کے متعدد یونانی، لاطینی اور ہندوستانی مفکر (ہیراک لاٹی ٹوئس، لوکری شیش، گوتم بدھ، چار واک وغیرہ) ان عقیدوں کو نہیں مانتے تھے لیکن عقلی دلائل کے علاوہ ان کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت انکار کے حق میں نہ تھا۔ البتہ ۱۹ویں صدی میں جب ڈارون اور دوسرے سائنسدانوں نے ارتقا کا نظریہ پیش کیا اور ٹھوس شواہد اور آثار سے ثابت کیا کہ حیوانوں کو کسی نے خلق نہیں کیا ہے اور نہ وہ ازل سے یکساں موجود ہیں بلکہ ان میں نوعی تبدیلیاں ہوتی رہی ہیں اور جانوروں نے بشمول انسان ارتقاء کے مختلف ادوار سے گزر کر موجودہ شکل اختیار کی ہے تو انسان کے افکار و عقائد میں بھی بڑی تبدیلیاں پیدا ہوئیں۔
اوپر کی باتوں سے ہم اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ ہمارے افکار و احساسات آسمان سے نہیں ٹپکتے اور نہ زمان و مکان کی قید سے آزاد ہوتے ہیں بلکہ تہذیب کے دوسرے عوامل کی طرح سماجی حالات کی پیداوار ہوتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ ہر تہذیب کے نظام فکر و احساس میں وقتاً فوقتاً تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں اور ان تبدیلیوں کا باعث سماجی حالات میں تغیرات ہیں لیکن سماجی حالات اس وقت تک نہیں بدلتے جب تک خود معاشرے کے اندر کوئی ایسی سماجی قوت نہ ابھرے جو ان حالات کی نفی کرتی ہو۔
اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ خیالات ہمارے ذہن کی فقط انفعال یا مجہول کیفیت ہوتے ہیں یا وہ ہمارے طرز عمل یا معاشرے پر کوئی اثر نہیں ڈالتے۔ حقیقت یہ ہے کہ خیالات میں بڑی طاقت، بڑی توانائی ہوتی ہے۔ خیالات انسان کی قوت عمل کو حرکت میں لاتے ہیں۔ اس کی سرگرمیوں کا رخ متعین کرتے ہیں۔ اس میں ایمان، یقین اور ولولہ پیدا کرتے ہیں اور اسے اپنی زندگی کا فلسفہ متعین کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ مگر جوں ہی ہم یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ فلاں فلسفہ دسویں صدی میں کیوں نمودار ہوا، دوسری صدی میں انسانوں کے ذہن میں کیوں نہیں ابھرا، یا فلاں نظریہ انیسویں صدی میں کیوں نمودار ہوا، پانچویں صدی میں کیوں نہ ابھرا تو پھر ہم کو لازمی طور پر اس مخصوص صدی میں انسان کے حالات زندگی کو جانچنا پڑتا ہے۔ ان کی ضروریات زندگی کیا تھیں، وہ ان ضرورتوں کو کس طرح پورا کرتے تھے، ان کے پیداواری عناصر اور آلاتِ پیداوار کیا تھے اور ان کے معاشرے میں انسان انسان کے درمیان کیا روابط تھے اور جب ہم ان سوالوں کے جواب پر غور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ انسان اپنی تاریخ کا مصنف بھی ہے اور تاریخ کے ڈرامے کا اداکار بھی۔
(اردو کے نامور ترقی پسند دانش ور، صحافی اور ادیب سبطِ حسن کی مشہور تصنیف قومی تہذیب سے اقتباس)