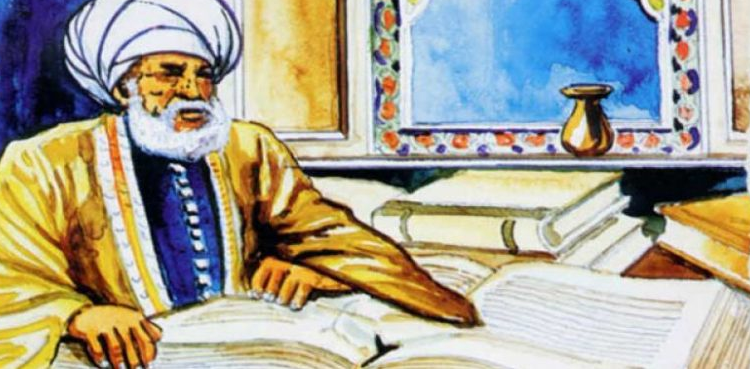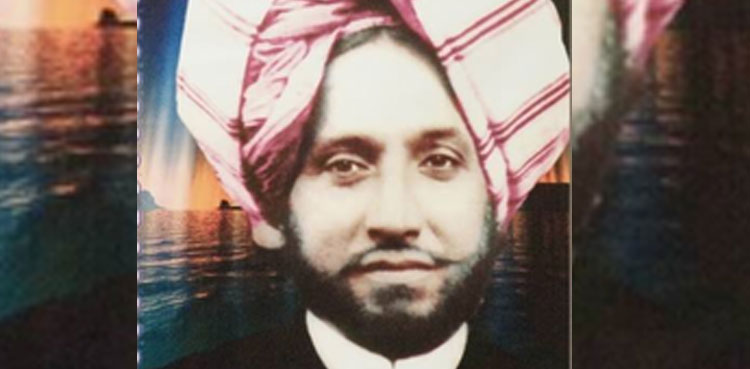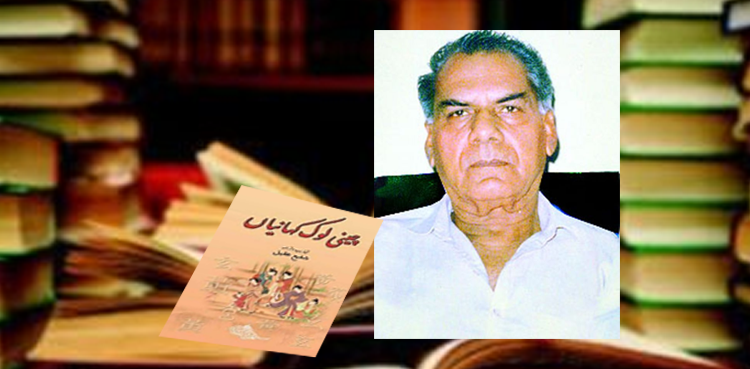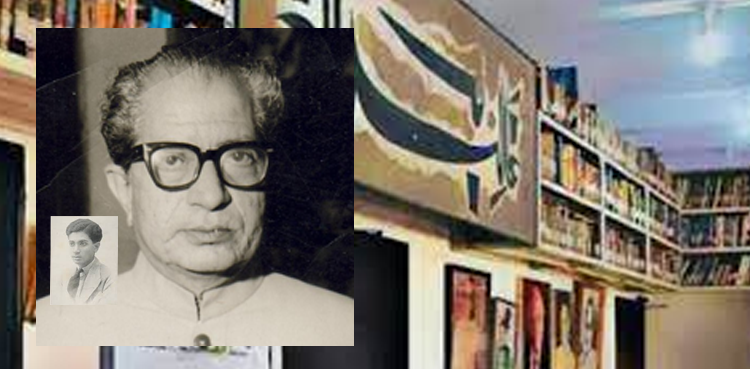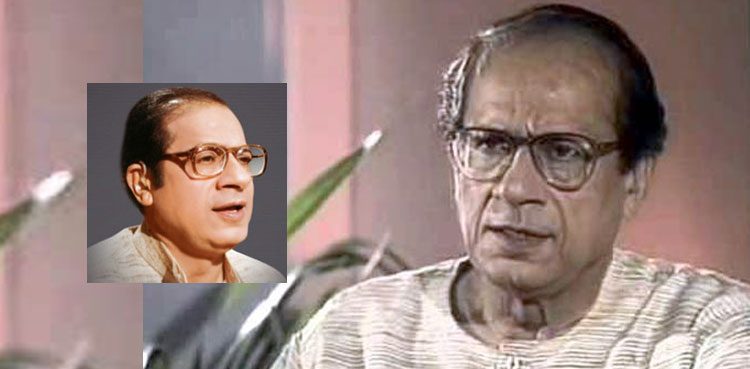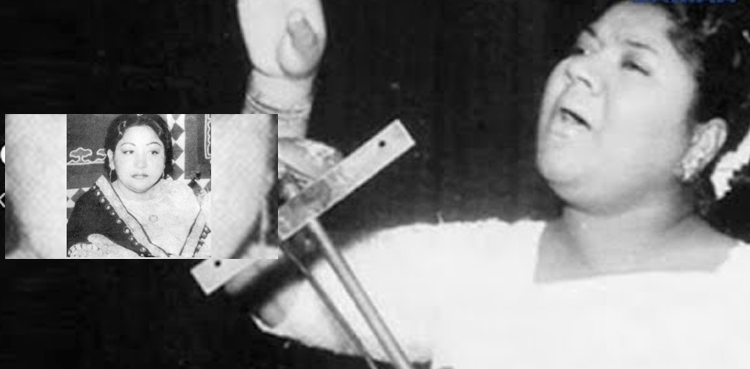غلام علی آزاد بلگرامی کو ان کے دینی ذوق و شوق، علمی و تحقیقی کام کے سبب بڑا مقام و مرتبہ حاصل ہے۔ انھیں ہندوستان کی عالم فاضل بزرگ شخصیات میں شمار کیا جاتا ہے جو شعر و ادب، تاریخ اور تذکرہ نگاری میں اپنی بلند پایہ تصانیف کی وجہ سے مشہور ہوئے۔
غلام علی آزاد بلگرامی نواب ناصر جنگ والیِ حیدر آباد دکن کے استاد تھے۔ وہ بلگرام سے اورنگ آباد آئے تھے جہاں ان کے علم و فضل کے سبب انھیں دربار میں جگہ ملی اور بڑی عزّت اور پذیرائی حاصل ہوئی۔ انھیں عربی، فارسی، اردو اور ہندی زبانوں پر عبور حاصل تھا۔
1704ء میں پیدا ہونے والے غلام علی آزاد کا تعلق بلگرام سے تھا اور اسی نسبت ان کے نام کے ساتھ بلگرامی لکھا جاتا ہے۔ 15 ستمبر کو اورنگ آباد میں قیام کے دوران ان کی زندگی کا سفر تمام ہوا۔ 1786ء میں اس دارِ فانی سے رخصت ہوجانے والے آزاد بلگرامی کو حسّانُ الہند بھی کہا جاتا ہے۔
حضرت غلام علی آزاد بلگرامی بیک وقت مختلف علوم و فنون میں طاق اور متعدد زبانوں پر کامل عبور رکھنے کے باعث اپنے ہم عصروں میں ممتاز رہے۔ انھیں نثر و نظم پر یکساں قدرت حاصل تھی۔ وہ تصنیف و تالیف اور شعر و شاعری تک ہی محدود نہ رہے بلکہ علمی میدان میں اپنے افکار و خیالات کے لازوال نقش چھوڑ گئے۔
ان کی نثری تالیف میں’’شمامہ العنبر فی ما ورد فی الہند من سید البشر‘‘ کے علاوہ سبحۃ المرجان جو دراصل علمائے ہند کا تذکرہ ہے، نہایت وقیع و مستند کتاب مانی گئی۔ اسی طرح یدِ بیضا کو بھی شہرت ملی، جو عام شعرا کے تذکرے سے سجائی گئی ہے۔ خزانۂ عامرہ بھی ان کی وہ یادگار ہے جس میں اُن شعرا کا تذکرہ ہے جو صلہ یافتہ تھے جب کہ سرورِ آزاد ہندی نژاد شعرا پر غلام علی آزاد بلگرامی کی ایک نہایت معلوماتی اور مفید کتاب ہے۔ مرحوم نے اپنی ایک اور تصنیف مآثر الکرام کی بدولت بڑی عزّت اور نام پایا جو دراصل علمائے بلگرام کے تذکرے پر مبنی ہے۔ اسی طرح روضۃُ الاولیا میں انھوں نے عرق ریزی سے اپنی تحقیق کے بعد اولیائے اورنگ آباد پر مستند اور جامع معلومات فراہم کی ہیں۔
وہ فنِ شعر گوئی اور تاریخ میں یدِ طولیٰ رکھتے تھے۔ وہ حلیم الطبع، منکسرالمزاج اور متواضع مشہور تھے۔ ان کا حافظہ نہایت قوی تھا اور کوئی واقعہ، شعر وغیرہ ایک بار پڑھ لیتے یا کسی کی زبانی سنتے تو ذہن میں رہتا اور سہولت سے دہرا دیتے تھے۔