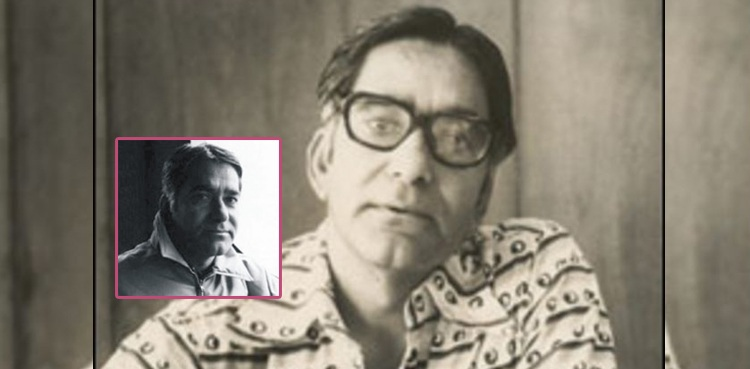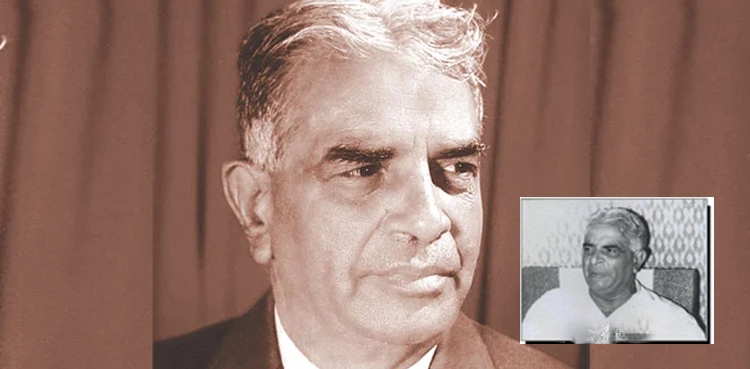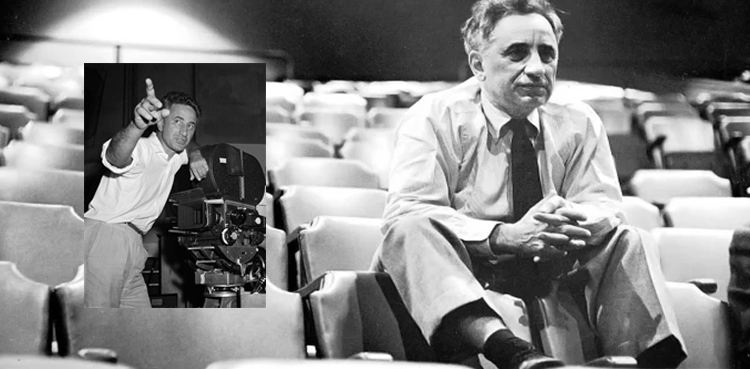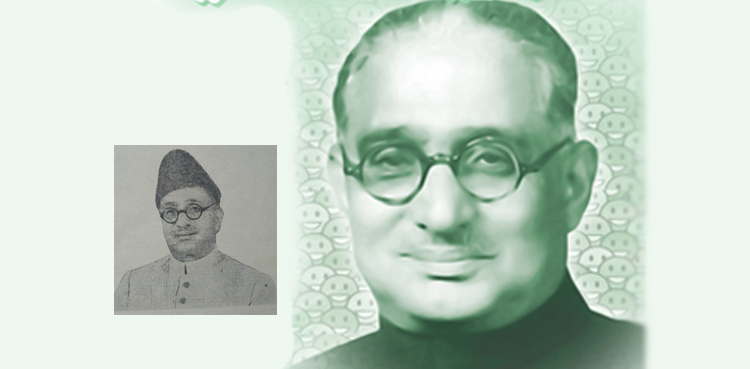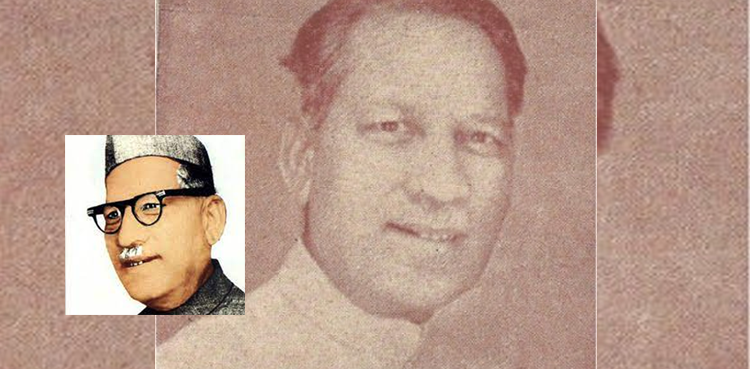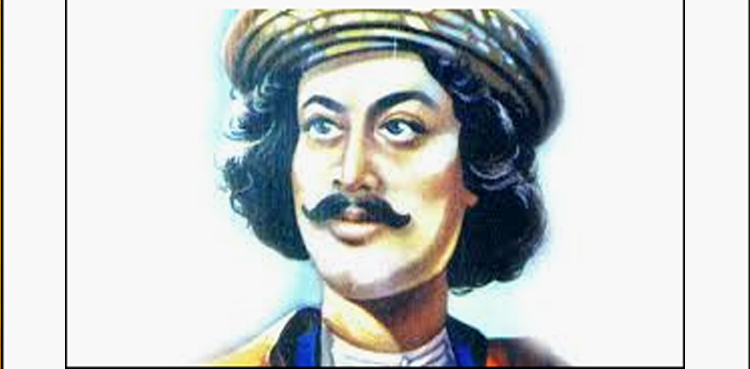پاکستان ٹیلی وژن کے معماروں میں سے ایک کنور آفتاب سنہ 2010ء میں آج ہی کے دن انتقال کرگئے تھے۔ کئی یادگار ڈرامے اور دستاویزی پروگرام کنور آفتاب کا نام اس شعبے کے ایک باکمال اور بہترین فن کار کے طور پر زندہ رکھیں گے۔
پاکستان میں ٹیلی ویژن نشریات کے آغاز کے ساتھ ہی اس شعبے میں قدم رکھنے والے فن کاروں اور قابل و باصلاحیت پروڈیوسروں اور ڈائریکٹروں میں ایک کنور آفتاب بھی تھے جن کی اوّلین سیریل ’نئی منزلیں نئے راستے‘ لاہور میں تیار ہوا، لیکن سینسر کی زد میں آگیا۔ تاہم بعد کے ادوار میں انھوں نے کئی یادگار ڈرامے پی ٹی وی کو دیے۔
کنور آفتاب 28 جولائی 1929ء کو مشرقی پنجاب میں پیدا ہوئے۔ گارڈن کالج راولپنڈی سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد انھوں نے پنجاب یونیورسٹی لا کالج سے ایل ایل بی کی ڈگری حاصل کی۔ والد انھیں وکیل بنانا چاہتے تھے، لیکن کنور آفتاب نے لندن جا کر فلم سازی کی تربیت حاصل کی اور چار برس کے بعد وطن لوٹے تو بطور ڈائریکٹر، پروڈیوسر اپنی پہلی فلم ’جھلک‘ تیّار کی۔ یہ روایتی اور عام ڈگر سے ہٹ کر فلم تھی جو باکس آفس پہ کامیاب نہ ہوسکی۔
اس فلم کی ناکامی کے بعد وہ 1964ء میں ٹیلی وژن سے وابستہ ہوگئے۔ انھوں نے فلم سازی کی تعلیم اور اپنے تجربے سے کام لے کر ٹیلی ویژن کی سرکردہ شخصیات اسلم اظہر، آغا ناصر اور فضل کمال کے ساتھ اردو ڈرامہ کو ہر خاص و عام میں مقبول بنایا۔
معروف صحافی اور براڈ کاسٹر عارف وقار لکھتے ہیں کہ کنور آفتاب زندگی بھر تجرباتی فلموں اور ڈراموں، علامت نگاری اور تجریدی فنون اور ادبی دانش وری کے سخت مخالف رہے۔ ڈرامے سے اُن کا رابطہ شعر و ادب کے حوالے سے نہیں بلکہ بصری فنون کے حوالے سے تھا چنانچہ ایسے مصنفین جو عوام کی سمجھ میں نہ آنے والا ادب تخلیق کرتے تھے، اُن کے نزدیک گردن زدنی تھے۔
عارف وقار مزید لکھتے ہیں، وہ ڈنکے کی چوٹ پر کہا کرتے تھے کہ میں راجپوت ہوں، جو کہتا ہوں کر دکھاتا ہوں۔ پاکستان ٹیلی ویژن کی ملازمت کے دوران پندرہ برس تک اُن کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا، اُن کا سکھایا ہوا پہلا سبق یہی تھا کہ وقت کی پابندی کرو اور دوسروں سے بھی کراؤ۔ اگر ہیرو بھی ریہرسل میں لیٹ آیا ہے تو سب کے سامنے اس کی سرزنش کرو تاکہ دوسروں کے لیے عبرت کا باعث بنے۔ سختی کے اس رویّے نے شروع شروع میں مجھے بہت پریشان کیا اور میں آرٹسٹ برادری میں ناپسندیدہ شخصیت بن کے رہ گیا لیکن کچھ ہی عرصے بعد اس سخت گیر رویّے کے ثمرات نمودار ہونے لگے جب ساری ٹیم نے بر وقت پہنچنا شروع کردیا اور ڈرامے صحیح وقت پر تیار ہوکر سب سے داد وصول کرنے لگے۔ غلام عباس کی کہانی ’ کن رس‘ اپنی سنجیدگی کے لحاظ سے اور امجد اسلام امجد کا ڈرامہ ’یا نصیب کلینک‘ اپنی ظرافت کے سبب کنور آفتاب کی ابتدائی کامیابیوں میں شامل تھے۔ جس طرح لاہور میں انھوں نے نوجوان ڈرامہ نگار امجد اسلام امجد کی تربیت کی اور اسے کامیڈی لکھنے کے گر سکھائے اسی طرح کراچی میں انھوں نے کہانی کار حمید کاشمیری کا ہاتھ تھاما اور ٹیلی پلے کے اسرار و رموز سمجھائے۔ کنور آفتاب کا طرزِ آموزش خالصتاً عملی تھا۔ وہ لیکچر دینے کی بجائے ہر چیز کر کے دکھاتے تھے۔
کنور آفتاب کے مشہور ٹیلی وژن ڈراموں میں نئی منزلیں نئے راستے، زندگی اے زندگی، منٹو راما اور شہ زوری سرِفہرست ہیں۔ انفرادی کاوشوں میں ان کے ڈرامے نجات، یا نصیب کلینک، سونے کی چڑیا، اور نشان حیدر سیریز کا ڈراما کیپٹن سرور شہید قابلِ ذکر ہیں۔
کنور آفتاب احمد نے دستاویزی پروگرام بھی تیار کیے۔ سیالکوٹ کی فٹ بال انڈسٹری پر ان کی بنائی ہوئی فلم کو بین الاقوامی فلمی میلوں میں ایوارڈ دیے گئے۔ انھیں لاہور کے ایک قبرستان میں سپردِ خاک کیا گیا۔