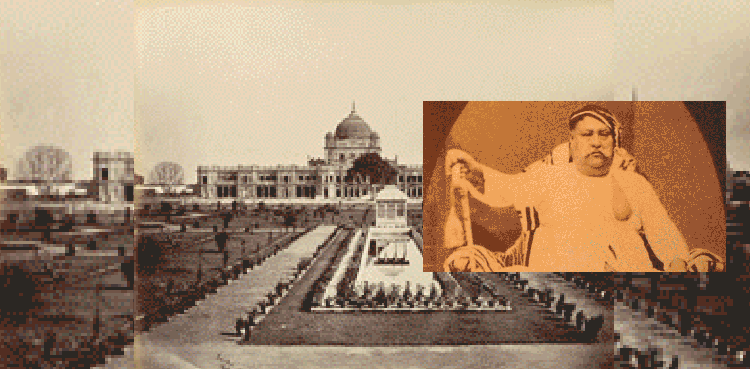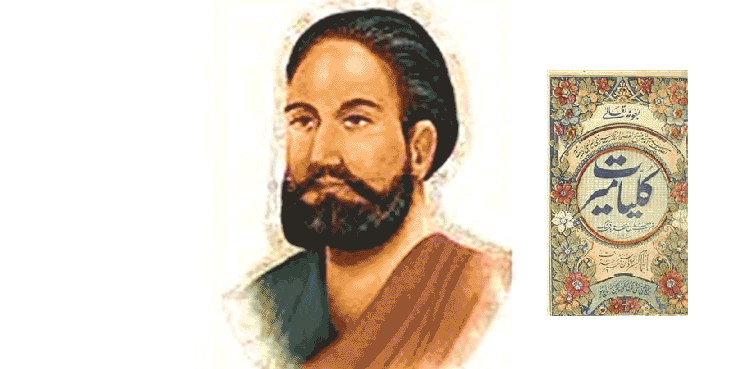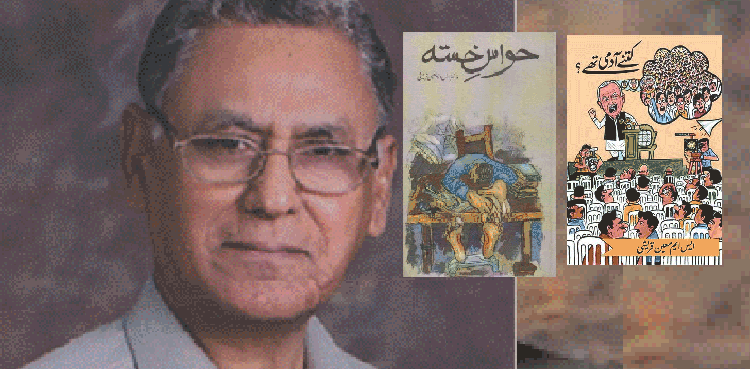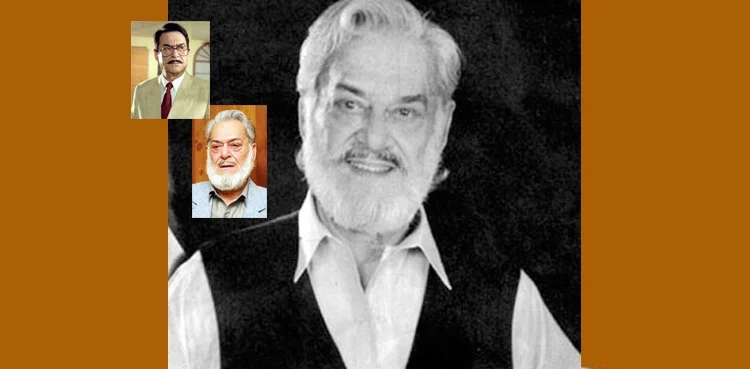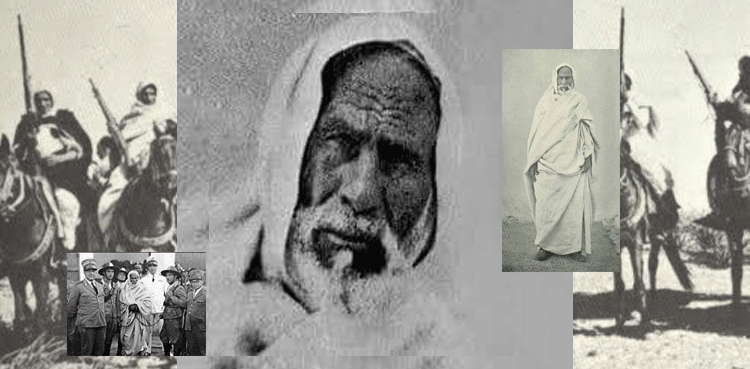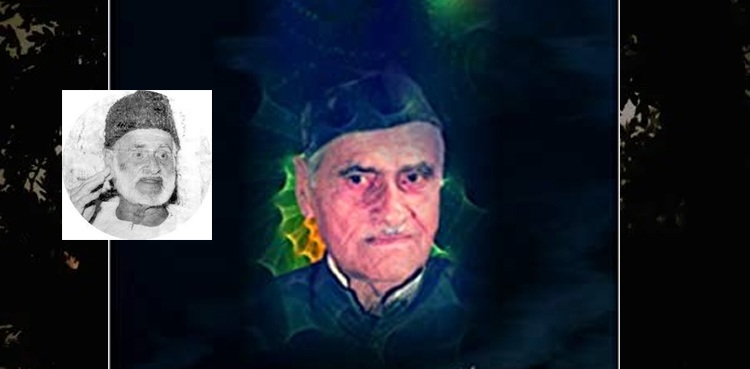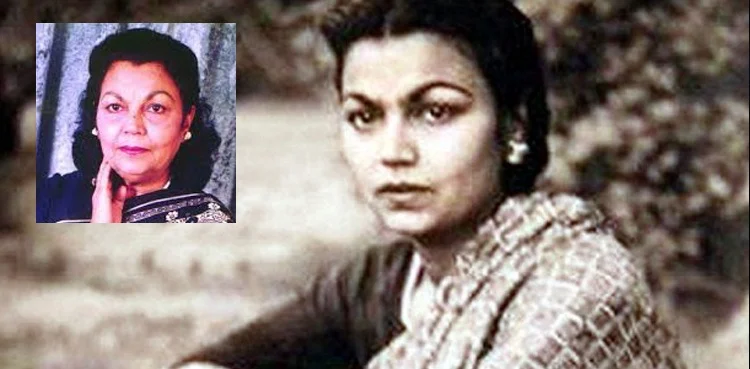سرتاجُ الشّعرا میر تقی میرؔ کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان گنت شعرا نے اُن کی تقلید کی کوشش کی، میرؔ کے لہجے، ان کے انداز میں شعر کہنا چاہا، اُن کی لفظیات کو برتا، مگر میرؔ کا شیوۂ گفتار کہاں نصیب ہو سکا۔
میر تقی میر ایسے شاعر نہ تھے کہ جو اپنے کلام کی وقعت اور اپنی عظمت کا احساس نہیں کرسکتا تھا، سو یہ تعلّی بھی میر کو زیب دیتی ہے:
جانے کا نہیں شور سخن کا مِرے ہرگز
تا حشر جہاں میں مِرا دیوان رہے گا
یہ شعر بھی ملاحظہ فرمائیے:
سارے عالم پر ہوں مَیں چھایا ہوا
مستند ہے میرا فرمایا ہوا
خدائے سخن میر تقی میرؔ نے 1810ء میں آج ہی کے دن وفات پائی اور آج بھی ان کا شہرہ اور اشعار کا چرچا ہورہا ہے۔
میر نے سبھی اصنافِ سخن میں طبع آزمائی کی، لیکن غزل میں ان کی غم انگیز لے اور ان کا شعورِ فن اور ہی مزہ دیتا ہے۔ انھوں نے کہا تھا:
مجھ کو شاعر نہ کہو میرؔ کہ صاحب میں نے
درد و غم کتنے کیے جمع تو دیوان کیا
نام وَر ادیب اور نقّاد رشید احمد صدیقی لکھتے ہیں۔ "آج تک میر سے بے تکلف ہونے کی ہمت کسی میں نہیں ہوئی۔ یہاں تک کہ آج اس پرانی زبان کی بھی نقل کی جا تی ہے جس کے نمونے جہاں تہاں میر کے کلام میں ملتے ہیں لیکن اب متروک ہو چکے ہیں۔ بر بنائے عقیدت کسی کے نقص کی پیروی کی جائے، تو بتایئے، وہ شخص کتنا بڑا ہوگا۔”
میرؔ کے آبا و اجداد کا تعلق حجاز سے تھا۔ وہاں سے نقل مکانی کر کے ہندوستان آئے۔ اس سر زمین پر اوّل اوّل جہاں قدم رکھے، وہ دکن تھا۔ دکن کے بعد احمد آباد، گجرات میں پڑاؤ اختیار کیا۔ میرؔ کے والد کا نام تذکروں میں میر محمد علی لکھا گیا ہے اور وہ علی متّقی مشہور تھے۔ میرؔ کے والد درویش صفت اور قلندرانہ مزاج رکھتے تھے۔
میرؔ نے اکبر آباد (آگرہ) میں 1723ء میں جنم لیا۔ تنگ دستی اور معاشی مشکلات دیکھیں۔ یہ بڑا پُر آشوب دور تھا۔ سلطنتِ مغلیہ زوال کی طرف گام زن تھی۔
قرآن اور بنیادی اسلامی تعلیمات سیکھنے کے بعد اردو اور فارسی پڑھی۔1732ء میں میرؔ کے والد انتقال کر گئے۔ یہ وقت میرؔ کے لیے سخت آزمایش اور ابتلا کا تھا، عمر دس سال سے کچھ زیادہ تھی اور ابھی تعلیم و تربیت کی ابتدائی منازل ہی طے کی تھیں۔ والد کی دو شادیاں تھیں اور سوتیلے بھائی نے تنگ کرنا شروع کردیا۔ ان باتوں کا میر پر گہرا اثر ہوا اور طبیعت میں زود رنجی پیدا ہو گئی۔ تب روزگار کی خاطر بہت دوڑ دھوپ کی، مگر کوئی بات نہ بن سکی۔
1734ء میں میرؔ نے دہلی کے شاہ جہاں آباد کا رُخ کیا اور یہاں والد کے ایک شناسا نواب صمصام الدّولہ کے بھتیجے، خواجہ محمد باسط کے توسط سے صمصام الدّولہ تک پہنچے تو معلوم ہوا کہ وہ بھی ان کے والد کی بہت عزّت کرتے ہیں۔ انھوں نے کہاکہ مرحوم کے مجھ پر بہت احسانات تھے، لہٰذا، مَیں ان کے صاحب زادے (میر تقی میرؔ) کے لیے ایک روپیا یومیہ وظیفہ مقرّر کرتا ہوں۔
یوں میر کو کچھ ذہنی و مالی آسودگی نصیب ہوئی۔ چار، پانچ برس سکون سے گزرئے تھے کہ نادر شاہ نے دہلی پر حملہ کر دیا اور صمصام الدّولہ مارے گئے اور میرؔ کا وظیفہ بھی بند ہو گیا۔
اب دلّی کو عازمِ سفر ہوئے جہاں ان کے رشتے کے ماموں اور مستند شاعر سراج الدّین علی خان آرزو کا طوطی بولتا تھا۔ اس وقت تک میر بھی شاعری کا آغاز کرچکے تھے، لیکن فی الوقت معاش نے تنگ کررکھا تھا، اس لیے زیادہ توجہ حالات بہتر بنانے پر تھی۔ فارسی اور اردو زبان پر دسترس اور اس حوالے سے نہایت فصیح و بلیغ تو تھے ہی، لیکن بعض تذکرہ نویسوں کے مطابق آرزو نے بھی ان سے کوئی اچھا برتاؤ نہ کیا۔ تاہم آرزوؔ کے علاوہ یہاں میرؔ کو جعفر ؔ عظیم آبادی اور سعادتؔ علی امروہوی سے تحصیلِ علم و ادب اور تہذیب برتنے کا موقع ملا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ دراصل سعادتؔ علی امروہوی کی صحبت کا نتیجہ تھا کہ میرؔ نے پورے طور پر شاعری سے رشتہ جوڑا اور گویا شاعری اُن کے لیے اوڑھنا بچھونا قرار پائی۔
یہی وہ زمانہ تھا جب شاعر کے طور پر میر کی شہرت کا آغاز ہوا۔ 1742ء میں بیس سال کی عمر میں میرؔ کی شاعری کا چرچا ہونے لگا۔
صاحبِ طرز ادیب اور انشا پرداز محمد حسین آزاد نے میر کے بارے میں لکھا کہ ’’غرض ہر چند کہ تخلّص اُن کا میرؔ تھا، مگر گنجفۂ سُخن کی بازی میں آفتاب ہو کر چمکے۔ قدر دانی نے ان کے کلام کو جواہر اور موتیوں کی نگاہوں سے دیکھا اور نام کو پُھولوں کی مہک بنا کر اُڑایا۔ ہندوستان میں یہ بات انہی کو نصیب ہوئی ہے کہ مسافر غزلوں کو تحفے کے طور پر شہر سے شہر میں لے جاتے تھے۔‘‘
سخن میں نام ور میر تقی میر نے 1752ء میں ’’نکات الشّعراء‘‘ تحریر کی جس میں اُردو زبان کے شاعروں کے مختصر حالات اور انتخابِ کلام شامل تھا۔ یہ کتاب فارسی میں تحریر کی گئی اور اردو شعرا کے اوّلین تذکروں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔
میرؔ اپنے زمانے کا سب سے تابندہ نام تھا اور انھیں مختلف امرا و نوابین کے دربار میں عزّت و تکریم کے ساتھ انعام و وظائف ملنے لگے تھے۔ میر تقی میر نے شادی کی اور ان کے بیٹے میر فیض علی اور میر حسن عسکری تھے جو شاعر اور بیٹی شمیم کو بھی شاعرہ لکھا گیا ہے جو صاحبِ دیوان تھیں۔
لکھنؤ کی بات کی جائے تو کہتے ہیں میرؔ سے پہلے میرؔ کی شُہرت لکھنؤ پہنچی تھی اور جب وہ اس شہر میں پہنچے تو وہاں مشاعرے کا انعقاد بھی کیا گیا تھا۔ میرؔ کا ظاہری انداز اور اطوار وہاں کی ثقافت سے مختلف تھے جس پر انھیں تمسخر کا سامنا کرنا پڑا، لیکن مشہور ہے کہ جب وہاں میرؔ کا تعارف جاننے کی خواہش کی گئی اور مذاق اڑانے کی مزید کوشش کی گئی تو میر نے فی البدیہہ یوں جواب دیا۔
کیا بود و باش پوچھو ہو پورب کے ساکنو
ہم کو غریب جان کے ہنس ہنس پکار کے
دلّی جو ایک شہر تھا عالم میں انتخاب
رہتے تھے منتخب ہی جہاں روزگار کے
اُس کو فلک نے لوٹ کے برباد کر دیا
ہم رہنے والے ہیں اسی اجڑے دیار کے
یہ سن کر سامعین میرؔ سے معافی کے طلب گار ہوئے اور ان کے کلام کو بھی سراہا۔
میر کی شاعری ذاتی غم و اندوہ کی حدوں سے گذر کر ہمہ گیر انسانی دکھ درد کی داستاں بنی۔ ان کی زندگی کا ابتدائی دور، بیٹی کی ناگہانی وفات اور اپنوں کا برا سلوک یہ سب میر کے کام آیا۔ میر کا غم جو بھی تھا، ان کے لیے فنی تخلیق کا ذریعہ اظہار کا ارفع وسیلہ بنایا۔ میر کے یہاں زندگی کا ایک ولولہ پایا جاتا ہے جس نے میر کی شاعری کو نئی رفعت عطا کی ہے۔
اردو زبان کے اس عظیم شاعر کا مدفن وقت کی گردش اور زمانے کی افتاد میں اپنا نام و نشان کھو چکا ہے۔ کہتے ہیں خدائے سخن کو لکھنؤ میں جہاں سپردِ خاک کیا گیا تھا، وہ موجودہ ریلوے اسٹیشن کے قریب کوئی جگہ تھی اور اس عمارت کی تعمیر کے دوران اس کا نشان باقی نہ رہا۔
میر کے فن کی عظمت کا اعتراف ان کے ہم عصر شعرا نے بھی کیا اور بعد میں آنے والوں نے بھی۔ عظیم شعرا اپنے کلام اور نام ور نقّادوں نے اپنے مضامین میں میر کے بارے میں لکھا اور انھیں بڑا شاعر تسلیم کیا ہے۔ اس ضمن میں مرزا رفیع سودا اور غالب کے اشعار بہت مشہور ہیں۔
کہتے ہیں میر نازک مزاج بھی تھے اور بدخو بھی اور یہ تلخی ان کے حالاتِ زندگی اور افتادِ زمانہ کی وجہ سے تھی۔