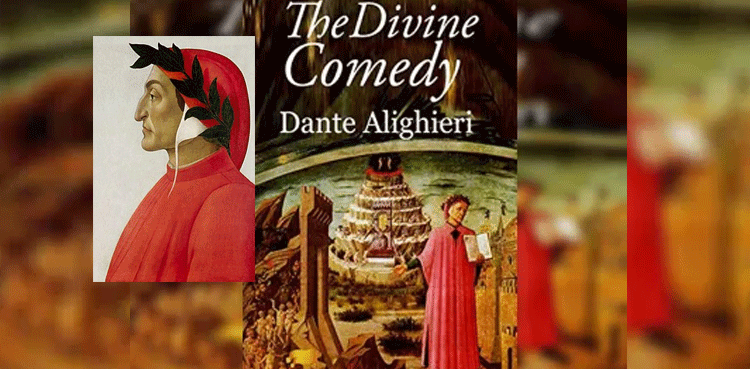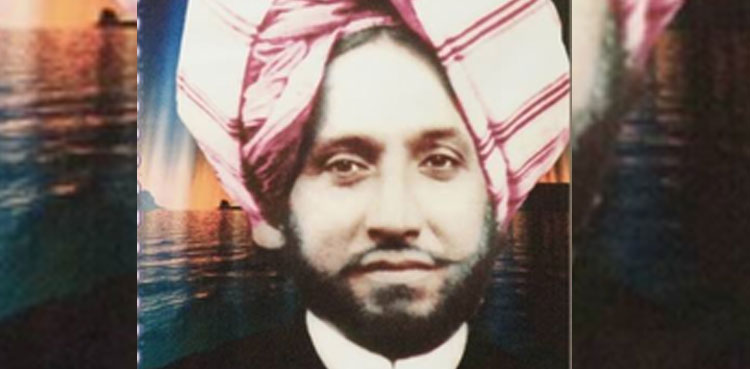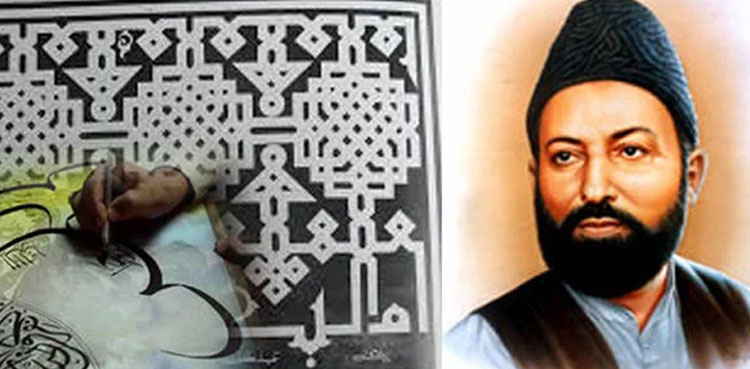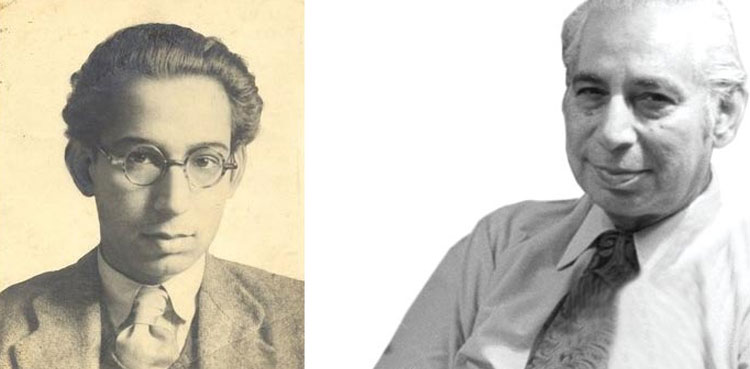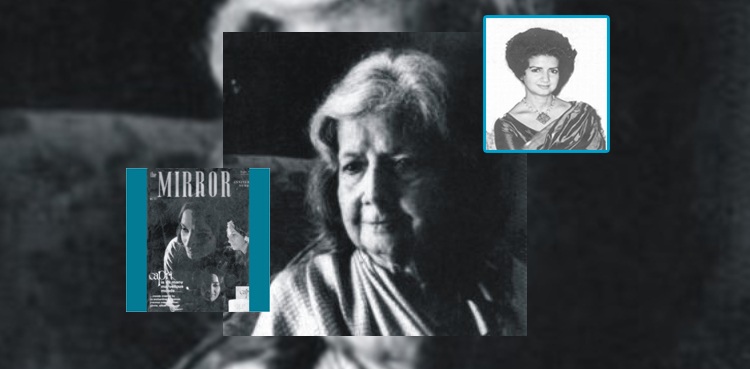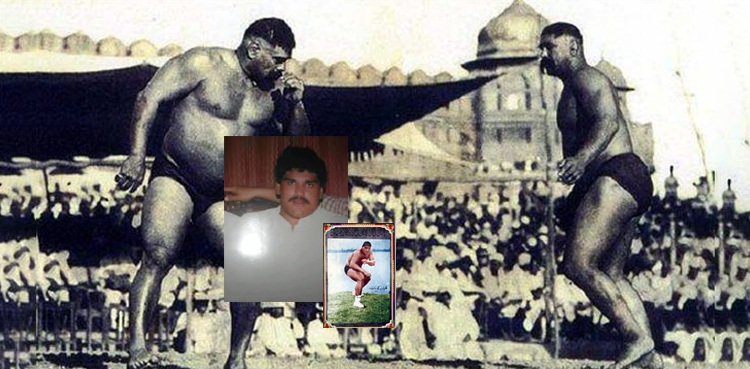میں بے حد پریشان بلکہ شرمندہ تھا۔ شرمندگی کا باعث میرا نصیب تھا کہ مجھے کوئی سیریس بیماری لاحق نہیں ہوتی تھی۔ جب بھی کوئی بیماری آتی وہ نزلہ زکام میں بدل جاتی۔
زیادہ سے زیادہ سر کا درد، پیٹ کا درد یا کوئی پھوڑا ابھرتا اور مجھے جُل دے کر نو دو گیارہ ہو جاتا۔ احباب اور رشتے دار زیرِ ناف قسم کا طعنہ دیا کرتے کہ ان غیر ضروری بیماریوں پر کوئی آپ سےکیا ہمدردی کرے۔ میری بیوی تو کنکھیوں سے کئی بار اشارے بھی کرچکی تھی کہ میں آپ کی خاطر مَر مٹنے کے لیے تیار ہوں لیکن اس مَر مٹنے کی کوئی ٹھوس بنیاد بھی تو پیدا کیجیے۔
اور نہ جانے میرے کس پیارکی دعا قبول ہوئی کہ ایک دن میں صبح کو شیو کرکے اٹھا تو میری ایک لغزشِ پا نے پکارا۔ ’’لینا کہ چلا میں!‘‘
میری بیوی جوشاید اسی نادر لمحے کے انتظار میں ادھیڑ ہوگئی تھی، فوراً ڈاکٹر کو بلا لائی۔ ڈاکٹر نے کہا ’’یہ لغزشِ پا نہیں ہے، سیریس بیماری ہے!‘‘
بیوی کی زبان سے بے ساختہ نکلا۔ ’’ہائے اللہ! یہ سریس بیماری ان کی بجائے مجھے لگ جائے۔‘‘
ڈاکٹر نے رولنگ دیا۔ ’’یہ فیصلہ اسپتال میں جاکر ہوگا کہ بیماری کس جسم کے لیے موزوں ہے، یہ متنازع مسئلہ ہے۔‘‘
اتنے میں میرے بہت سے احباب اور رشتے دار جمع ہوگئے تھے۔ انھو ں نے ڈاکٹر سے ’’ونس مور‘‘ کہا اور باری تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا کہ آخر میں تھرڈ ریٹ بیماریوں کے چنگل سے نکل آیا اور اب راہِ راست پر چل پڑا ہوں۔ ان کی آنکھوں میں مسرت کے آنسو بھر گئے۔ انھوں نے تالیاں بجائیں کئی ایک فرطِ انبساط سے رقص کرنے لگے۔ میری بیوی نے جذبات سے کانپتے لفظوں میں اعلان کیا کہ وہ میرے غسلِ صحت پر یتیموں کو کھانا کھلائے گی۔ اسپتال کے بڑے ڈاکٹر نے سرگوشی میں ایک دوست کو بتایا کہ نروس بریک ڈاؤن کی بیماری ہے۔ ہوسکتاہے، کئی سال لگ جائیں۔
کئی سال؟ مجھے یتیموں کا مستقبل خطرے میں نظر آیا۔
اسپتال کے پیڈ پر لیٹتے ہی مجھے بے حد اطمینان ہوا۔ نہ پریشانی باقی رہی تھی نہ شرمندگی ہی۔ بلکہ فخر سے پھولا نہ سماتا تھا کہ اب اس سیریس بیماری کی بدولت کئی لوگوں کو ابلائیج کرسکوں گا۔ میرے احباب خلوص اور ہمدردی کا فراخ دلانہ استعمال کرسکیں گے۔ رشتے داروں کو ٹھنڈی آہیں بھرنے اور آنسو تھر تھرانے کا موقع نصیب ہوگا۔ میری ایک جنبشِ لب پر وہ اپنی گردنیں کٹوانے کے لیے تیار ہوجائیں گے۔
میری آنکھ کا ایک ہلکا سا اشارہ ان کی زنگ آلود روح کے سبھی بند دروازے کھول دے گا۔ میرے بدن میں ایک چھوٹی سی ٹیس اٹھے گی تو احباب مرغِ بسمل کی طرح اسپتال کے سڑک پر تڑپتے ہوئے نظر آئیں گے۔ میری بیوی ہر پرسانِ حال کے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر کہہ سکے گی،
سرہانے میرؔ کے آہستہ بولو
ابھی ٹک روتے روتے سوگیا ہے
غرض میں اپنے آپ کو بڑا خوش نصیب سمجھتا تھا کہ زندگی میں کسی کے کام تو آیا۔ دوسروں کی خوشنودی کے چند لمحے بھی میسر آجائیں تو وہ سُنبل و ریحاں اور لعل و یاقوت وغیرہ سے کم نہیں ہوتے ورنہ اس سے پہلے تو زندگی جیسے بے برگ و گیاہ ریگستان میں گزر رہی تھی۔ نہ کسی کے آنسو، نہ تبسم، نہ جذبات سے چُور چُور ہونٹ، نہ کسی کی ہمدردی، نہ کسی کا خلوص، نہ کسی کا امتحان، نہ کوئی ممتحن۔
اسپتال میں جاتے ہی سب سے پہلے تو میرے ایک منسٹر دوست نے میرے ریگستان میں ایک پھول کھلا دیا۔ یعنی ایک دوست کے ٹیلیفون پر میڈیکل سپرنٹنڈنٹ سے کہہ دیا کہ اس مریض کو فوراً ایک بیڈ عطا کیا جائے۔ اسپتال میں بیڈ میسر آنے کا مطلب ہوتا ہے جیسے کسی بے روزگار کو اپائنٹمنٹ لیٹر مل جائے۔ میرے ایک پروفیسر دوست نے میری ہوا باندھتے ہوئے کہا ’’جی! بیڈ کیوں نہ ملتا۔ ان کی رسائی تو منسٹروں تک ہے۔‘‘
مجھے منسٹروں کی اس پستی پر رحم کھانا چاہیے تھا لیکن منسٹر کی خوشی مجھے بیڈ میں مل جانے میں مضمر تھی۔ اس لیے میں اس پستی کو شہد کا گھونٹ سمجھ کر پی گیا۔
بیڈ مل جانے کے بعد میں تین چار دن تک یہ دیکھتا رہا کہ احباب اور رشتے دار نہایت سرگرم ہوگئے ہیں۔ چاروں طرف بھاگے بھاگے پھرتے ہیں۔ وہ لمحہ بہ لمحہ اپنی دوڑ دھوپ کی رپورٹ لے آتے اور میرے حلق میں انڈیل دیتے۔ کوئی بتاتا اسپتال کا ہارٹ اسپیشلسٹ میرے کالج کا ساتھی ہے اور مجھ سے میتھمیٹکس کی گائڈ بک لے جایا کرتا تھا۔ کوئی انکشاف کرتا، بلڈ بنک کے انچارج سے میں نے کہہ دیا ہے کہ آپ کی خوش نصیبی ہے۔ آپ کے اسپتال میں ایک عظیم مریض داخل ہوا ہے۔ یہ انچارج میری خالہ کا چوتھا بیٹا ہے۔ اگرچہ خالہ نے اسے جائداد سے عاق کردیا ہے لیکن اس کی لو میرج سے پہلے کے سبھی لو لیٹر میں نے ہی قلم بند کرکے دیے تھے۔
ایک دوست نے تین اخباروں میں میری فوٹو اور بیماری کی خبر بے حد ولولہ انگیز انداز میں شائع کروا کے مسرت حاصل کی جیسے اس نے مجھے مرنے کے بعد جنت کی سیٹ دلوادی ہو۔ چار پانچ دوستوں نے کافی ہاؤس میں ایک ریزولیوشن پاس کروادیا کہ خدانخواستہ اگر فکر تونسوی کی موت واقع ہوگئی تو پورے کافی ہاؤس کے ممبران نہ صرف باجماعت شمشان بھومی تک جائیں گے بلکہ پسماندگان کے لیے چندہ بھی اکٹھا کریں گے۔
یہ جان توڑ سرگرمیاں دیکھ کر مجھے یوں محسوس ہوا جیسے سارا ہندوستان میری بیماری کی خاطر زندہ ہے ورنہ درگور ہوگیا ہوتا! ہر روز کئی ڈاکٹر باری باری آتے اور مجھے لیبارٹری سمجھ کر تجربے شروع کر دیتے۔ جیسے یہ ڈاکٹر نہ ہوں، اسکول کے طالب علم ہوں اور میں ایک کاپی ہوں جس پر وہ ہوم ورک کر رہے ہوں۔ پہلے تو میں سمجھا کہ وہ میرے مرض سے خوش ہونے کی وجہ سے سرگرم ہیں لیکن ایک بار میں نے ان کی خوشی سے بور ہو کر ایک ڈاکٹر سے پوچھا ’’جناب! کیا آپ کو مریض سے محبت ہے یا مرض سے؟‘‘
وہ بولا ’’مرض سے! کیونکہ ہم مریض پر ریسرچ کرکے مرض تک پہنچتے ہیں۔ آپ پر ریسرچ کرنے سے بنی نوع انسان کو بھی فائدہ پہنچے گا۔‘‘
’’اور اگر میں نہ آتا تو بنی نوع انسان کا کیا بنتا؟‘‘
اس کے جواب میں ڈاکٹر نے اپنے اسسٹنٹ کو حکم دیا۔ ’’اس مریض کی بی۔ سی۔جی بھی کرائی جائے۔ دماغ میں توقع سے زیادہ خلل معلوم ہوتا ہے۔‘‘
لیکن میں جانتا تھا کہ میرے دماغ کے خلل کا سبب میری بے پناہ مسرت ہے، جو مریض بن کر مجھے حاصل ہو رہی ہے۔ میں یہ سوچ کر جھوم اٹھا کہ اسپتال میں مجھے بے حد رومانٹک ماحول ملے گا۔ میں نے سن رکھا تھا کہ کئی آرٹسٹ لوگ اسپتال میں جاکر ناول تک لکھتے ہیں اور بیماری کو ادبِ عالیہ میں اضافہ کا باعث بناتے ہیں۔ ان میں سے کئی ایک نرسوں سے پیار بھی کرنے لگتے ہیں بلکہ کئی نرسیں تو نوکری پر لات مار دیتی ہیں اور ناول نگار کی روح کے نرم گوشے میں دلہن بن کر گھس جاتی ہیں۔
دوسرے دن جب میں چھم سے کسی نرس کی آمد کی انتظار میں آنکھیں بند کیے پڑا تھا۔ کسی نے میرا کندھا جھنجھوڑا۔ یہ واقعی نرس تھی (میرے متوقع ناول کی متوقع ہیروئن۔) میں نے آنکھ کھول کر دیکھا نرس خوبصورت نہ تھی، خوبصورت دنیا کے جسم پر ایک چیتھڑا تھی! اس نے پہلے مجھے سونگھا پھر ماحول کو سونگھا اور جیسے اسے احساس ہواکہ ماحول نامکمل ہے۔ اس لیے اس نے میرے بیڈ کے سرہانے ایک مَیلے سے گتے پر میڈیکل چارٹ لٹکا کر ماحول کو مکمل کردیا۔
اور مجھے یوں محسوس ہوا جیسے اس نے میری قبر پر دِیا جلا دیا ہو۔
(طنز و مزاح نگار اور شاعر فکر تونسوی کے قلم سے شگفتہ پارے)