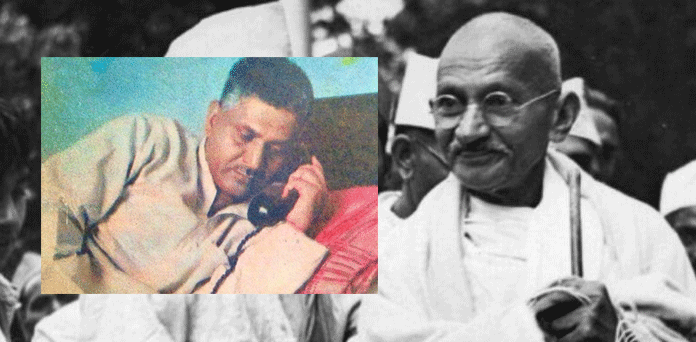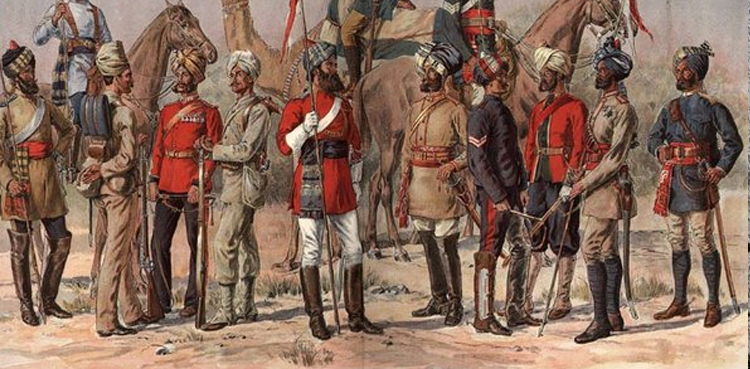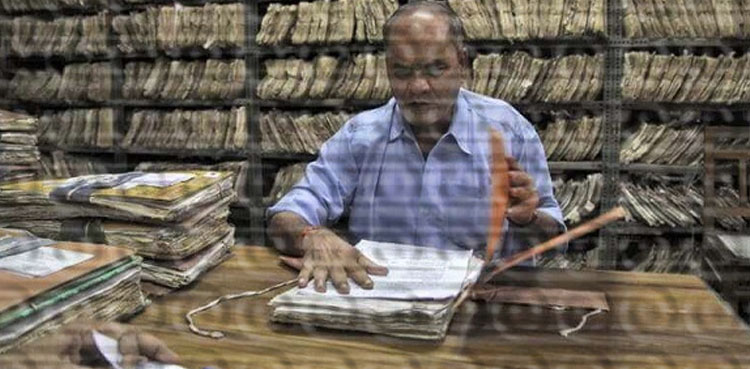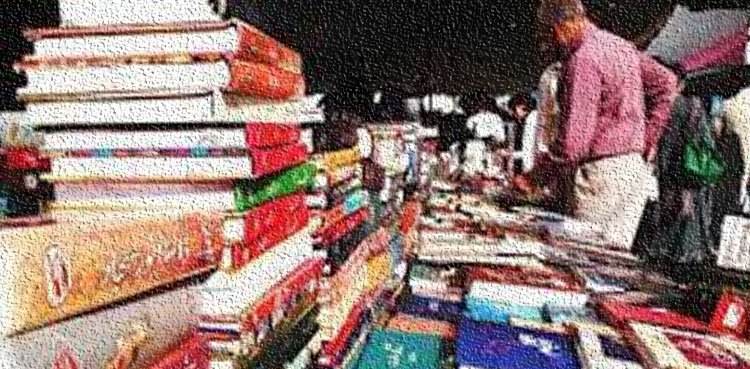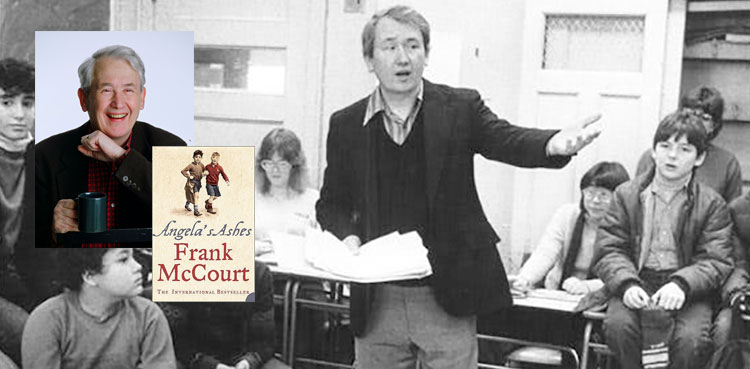مولانا حبیب الرّحمٰن کے بیٹے عزیز الرّحمٰن جامعی نہایت ہوشیار نوجوان تھے، انہیں شوق تھا کہ بڑے بڑے آدمیوں سے ملتے، والد کا ذکر کرتے اور کوئی نہ کوئی خبر اڑا لاتے، ان دنوں زعمائے احرار کی خبروں کا منبع عزیز الرّحمٰن ہی تھے۔ گاندھی، نہرو آزاد وغیرہ کے ہاں تو ان کا آنا جانا روز ہی کا تھا، ان سے ملاقات نہ ہوتی، ان کے سیکرٹریوں سے مل آتے، سیکرٹریوں سے نہ ملتے، تو ان کے سٹینو گرافروں سے مل آتے لیکن خبریں زور کی لاتے اور اکثر خبریں صحیح نکلتی تھیں۔
ایک دن میں نے اور نواب زادہ نصر اللہ خاں نے ان سے کہا کہ گاندھی جی سے ملنے کی راہ نکالو، عزیز نے کہا کہ ’’ابھی چلو، گاندھی جی نے بھنگی کالونی میں کٹیا ڈال رکھی ہے، کوئی نہ کوئی سبیل نکل آئے گی۔‘‘ ہم تیار ہو گئے۔
میں، نواب زادہ، انور صابری اورعزیز الرّحمٰن بھنگی کالونی پہنچے تو گاندھی جی وائسریگل لاج گئے ہوئے تھے۔ ان کی کٹیا ہری جنوں کی بستی کے بیچوں بیچ لیکن کھلے میدان میں تھی۔ کوئی تیس گز ادھر بانس بندھے ہوئے تھے اور یہ کھلا دروازہ تھا۔ یہاں سے قریب ہی ایک خیمہ تھا، جس میں رضاکاروں کا سالار رہتا، ادھر ادھر کچھ چارپائیاں پڑی تھیں۔ کرسیوں کا نشان تک نہ تھا، گاندھی جی کی بیٹھک کا تمام حصہ فرشی تھا، کچھ دیر تو ہم بعض دوسرے مشتاقین کے ساتھ بانس کے دروازے پر کھڑے رہے، پھر عزیز الرّحمن نے ہمت کی اور پیارے لال کو کہلوایا، اس نے بلوایا، پیارے لال گاندھی جی کا سکریٹری تھا، عزیز الرّحمٰن نے اس سے کہا کہ ’’ہم اس غرض سے آئے ہیں۔‘‘ وہ نیم راضی ہوگیا، کہنے لگا ’’آپ سامنے درخت کی چھاؤں میں بیٹھیں، باپو ابھی آتے ہیں، ان کی مصروفیتیوں کا تو آپ کو اندازہ ہے، ممکن ہے کوئی اور وقت دیں۔‘‘
ہم ٹھہر گئے۔ نواب زادہ نصر اللہ خان نے ترکی ٹوپی پہن رکھی تھی۔ میں ان دنوں کھدر پہنتا لیکن سر پر جناح کیپ رکھتا تھا۔ انور صابری نے قلندروں کا جھول پہن رکھا اور عزیز الرّحمٰن مولویوں کے چغہ میں تھا۔ کوئی چالیس منٹ ٹھہرے ہوں گے کہ گاندھی جی کی کار کی آمد کا غل ہوا۔ اتنے میں درجن ڈیڑھ درجن دیویاں بھی آگئیں، گاندھی جی کی کار سڑک سے اندر داخل ہوئی، دیویوں نے پاپوشی کرنی چاہی لیکن گاندھی جی تیر کی طرح نکل کر ہمارے پاس رک گئے۔ ہم نے ہاتھ اٹھا کر آداب کیا، مسکرائے۔
’’آپ لوگ کہاں سے آئے ہیں؟‘‘
’’پنجاب سے۔‘‘
’’آپ نے بہت تکلیف کی؟‘‘۔
’’جی نہیں، ہم آپ کے درشن کرنے آئے ہیں۔‘‘
عزیز الرّحمٰن نے کہا: ’’مہاتما جی! میں مولانا حبیب الرّحمٰن لدھیانوی کا بیٹا ہوں۔‘‘
’’اچھا! وہ مولوی صاحب جو مجھ سے بہت لڑتے ہیں۔‘‘
عزیز الرّحمٰن نے ہم تینوں کا تعارف کرایا، گاندھی جی مسکراتے رہے۔ ملاقات کا وقت مانگا، گاندھی جی نے ہامی بھر لی، کہا: ’’آپ لوگ پرسوں شام پانچ بجے آدھ گھنٹے کے لیے آجائیں۔‘‘
عزیز نے کہا:’’آپ کے سیکریٹری ٹرخا دیتے ہیں، ذرا ان سے بھی کہہ دیں۔‘‘
گاندھی جی نے کہا:’’کوئی بات نہیں، یہ کھڑے ہیں، ان سے میں نے کہہ دیا ہے۔‘‘ مزید کہا: ’’کل بھی میں آپ کو بلا سکتا ہوں لیکن کل میرا مون برت ہے۔ آپ باتیں کریں، تو میں سلیٹ پر لکھ کر جواب دوں گا، کچھ کہنا سننا ہے، تو پرسوں کا وقت ٹھیک رہے گا۔‘‘
ہم نے صاد کیا ، گاندھی جی نے ہاتھ باندھ کر پرنام کیا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتے ہوئے کٹیا میں داخل ہوگئے۔ دوسرے لوگ ہمیں حیرت سے تکتے رہے۔
(1946 میں شورش کاشمیری نے دہلی میں قیام کے دوران کئی قومی لیڈروں اور اہم شخصیات سے ملاقاتیں کی تھیں جن کا ذکر اپنی کتاب بوئے گل نالۂ دل دودِ چراغِ محفل میں کیا ہے، یہ پارہ اسی کتاب سے لیا گیا ہے)