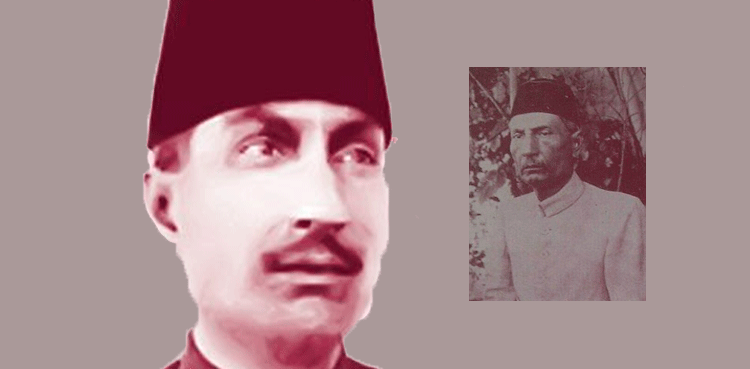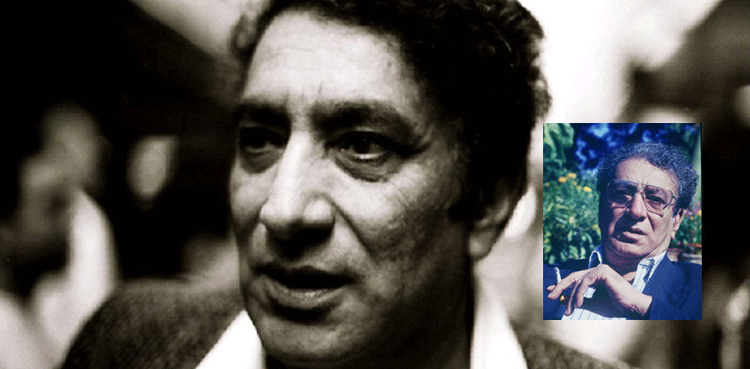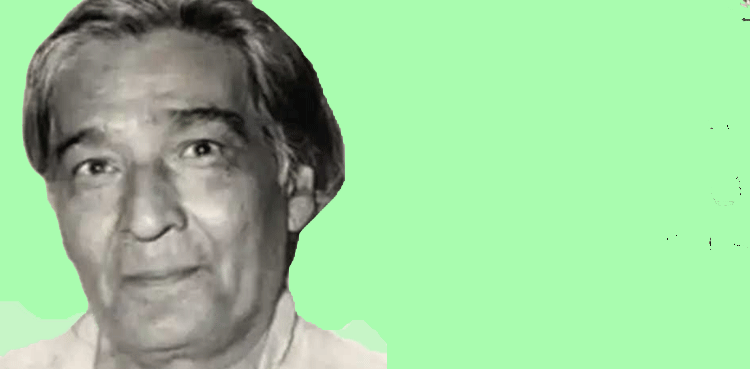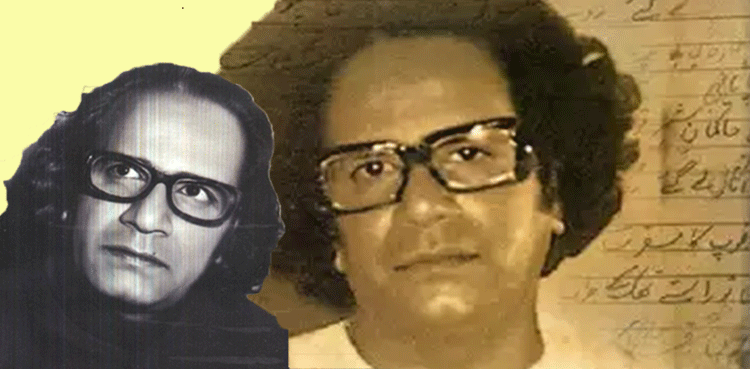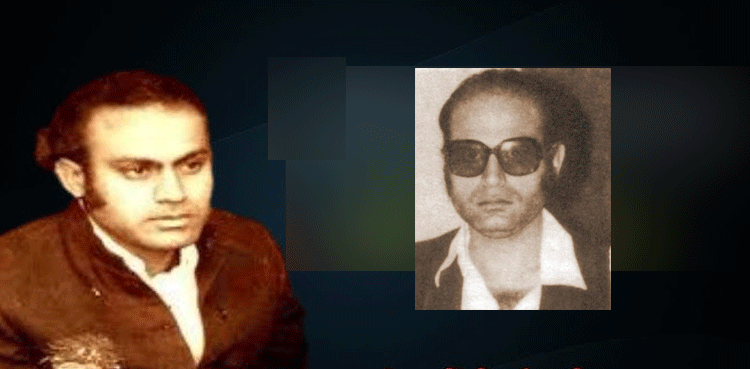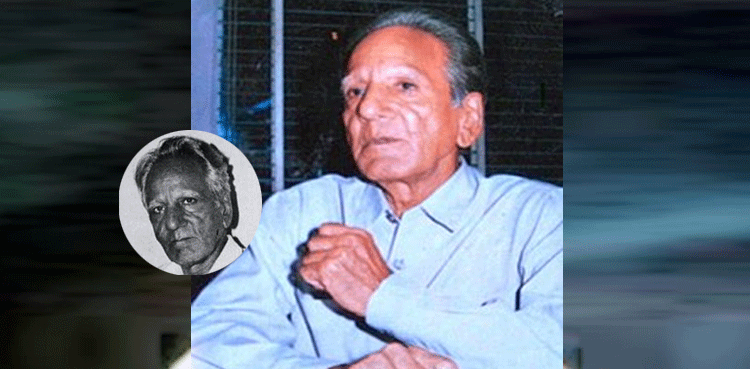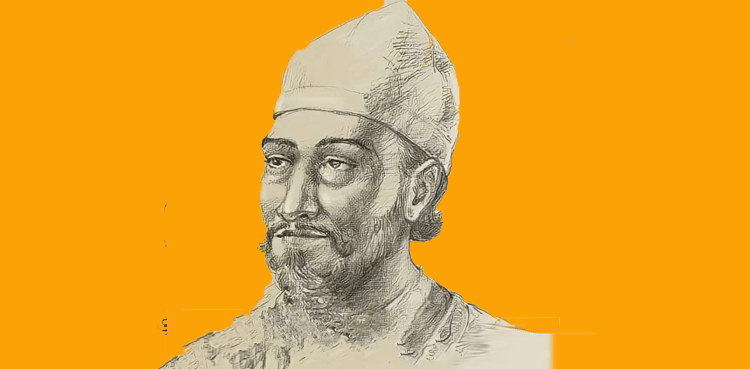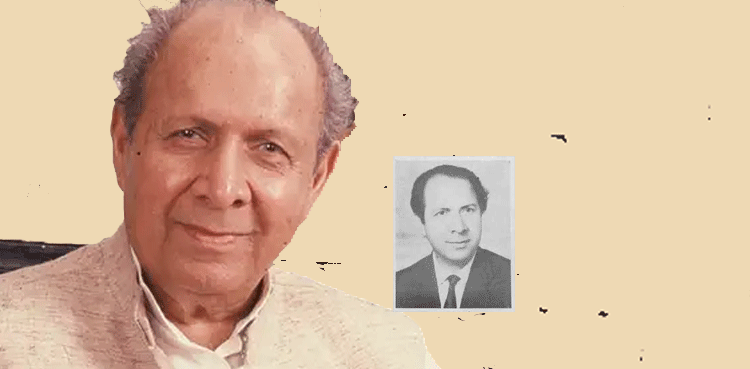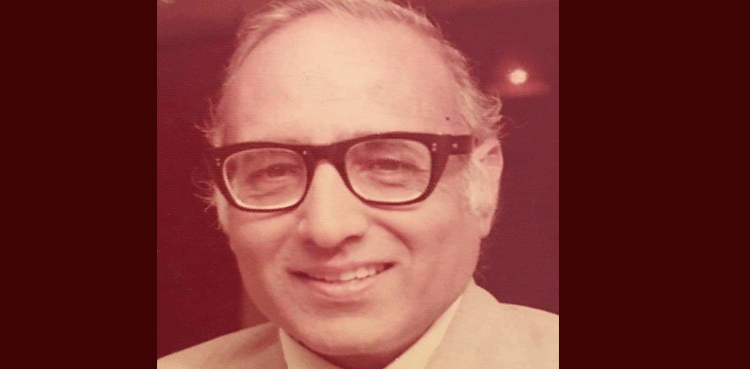کلیم عثمانی مقبول ملّی نغمات کے خالق ہی نہیں ان کے فلمی گیت بھی بہت مشہور ہوئے، مگر بحیثیت غزل گو شاعر بھی انھوں نے اپنی پہچان بنائی۔ بلاشبہ وہ ان شعرا میں سے ہیں جن کا بطور فلمی نغمہ نگار ہی برصغیر میں چرچا نہیں ہوا بلکہ غزل جیسی معتبر صنف سخن میں بھی وہ قتیل شفائی، مجروح سلطان پوری، شکیل بدایونی، سیف الدین سیف، تنویر نقوی اور دوسرے شعرا کی طرح مشہور تھے۔
28 اگست 2000ء کو کلیم عثمانی انتقال کرگئے تھے۔ آج ان کی برسی منائی جارہی ہے۔ کلیم عثمانی کا اصل نام احتشام الٰہی تھا۔ وہ ضلع سہارن پور، دیو بند میں 28 فروری 1928 کو پیدا ہوئے۔ والد فضل الٰہی بیگل بھی شاعر تھے اور اس علمی و ادبی ماحول میں پروان چڑھنے والے احتشام الٰہی نے بھی یہی مشغلہ اپنایا۔ وہ شاعری کے میدان میں کلیم عثمانی کے نام سے پہچانے گئے۔ قیامِ پاکستان کے بعد ان کا خاندان ہجرت کر کے لاہور آگیا تھا جہاں بطور شاعر انھوں نے شہرت پائی۔
کلیم عثمانی نے اپنے وقت کے مشہور شاعر احسان دانش سے اصلاح لی۔ ان کا ترنم بہت مشہور تھا اور لاہور اور پاکستان بھر میں وہ مشاعروں میں ترنم سے اپنا کلام پیش کرکے داد پاتے تھے۔ کلیم عثمانی نے غزل گوئی سے اپنے شعری سفر کا آغاز کیا اور بعد میں فلموں کے لیے گیت لکھنے شروع کیے۔ فلم بڑا آدمی، راز، دھوپ چھاؤں کے لیے ان کے تحریر کردہ گیت بہت مقبول ہوئے اور کلیم عثمانی کو ان کے بعد فلم انڈسٹری میں بہت اہمیت دی جانے لگی۔
1966ء میں کلیم عثمانی نے فلم ہم دونوں اور جلوہ کے گیت تخلیق کیے جس سے ان کی شہرت کو گویا پَر لگ گئے۔ جلوہ وہ فلم تھی جس کے یہ دو گیت انتہائی اعلیٰ درجے کے تھے، کوئی جا کے ان سے کہہ دے ہمیں یوں نہ آزمائیں… اور لاگی رے لاگی لگن یہی دل میں…۔ ایک فلم راز کا مقبول ترین گیت تھا، میٹھی میٹھی بتیوں سے جیا نہ جلا….. کلیم عثمانی نے لکھا تھا۔ 1974ء میں فلم شرافت ریلیز ہوئی جس کے ایک گیت کو لازوال شہرت نصیب ہوئی۔ اس گیت کی موسیقی روبن گھوش نے ترتیب دی تھی اور اس کے بول تھے ’’تیرے بھیگے بدن کی خوشبو سے…. لہریں بھی ہوئیں مستانی سی۔‘‘ اس گیت کی مثال آج بھی دی جاتی ہے اور بلاشبہ یہ وہ گیت ہے جو کلیم عثمانی کو بطور نغمہ نگار ہمیشہ زندہ رکھے گا۔
جوشِ انتقام، ایک مسافر ایک حسینہ، عندلیب اور نازنین جیسی کام یاب فلموں کے نغمات بھی کلیم عثمانی نے لکھے تھے جو بہت مقبول ہوئے۔ ایک زمانہ تھا جب ریڈیو پر فلمی گیت سامعین کی فرمائش پر نشر کیے جاتے تھے۔ ان میں دوسرے شعرا کی طرح کلیم عثمانی کے لکھے ہوئے نغمات بھی شامل ہوتے تھے۔
1973 میں کلیم عثمانی کو فلم گھرانا کے اس مقبولِ عام گیت "تیرا سایہ جہاں بھی ہو سجنا پلکیں بچھا دوں….” پر نگار ایوارڈ سے نوازا گیا تھا۔ یہ گیت آج بھی ہماری سماعتوں میں محفوظ ہے اور جب بھی سنا جائے ایک عجیب لطف دیتا ہے۔ اگر ملّی نغمات کی بات کریں تو پاکستانی قوم کی امنگوں اور وطن کے لیے جذبات کی ترجمانی کرنے والے ان نغمات میں "اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں” اور "یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاسباں اس کے….” سرفہرست ہیں۔ کلیم عثمانی کے یہ ملّی نغمات تاقیامت پاکستان کی فضاؤں میں گونجتے رہیں گے۔
غزل گو شاعر، اور فلمی گیت نگار کلیم عثمانی لاہور کے ایک قبرستان میں آسودۂ خاک ہیں۔ ان کی ایک غزل بہت مشہور ہوئی جس کے چند اشعار ہم یہاں نقل کررہے ہیں۔
غزل
رات پھیلی ہے تیرے سرمئی آنچل کی طرح
چاند نکلا ہے تجھے ڈھونڈنے پاگل کی طرح
خشک پتوں کی طرح لوگ اڑے جاتے ہیں
شہر بھی اب تو نظر آتا ہے جنگل کی طرح
پھر خیالوں میں ترے قرب کی خوشبو جاگی
پھر برسنے لگی آنکھیں مری بادل کی طرح
بے وفاؤں سے وفا کر کے گزاری ہے حیات
میں برستا رہا ویرانوں میں بادل کی طرح