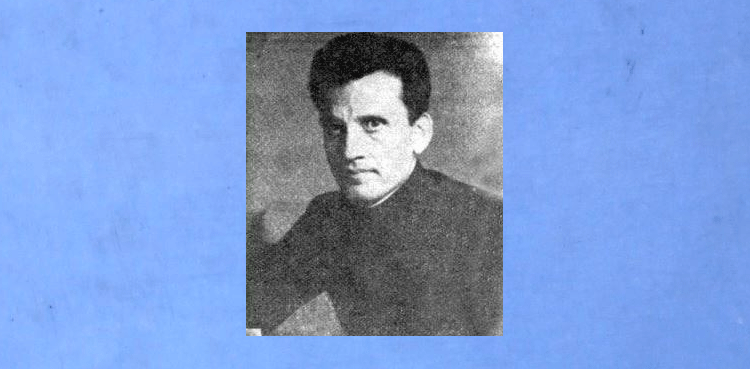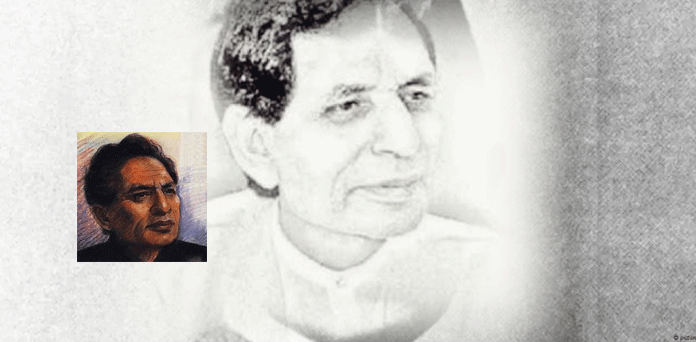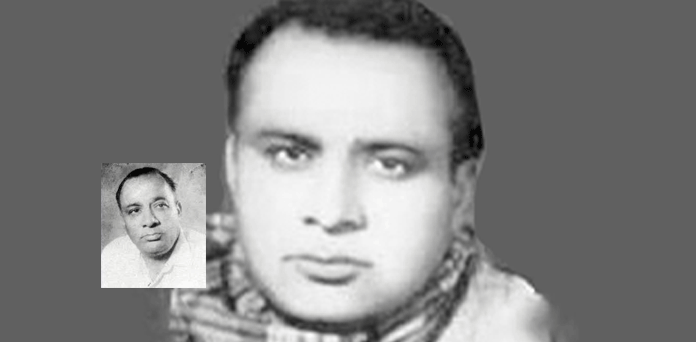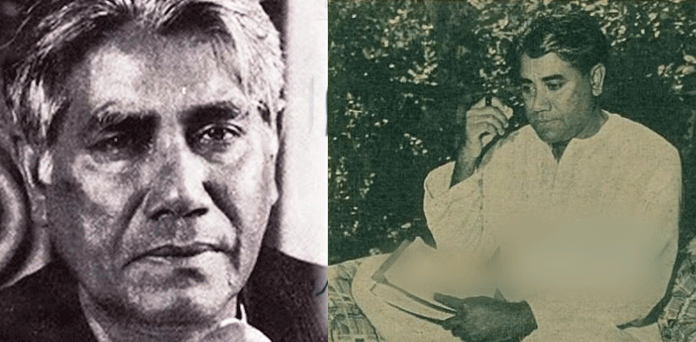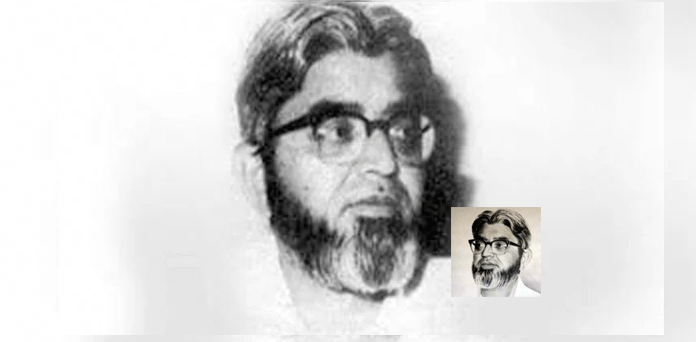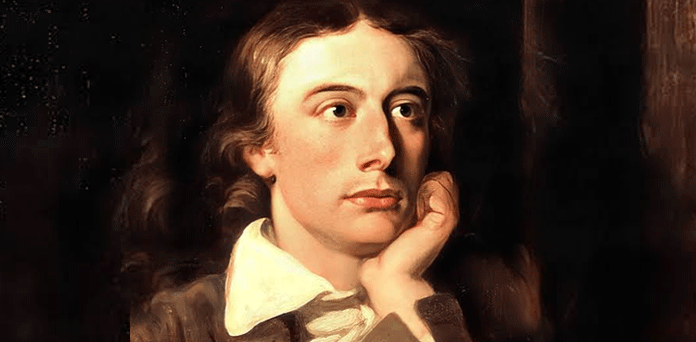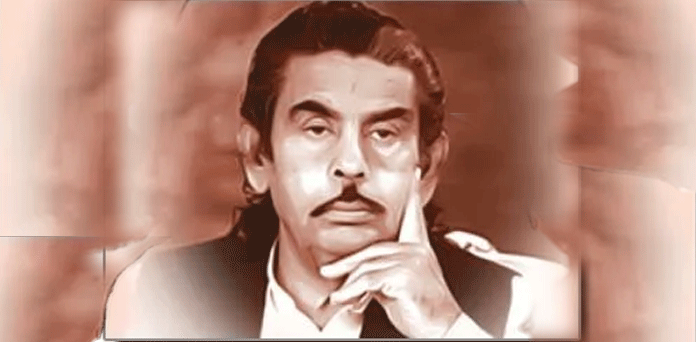ادب کی دنیا میں مختلف نظریات اور دبستان سے وابستہ ہونے والوں نے گروہی سرگرمیوں کے لیے تنظیموں اور اداروں کی بنیاد رکھی جن میں بعض پلیٹ فارم ایسے تھے جن کے ذریعے نہ صرف ادب سرگرمیوں کو فروغ حاصل ہوا بلکہ اس نے نئے لکھنے والوں کی راہنمائی اور تربیت کا بھی کام کیا۔ حلقۂ اربابِ ذوق ایسا ہی ایک پلیٹ فارم تھا جس کی بنیاد رکھنے والوں میں قیوم نظر بھی شامل تھے۔ لیکن پھر ادبی گروہ بندیوں کی وجہ سے قیوم نظر کو تنظیم سے دور ہونا پڑا۔ وہ اردو اور پنجابی زبانوں کے معروف شاعر تھے جنھوں نے ڈرامہ بھی لکھا اور بہترین تراجم بھی کیے۔ اردو غزل گوئی میں قیوم نظر کو ایک نئے مزاج اور آہنگ کا شاعر کہا جاتا ہے۔
قیوم نظر کا یہ تذکرہ ان کی برسی کی مناسبت سے کیا جارہا ہے۔ وہ 23 جون 1989ء کو کراچی میں وفات پاگئے تھے۔
قیوم نظر نے حلقۂ اربابِ ذوق کی بنیاد رکھنے کے بعد اپنے ہم خیال ادیبوں اور شاعروں کے ساتھ مل کر ادبی سرگرمیوں کو فروغ دیا اور اس بینر تلے فعال رہے۔ ان کے ایک رفیق خواجہ محمد ذکریا اپنے اخباری کالم میں لکھتے ہیں، قیوم نظر حلقۂ اربابِ ذوق کے ’بڑوں‘ میں بہت پہلے سے شامل تھے۔ ایک سے زیادہ دفعہ سیکرٹری بھی رہے تھے۔ تقسیم ملک کے بعد حلقے میں کچھ نئے لوگ بھی شامل ہوگئے جن میں انتظار حسین، ناصر کاظمی، شہرت بخاری وغیرہ تھے۔ قیوم نظر کا گروپ پہلے سے موجود تھا۔ دونوں گروپوں میں حلقے پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے کشمکش شروع ہوگئی۔ چند سال قیوم نظر کا گروپ غالب رہا، پھر دوسرا گروپ غالب آگیا۔ حلقے نے بہت اتار چڑھاؤ دیکھے رفتہ رفتہ قیوم نظر اور ان کے گروپ کی اہمیت کم ہوتی گئی پھر قیوم نظر کی زندگی میں پے در پے ایسے حادثات ہوئے کہ وہ مجبوراً ادبی محفلوں سے کنارہ کش ہوگئے۔ پہلا حادثہ یہ ہوا کہ ان کی نظر کمزور ہوگئی۔ ان کے عزیز دوست انجم رومانی نے انھیں اس سلسلے میں بڑے خلوص سے ایک غلط مشورہ دیا۔ انھوں نے کہا کہ آنکھوں کے کسی معالج سے علاج کروانے کی بجائے آپ مجھ سے علاج کرائیں۔ میرے پاس اس کے لیے ایک بہت عمدہ کتاب ہے جس میں آنکھوں کے علاج کے لیے بہت اچھی ’ایکسرسائز‘ بتائی گئی ہیں۔ انھوں نے ایکسرسائز کرائی تو آنکھیں متورم ہوگئیں اور بینائی ایسی خراب ہوئی کہ ایک ایک کے دو دو نظر آنے لگے۔ ماہر آئی سرجنز کے پاس گئے تو انھوں نے کہا کہ اب علاج ممکن نہیں۔ وفات تک بینائی کی یہی کیفیت رہی۔
اس دوران پہلے ان کے بڑے بیٹے کا لندن میں انتقال ہوگیا جو کئی سال پہلے وہاں کا شہری بن چکا تھا۔ اس حادثے کو تو وہ برداشت کرگئے۔ اس کے دو تین برس بعد ان کے چھوٹے بیٹے سلمان بٹ کا ایک حادثے میں انتقال ہوگیا۔ اس حادثے نے قیوم نظر کو بالکل دل شکستہ کردیا۔ وہ لاہور سے بھی بیزار ہوگئے۔ وہ اپنی ایک بیٹی کے پاس کراچی میں رہنے لگے اور وہیں 23 جون 1989ء کو وفات پائی۔ اگلے دن تدفین ان کی وصیت کے مطابق لاہور میں ہوئی۔
قیوم نظر لاہور میں 7 مارچ 1914ء کو پیدا ہوئے تھے۔ ان کا اصل نام عبدالقیوم تھا۔ وہ 1944ء سے 1955ء تک حلقہ اربابِ ذوق کے سیکرٹری رہے۔ قیوم نظر نے اردو غزل کو ایک نیا مزاج، نیا آہنگ عطا کیا۔ وہ میر تقی میر اور فانی بدایونی سے متأثر تھے۔ تاہم روایتی بندشوں کے ساتھ ان کی شاعری میں فطرت کے تجربات اچھوتے اور تازہ ہیں۔ ان کی تصانیف میں "پون جھکولے”، "قندیل”، "سویدا”، "اردو نثر انیسویں صدی میں”، "زندہ ہے لاہور "اور "امانت ” شامل ہیں۔ انھوں نے بچّوں کے لیے ایک کتاب "بلبل کا بچہ ” بھی لکھی۔
اردو ادب کی خدمت کرنے والے قیوم نظر نے پنجابی زبان میں بھی قابل ذکر کام کیا۔ میرا جی سے ان کی بے تکلفی تھی۔ وہ ادب میں نئے نئے تجربات کے امکانات پر غور کرتے تھے، تبادلۂ خیال کرتے تھے اور پھر اپنے اپنے انداز میں معاصر شاعری میں جدّت پیدا کرنے کے لیے لکھنے میں مشغول ہوجاتے تھے۔ ان کے دوسرے ساتھیوں میں مختار صدیقی، یوسف ظفر، حفیظ ہوشیار پوری، ضیاء جالندھری وغیرہ تھے۔
قیوم نظر نے بی اے کیا اور اے جی آفس میں کلرک بن گئے۔ پاکستان بنا تو ایم اے اردو کیا اور پھر کئی سال محکمۂ تعلیم سے وابستہ رہے، پھر ٹیکسٹ بک بورڈ میں ماہرِ مضمون کی حیثیت سے کام کیا، اس کے بعد پاکستان نیشنل سینٹر لاہور کے ڈائریکٹر بن گئے۔ آخر میں پنجاب یونیورسٹی کے شعبۂ پنجابی میں صدرِ شعبہ کی حیثیت سے کام کیا۔ یعنی معمولی ملازمتوں سے گز رکر رفتہ رفتہ اعلیٰ عہدوں تک پہنچے۔ ان مصروفیات کے ساتھ ساتھ ادب و شعر سے ہمیشہ تعلق برقرار رکھا۔ ان کی اولین اور اہم تر حیثیت تو شاعر کی تھی لیکن نثر سے بھی دامن کشاں نہیں رہے۔ تنقید لکھی، خاکہ نگاری کی طرف بھی التفات کیا اور ڈرامے بھی لکھے۔ کئی کتابیں مرتب کیں جن میں ان کی نصابی کتابیں میرے نزدیک بہت اہم ہیں۔ نصابی کتابوں کو ترتیب دینے میں وہ اپنے رفقاء سے بہت بہتر تھے۔
شاعری میں جدید انداز کے اچھے شاعر تھے۔ موضوعات کی جدت کے ساتھ ہیئت کے تجربات کرتے رہتے تھے۔ قیوم نظر نے عمر کے آخری ایک دو برسوں میں اپنی کلیات شاعری ’قلب و نظر کے سلسلے‘ کے نام سے ترتیب دی۔ وہ جدید نظمیں تو لکھتے ہی تھے مگر اپنے بعض معاصرین کے برخلاف غزلیں بھی برابر کہتے رہے۔ اس کے علاوہ انھوں نے بچوں کے لیے شاہکار نظمیں تخلیق کیں جن کے کئی مجموعے چھپ چکے ہیں۔ کسی زمانے میں پوری پوری کلاس کو یہ نظمیں یاد ہوتی تھیں جن میں خصوصاً ’بلبل کا بچہ‘ ایسی پُرتاثیر تھی کہ بچوں کے دلوں میں عمر بھر کے لیے بس جاتی تھی۔ قیوم نظر کے گیت ، ترانے اور نعتیں بھی ان کی شاعری کے تنوع کا اچھا اظہار ہیں۔
وہ لاہور اور امرتسر دونوں شہروں میں جوان ہوئے اس لیے پنجابی تو ان کی اپنی زبان تھی لیکن زندگی بھر اردو اوڑھنا بچھونا رہی۔ اردو تحریر و تقریر میں اظہار پر یکساں قدرت رکھتے تھے لیکن شاید کم لوگوں کو معلوم ہوگا کہ ان کی انگریزی بھی بہت اچھی تھی۔ بہت سے جدید امریکی اور برطانوی شعراء کی نظموں کے ترجمے کرتے رہتے تھے۔
مجموعی طور پر بڑے ہنس مکھ، دوستوں کے دوست اور دشمنوں کے دشمن تھے۔ انھوں نے بذلہ سنجی سے بہت سے لوگوں کو دشمن بھی بنایا لیکن بہت سے لوگ ان کے محب بھی تھے۔ اگر آخری زندگی میں دل کو پاش پاش کرنے والے صدموں سے دوچار نہ ہوتے تو کہا جاسکتا کہ انھوں نے اچھی زندگی گزاری۔ ان کے مزاج میں اگر لوگوں کو فقرہ بازی سے ناراض کرنے کی عادت نہ ہوتی تو اور زیادہ کامیاب زندگی بسر کرتے مگر انسان کا جو مزاج بن گیا سو بن گیا۔
یہاں ہم قیوم نظر کے انٹرویو سے چند اقتباسات بھی نقل کرتے ہیں جس سے قیوم نظر کی زبانی انھیں جاننے کا موقع ملے گا، وہ بتاتے ہیں، ’’خود میرا یہ حال تھا کہ میرے والد خواجہ رحیم بخش سرکاری ملازم تھے۔ ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ چار بھائیوں اور دو بہنوں کا بوجھ بہ حیثیت بڑے بھائی مجھ پر آپڑا تھا۔ میں نے ٹیوشن اور ملازمت کے ساتھ ساتھ اپنی تعلیم مکمل کی تھی اور اورینٹل کالج لاہور سے اردو میں ایم اے کرنے کے بعد اکاؤنٹنٹ جنرل آفس میں لگا ہوا تھا۔ میں اے جی آفس کی نوکری سے سخت اکتا گیا تھا لیکن اس سے گلو خلاصی بھی ممکن نہ تھی۔ میں سخت پریشان تھا۔ اتفاق سے یونیورسٹی کے مشاعرے میں میری ملاقات گورنر پنجاب عبدالرب نشتر سے ہوگئی۔ اے جی آفس سے میری ناخوشی کا سن کر انہوں نے اپنی ذاتی کوشش سے میرا تبادلہ محکمۂ تعلیم میں کروا دیا۔‘‘
’’1956ء میں مجھے یونیسکو کا کریٹیو رائٹر کا فیلو شپ ملا اور اس طرح مجھے فرانس، اٹلی، اسپین، ہالینڈ، سوئٹزر لینڈ، روم وغیرہ گھومنے اور وہاں کے تخلیقی فن کاروں سے ملاقات کا موقع ملا۔‘‘
’’شاعری کی ابتدا میں نے کالج ہی کے زمانے سے کر دی تھی۔ میں نے ایک دن اپنے استاد شمسُ العلما تاجور نجیب آبادی صاحب سے پوچھا کہ میں کیا تخلّص رکھوں؟ بولے ’’میں اپنے شاگردوں میں اب مزید کسی باغی کا اضافہ کرنا نہیں چاہتا۔ ن م راشد، اختر شیرانی، کنور مہندر سنگھ اور دیگر کئی نامور شعرا ان کی شاگردی میں رہ چکے تھے۔) میں نے وعدہ کیا کہ میں بغاوت نہیں کروں گا اس پر مشورہ دیا کہ ’’نظر تخلّص کر لو۔‘‘