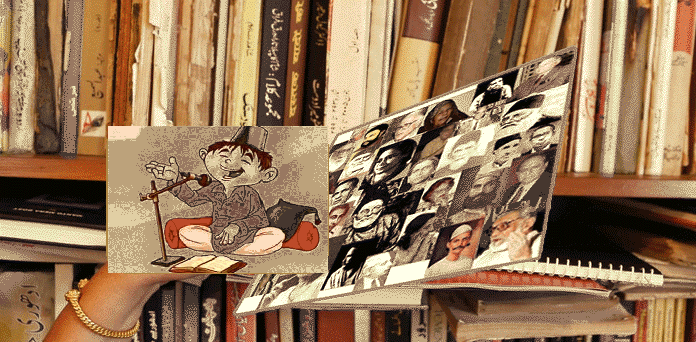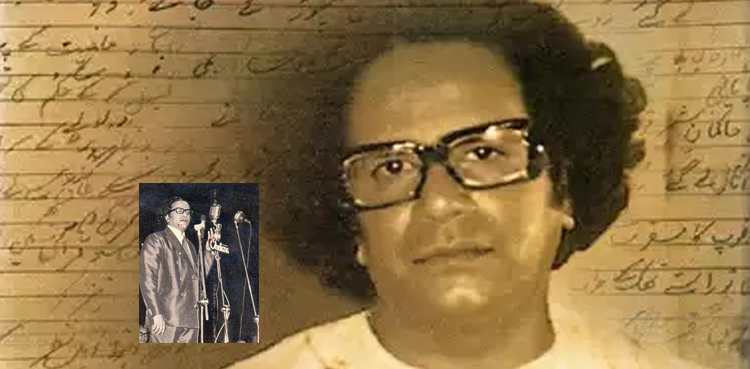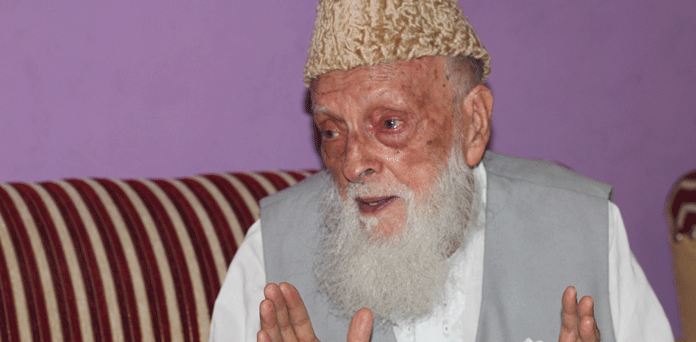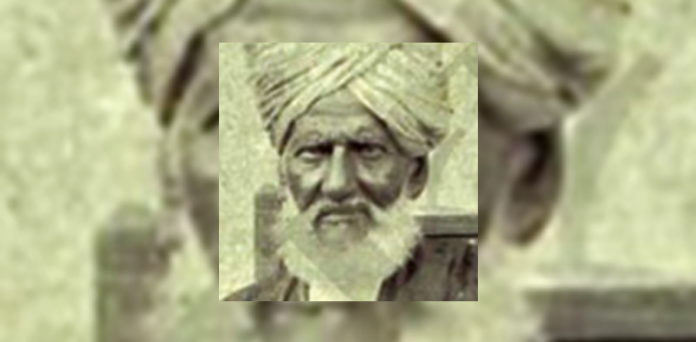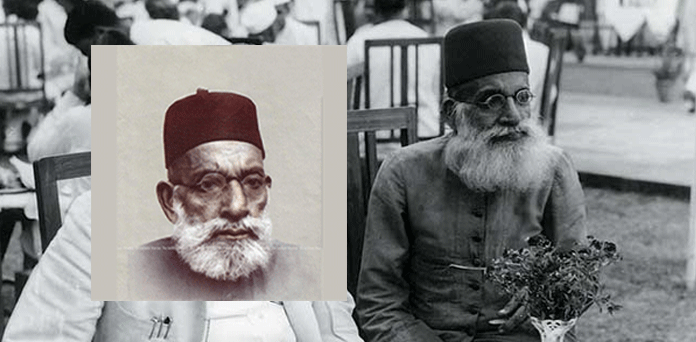ترقی پسند ادب کے زمانے میں جب نظم کے مقابلے میں صنفِ غزل کو کمتر خیال کیا جارہا تھا اور اس کے خلاف مہم بھی شروع کردی گئی تھی، تب مجروح سلطان پوری نے غزل لکھی اور اس کی آبرو کو سلامت رکھا۔ آج عمدہ غزل گو اور فلمی گیت نگار مجروح سلطان پوری کی برسی ہے۔
برصغیر پاک و ہند میں جن شعراء کو بطور نغمہ نگار زیادہ شہرت اور پذیرائی ملی، مجروح سلطان پوری ان میں سے ایک ہیں۔ وہ بھارت کے متوطن تھے اور غزل کے ساتھ انھوں نے نظم اور گیت نگاری میں بڑا نام پایا۔ مجروح سلطان پوری کی غزلیں اور نظمیں زباں زدِ عام ہوئیں جب کہ فلمی نغمات نے مجروح کو لازوال شہرت سے ہمکنار کیا۔ مجروح سلطان پوری 50 اور 60 کی دہائی میں بھارتی فلمی صنعت میں بحیثیت نغمہ نگار چھائے رہے اور کوئی ان کی جگہ نہیں لے سکا۔
رفعت سروش کو مجروح کی رفاقت نصیب ہوئی تھی جو ان کی وفات پر اپنے ایک مضمون میں لکھتے ہیں:” ذہن ماضی کے نہاں خانوں میں جاتا ہے، اور مجھے یاد آرہے ہیں بہت سے ایسے لمحے جو مجروح کی ہم نفسی اور رفاقت میں گزرے۔ اوائل 1945ء کی کوئی شام۔ اردو بازار (دہلی) مولانا سمیع اللہ کے کتب خانہ عزیزیہ کے باہر رکھی ہوئی لکڑی کی وہ بنچیں جن پر ہندوستان کے سیکڑوں علماء، شعراء، دانشور، فقیر اور تو نگر بیٹھے ہوں گے۔ میں اپنی قیام گاہ واقع گلی خان خاناں اردو بازار سے نکلا اور حسبِ معمول ٹہلتا ٹہلتا کتب خانہ عزیزیہ پہنچا۔ یہاں مولانا کی باغ و بہار شخصیت ہر شخص کا استقبال کرتی تھی۔ ایک بنچ پر ایک خوش شکل اور خوش لباس، شیروانی میں ملبوس نوجوان کو بیٹھے دیکھا۔ مولانا نے تعارف کرایا یہ ہیں مجروح سلطان پوری۔
اس زمانے کے ابھرتے ہوئے اور مترنم غزل گو شعرا کو جگر مراد آبادی کی سرپرستی حاصل تھی۔ چاہے شکیل ہوں، راز مراد آبادی ہوں یا خمار بارہ بنکوی اور مجروح سلطانپوری۔ یا بعد میں شمیم جے پوری۔ جگر صاحب اپنے ساتھ نوجوان شعراء کو لے جاتے تھے اور انھیں نمایاں ہونے کا موقع مل جاتا تھا۔ مجروح کی بمبئی میں آمد کے سلسلے میں سید سجاد ظہیر ( بنے بھائی) نے اپنی خود نوشت روشنائی میں لکھا ہے کہ مجروح سلطان پوری جگر صاحب کے ساتھ لگے لگے بمبئی آئے، ترقی پسندوں سے ملے اور پھر ترقی پسند مصنّفین کے لیڈروں میں شامل ہوگئے۔
مجروح نے کئی ماہ کی جیل کاٹی۔ اس زمانے میں ان کی پریشانیاں بہت بڑھ گئی تھیں۔ یہاں تک ہوا کہ انھوں نے اپنی بیگم کو بطور امداد کچھ روپے بھیجنے کے لیے اپنے کچھ دوستوں کے ناموں کی لسٹ بھیجی جس میں راقم الحروف کا نام بھی شامل تھا۔ ایک دو ماہ بعد راجندر سنگھ بیدی نے مجروح کی مدد کی اور جب تک وہ جیل میں رہے ان کے اخراجات اپنے ذمے لے لیے۔ غرض مجروح سلطان پوری آہستہ آہستہ انجمن ترقی پسند مصنّفین سے عملی طور پر دور ہوتے چلے گئے۔ اور خود انجمن بھی کم فعال رہ گئی تھی۔”
1919ء میں نظام آباد ضلع سلطان پور میں پیدا ہونے والے مجروح کا اصل نام اسرار حسین خان تھا۔ ان کے والد محکمۂ پولیس میں ملازم تھے۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد مجروح نے حکمت کا پیشہ اختیار کیا اور ساتھ ساتھ شاعری بھی کرتے رہے۔ بعد میں انھوں نے حکمت کو خیرباد کہہ کر شاعری پر توجہ دی
خلیق انجم نے مجروح کے شخصی خاکے میں ایک جگہ لکھا ہے: مجروح بہت ذہین طالب علم تھے اور طالبِ علمی ہی کے زمانے میں طبّ پر انہوں نے ایسی قدرت حاصل کر لی تھی کہ جھوائی ٹولے کے بڑے طبیب حکیم عبدالمعید جب کسی علاج کے سلسلے میں باہر تشریف لے جاتے تو مجروح کو اپنی کرسی پر بٹھا کر جاتے۔ 1938ء میں کالج سے سند حاصل کرنے کے بعد مجروح فیض آباد کے قصبہ ٹانڈہ چلے گئے اور وہاں انہوں نے اپنا مطب قائم کر لیا۔ مجروح نے خود مجھے مسکراتے ہوئے بتایا تھا کہ ٹانڈہ میں ایک بہت خوب صورت لڑکی سے ان کو عشق ہو گیا تھا۔ جس کا بعض لوگوں کو علم ہو گیا۔ اس لیے لڑکی کی رسوائی کے ڈر سے وہ مانڈہ چھوڑ کر سلطان پور آ گئے۔ ایک گفتگو کے دوران مجروح نے دماغ پر زور دے کر بتایا تھا کہ انہوں نے 1935ء یا 1936ء میں شاعری شروع کی تھی۔”
بعد میں مجروح جگر مراد آبادی کے توسط سے مشہور ہدایت کار اے آر کاردار سے ملے اور اے آر کاردار نے ان سے فلمی گیت لکھنے کو کہا۔ لیکن اس وقت مجروح نے انکار کر دیا۔ وہ اسے معیاری اور ارفع کام نہیں سمجھتے تھے۔ جگر مراد آبادی نے انھیں سمجھایا اور پھر کاردار کے ساتھ مجروح موسیقار نوشاد کے پاس پہنچے جنھوں نے اس نوجوان شاعر کا ٹیسٹ لیا۔ مشہور ہے کہ نوشاد نے شاعر مجروح کو ایک طرز دی اور کہا کہ وہ اس پر کچھ لکھ دیں۔ مجروح نے ’جب اس نے گیسو بکھیرے، بادل آیا جھوم کے‘‘لکھ کر دیا جس کے بعد انھیں فلم ’’شاہ جہاں‘‘ کے نغمات لکھنے کے لیے کہا گیا۔ مجروح موسیقی کا بھی شوق رکھتے تھے اور سیکھنا چاہتے تھے لیکن والد کو یہ ناپسند تھا اور اس لیے ان کا یہ شوق پورا نہ ہوسکا۔
فلم شاہ جہاں 1946ء میں ریلیز ہوئی اور اس فلم کے نغمات نے ہر طرف دھوم مچا دی۔ اس فلم کے ایک گیت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب گلوکار کے ایل سہگل نے یہ گیت ’جب دل ہی ٹوٹ گیا، اب جی کر کیا کریں گے‘ سنا تو کہا کہ میری ارتھی اٹھانے کے موقع پر اس گیت کو گایا جائے۔ شاہ جہاں کے بعد مجروح کو فلم ’’مہندی، انداز، اور آرزو‘‘ ملی اور ان کے تحریر کردہ گیتوں نے مقبولیت حاصل کی۔ ان کام یابیوں کے بعد فلم نگری میں مجروح سلطان پوری کی خوب شہرت ہوئی۔
مجروح ان شعرا میں سے تھے جو بائیں بازو کے نظریات رکھتے تھے۔ وہ انجمن ترقی پسند مصنفین کے سرگرم رکن بھی بن گئے تھے۔ 1949ء میں مجروح کو حکومت کے خلاف نظمیں لکھنے پر گرفتار کر لیا گیا۔ ان کے ساتھ مشہور اداکار بلراج ساہنی کو بھی جیل بھیج دیا گیا۔مجروح سے کہا گیا کہ وہ معافی مانگیں۔ لیکن انکار پر مجروح کو دو سال قید کی سزا سنا دی گئی۔ اس دوران ان کے کنبے نے شدید مالی مشکلات کا سامنا کیا۔
فلم ساز اور ہدایت کار ناصر حسین کی فلموں کے لیے مجروح کے لکھے ہوئے نغمات کی مقبولیت آج بھی برقرار ہے۔ مجروح کا 60 سالہ فلمی کیریئر ان کی شہرت کے ساتھ کئی ایوارڈ اور فلمی دنیا میں زبردست پذیرائی سے بھرا ہوا ہے۔ 1965ء میں فلم ’دوستی‘ کا نغمہ ’’چاہوں گا میں تجھے سانجھ سویرے‘‘ لکھنے پر مجروح سلطان پوری کو فلم فیئر ایوارڈ سے نوازا گیا تھا۔1993ء میں دادا صاحب پھالکے ایوارڈ دیا گیا۔ ناصر حسین کی فلموں کے لیے مجروح نے جو گیت لکھے ان میں سے زیادہ تر گیت مقبول ہوئے اور فلمیں کام یاب ثابت ہوئیں۔
مجروح کی شاعری کے آغاز کے بارے میں مجروح کے لڑکپن کے دوست نے رسالہ "چراغ” (بمبئی) میں لکھا ہے: "مجروح کی طبیعت کو شاعری سے لگاؤ اور کافی مناسبت تھی۔ سلطان پور میں ہی پہلی غزل کہی اور وہیں کے ایک آل انڈیا مشاعرے میں سنائی۔ اس مشاعرے میں مولانا آسی الدنی شریک تھے۔ مجروح نے اپنی ایک غزل مولانا کی خدمت بغرضِ اصلاح روانہ کی۔ مولانا نے مجروح کے خیالات کو باقی رکھنے اور کسی صحیح مشورے کے بجائے ان کے اشعار ہی سرے سے کاٹ دیے اور اپنے اشعار لکھ دیے۔ مجروح نے مولانا کو لکھا کہ مقصدِ اصلاح یہ ہے کہ اگر قواعد با زبان یا بحر کی کوئی لغزش ہو تو مجھے آپ اس طرف متوجہ کریں، یہ نہیں کہ اپنے اشعار کا اضافہ کر دیں۔ مولانا نے جواب دیا کہ اس قسم کی اصلاح کے لیے میرے پاس وقت نہیں، چناںچہ یہ سلسلہ بند ہو گیا۔”
اس کے بعد مجروح نے اپنا کلام کسی استاد کو نہیں دکھایا اور خود محنت کر کے فنِ شاعری اور زبان و بیان پر وہ قدرت حاصل کی جو ان کے معاصرین میں بہت کم لوگوں کو نصیب تھی۔
بھارت کے اس مشہور فلمی شاعر کے جن گیتوں نے مقبولیت کے نئے ریکارڈ قائم کیے، ان میں چھوڑ دو آنچل زمانہ کیا کہے گا، چاہوں گا میں تجھے سانجھ سویرے، بابو جی دھیرے چلنا، چلو سجنا جہاں تک گھٹا چلے و دیگر شامل ہیں۔
مجروح سلطان پوری کا یہ زباں زدِ عام شعر آپ نے بھی سنا ہوگا۔
میں اکیلا ہی چلا تھا جانبِ منزل مگر
لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا
24 مئی 2004ء کو مجروح سلطان پوری اس دنیا سے رخصت ہوگئے تھے۔ ان کے یہ اشعار بھی بہت مشہور ہوئے:
جلا کے مشعلِ جاں ہم جنوں صفات چلے
جو گھر کو آگ لگائے ہمارے ساتھ چلے
ستونِ دار پہ رکھتے چلو سَروں کے چراغ
جہاں تلک یہ ستم کی سیاہ رات چلے