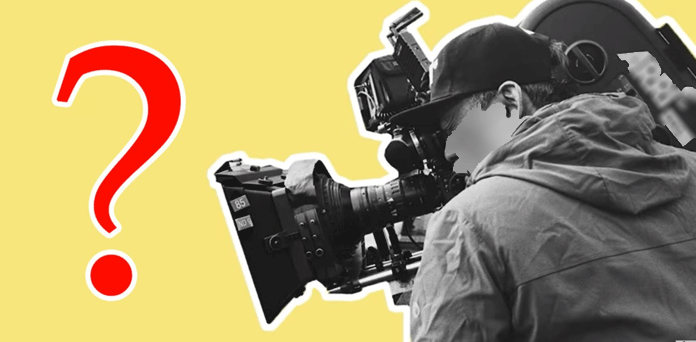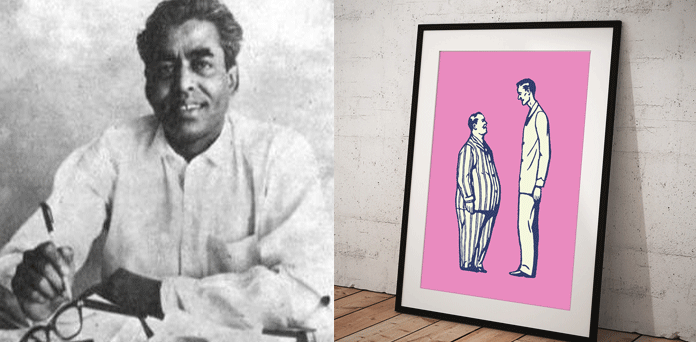سیاست داں سے بڑا سیاح کوئی نہیں۔ اندرون ملک وہ ایک پارٹی سے دوسری اور دوسری سے تیسری کی سیاحت کرتا ہے اور اگر کسی جوڑ توڑ کے نتیجے میں برسراقتدار آجاتا ہے، تو سرکاری خرچے پر اپنے اہل وعیال، دوست احباب اور خوشامدیوں کے ساتھ ملکوں ملکوں گھومنے پھرنے کا لائسنس حاصل کر لیتا ہے۔
سیاست داں کو وفاداری بدلنے کے لیے اسمبلی کا ایک ٹکٹ یا کابینہ کی ایک نشست کی ترغیب کافی ہے۔ اب تو سیاسی وفاداری کا معیار یہ رہ گیا ہے کہ جس پارٹی نے کسی سیاست داں کو خریدا ہے، وہ اسی کا ہو رہے، لیکن وہ تو دھڑلے سے کہتا ہے کہ سیاست میں کوئی چیز حتمی، آخری یا مستقل نہیں ہوتی۔ چناں چہ جب بھی انتخابات کا موسم قریب آتا ہے سیاست کا میدان ”اسٹاک ایکسچینج“ میں تبدیل ہو جاتا ہے اور سودوں میں تیزی آجاتی ہے۔ انگریزی میں اس طرح بک جانے والے سیاست داں کو Turncoat کہا جاتا ہے، جب کہ اردو میں وہ اپنی لڑھکتی خصلت کے باعث ”لوٹا“ کہلاتا ہے۔ جس پارٹی سے وہ قطع تعلق کرتا ہے، وہ اسے ”گندا انڈا“ قرار دیتی ہے اور جہاں جاتا ہے وہاں اس کی ایسی آؤ بھگت ہوتی ہے کہ وہ خود کو بھگت کبیر سمجھنے لگتا ہے۔ آپ ایسے کسی سیاست داں کے جس کو سابقہ ریکارڈ کی بنا پر شرمندہ کرنے کی کوشش کریں، تو وہ علامہ اقبال کی سند لے آتا ہے:
جہاں میں اہل ایماں صورتِ خورشید جیتے ہیں
اِدھر ڈوبے اُدھر نکلے، اُدھر ڈوبے اِدھر نکلے
سیاست داں کا ہر قدم ہر قول، ہر کام قوم کے بہترین مفاد میں ہوتا ہے۔ اس کے ”یوٹرنز“ قلابازیوں، کہہ مکرنیوں اور وعدہ خلافیوں، سب پر قوم کے بہترین مفاد کی چھاپ لگی ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ وہ قومی خزانے کی لوٹ کھسوٹ بھی قوم کے بہترین مفاد میں کرتا ہے۔ وہ قوم کے بہترین مفاد میں کوئی ادارہ بناتا ہے اور پھر قوم کے بہترین مفاد میں اسے بند کر دیتا ہے۔ یہی حال قانون سازی کا ہے۔ بے چارہ قانون خود پکار اٹھتا ہے کہ ’میں ترا چراغ ہوں، جلائے جا بجھائے جا۔‘ عوام کی بے لوث خدمت اس کا اولین و آخرین نصب العین ہوتا ہے۔ سیاست داں اس وقت تک خدمت کرتا رہتا ہے، جب تک دَھر نہیں لیا جاتا اور جب دَھر لیا جاتا ہے، تو پولیس وین میں بیٹھ کر پوری ڈھٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انگلیوں سے ”وی“ (V) کا نشان بنانا نہیں بھولتا، جس سے اپنے حواریوں کو یہ پیغام دینا مقصود ہوتا ہے کہ ڈٹے رہو جیت بالآخر بدعنوانی کی ہوگی۔ جیل جاتے ہی وہ بیمار پڑ جاتا ہے اور سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر اسپتال کے اسپیشل وارڈ میں داخل کر لیا جاتا ہے۔ اس دوران اس کی ضمانت ہو گئی، تو ٹھیک ورنہ میڈیکل بورڈ فوراً اس کی مرضی کے ملک میں علاج کی سفارش کر دیتا ہے اور وہ یہ کہتا ہوا نو دو گیارہ ہو جاتا ہے کہ؎
اب تو جاتے ہیں بُت کدے سے میر
پھر ملیں گے اگر خدا لایا
(طنز و مزاح پر مبنی یہ تحریر ڈاکٹر ایس ایم معین قریشی کی "تصنیف کتنے آدمی تھے؟” سے چنا گیا)