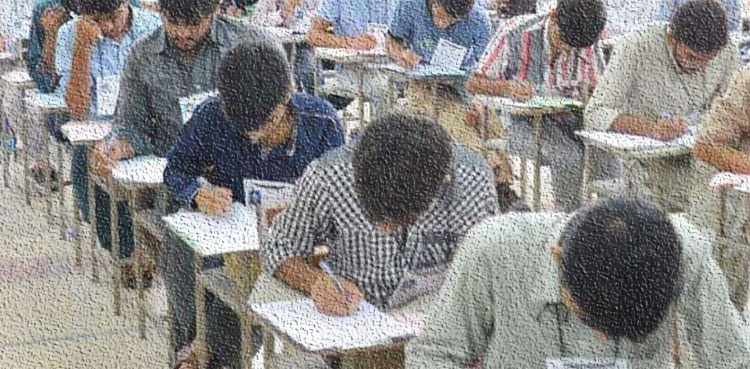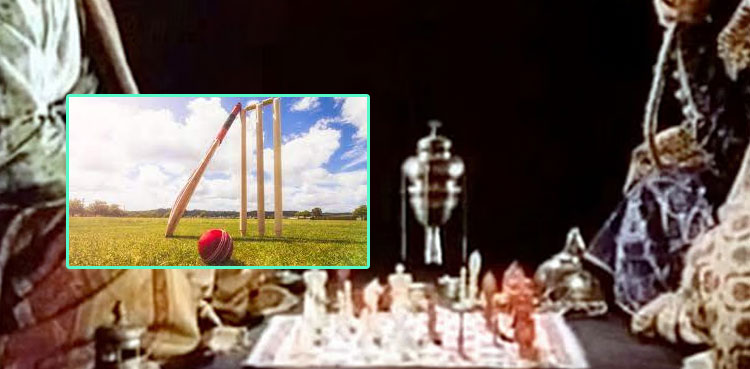دیمک پودوں اور لکڑی میں پایا جانے والا ایک کیڑا ہے جس کی کئی اقسام ہیں۔ یہ جس لکڑی کو لگ جائے اسے ختم کر کے چھوڑتی ہے۔
یہاں ہم اردو کے مشہور مزاح نگار مجتبی حسین کے مضمون سے ایک پارہ نقل کررہے ہیں جو آپ کی دل چسپی کا باعث بنے گا۔ یہ ان کے مضمون دیمکوں کی ملکہ سے ایک ملاقات سے ماخوذ ہے۔ مصنّف ایک لائبریری میں جاتے ہیں جہاں اردو کے شاعر کے دیوان میں انھیں دیمک نظر آتی ہے۔ اس سے ہونے والی بات چیت کچھ یوں ہے۔
"میں(مصنّف) نے کہا، ’’اب جب کہ تم نے خاصے اردو ادب کو چاٹ لیا ہے تو یہ بتاؤ یہ تمہیں کیسے لگتا ہے؟‘‘
بولی، ’’شروع شروع میں یہ میرے پلے نہیں پڑا تھا۔ بڑا ریاض کیا۔ متقدمین کے دیوان چاٹے۔ مشکل یہ ہوئی کہ میں نے سب سے پہلے ’دیوانِ غالب‘ پر ہاتھ صاف کرنے کی کوشش کی۔ خاک سمجھ میں نہ آیا۔ لہٰذا مولوی اسماعیل میرٹھی کی آسان اور زود ہضم نظمیں پہلے نوشِ جان لیں۔ پھر وہ کیا کہتے ہیں آپ کے مفلر والے شاعر، وہی جو پانی پت میں رہتے تھے مگر وہاں کی جنگوں میں شریک نہیں تھے۔ ارے اپنے وہی مولانا حالی۔ ان کی نصیحت آمیز شاعری پڑھی۔ شاعری کم کرتے تھے نصیحت زیادہ کرتے تھے۔ وہ تو اچھا ہوا کہ تم لوگوں نے ان کی نصیحتوں پرعمل نہیں کیا۔ اگر کیا ہوتا تو آج تمہارے گلے میں بھی روایات کا ایک بوسیدہ سا مفلر ہوتا۔ اب تو خیر سے سارا ہی اردو ادب میری مٹھی میں ہے۔ سب کو چاٹ چکی ہوں۔
ایک بارغلطی سے جوش ملیح آبادی کی ایک رباعی چاٹ لی طبیعت میں ایسا بھونچال آیا کہ سارا وجود آپے سے باہر ہونے لگا۔ اس کے اثر کو زائل کرنے کے لئے چار و ناچار، جاں نثار اختر کی گھر آنگن والی شاعری چاٹنی پڑی۔
ویسے تو میں نے دنیا کی کم و بیش ساری زبانوں کی کتابیں چاٹ لی ہیں لیکن اردو شاعروں میں ہی یہ وصف دیکھا ہے کہ اپنے معشوق کو کبھی چین سے بیٹھنے نہیں دیتے۔ کوئی معشوق کے گیسو سنوارنا چاہتا ہے تو کوئی انہیں بکھیر دینا چاہتا ہے۔ کوئی وصل کا طالب ہے تو کوئی ہجر کی لذتوں میں سرشار رہنا چاہتا ہے۔ کوئی معشوق کو کوٹھے پر بلانے کا قائل ہے تو کوئی اس کا دیدار بھی یوں کرنا چاہتا ہے جیسے چوری کر رہا ہو۔ تم لوگ آخر معشوق سے چاہتے کیا ہو۔ اسے ہزار طرح پریشان کیوں کرتے ہو۔ اردو شاعری میں معشوق خود شاعر سے کہیں زیادہ مصروف نظر آتا ہے۔ یہ بات کسی اور زبان کے معشوق میں نظر نہیں آئی۔ اردو شاعروں کا عشق بھی عجیب و غریب ہے۔ عشق کرنا ہو تو سیدھے سیدھے عشق کرو بھائی۔
کس نے کہا ہے تم سے کہ معشوق کی یاد آئے تو آسمان کی طرف دیکھ کر تارے گنتے رہو۔ اس کی یاد نے زور مارا تو اپنا گریبان پھاڑنے کے لئے بیٹھ جاؤ۔ معلوم ہے کپڑا کتنا مہنگا ہوگیا ہے۔ سیدھے سیدھے معشوق کے پاس جاتے کیوں نہیں۔ اپنے دل کا مدعا بیان کیوں نہیں کرتے۔ عاشق، بزدل اور ڈرپوک تو ایسے ہی چونچلے کر کے اپنے دل کو بہلاتا رہتا ہے۔‘‘