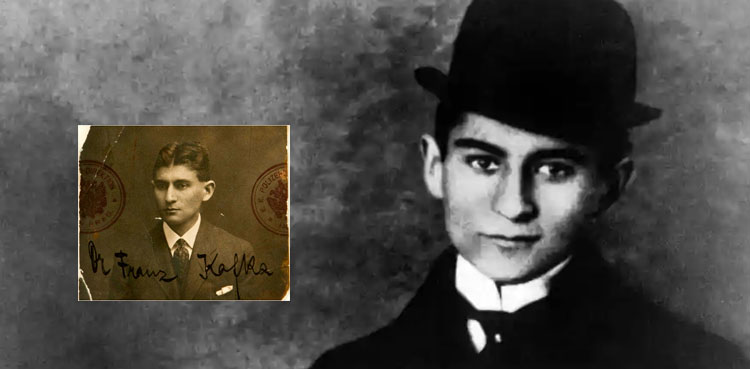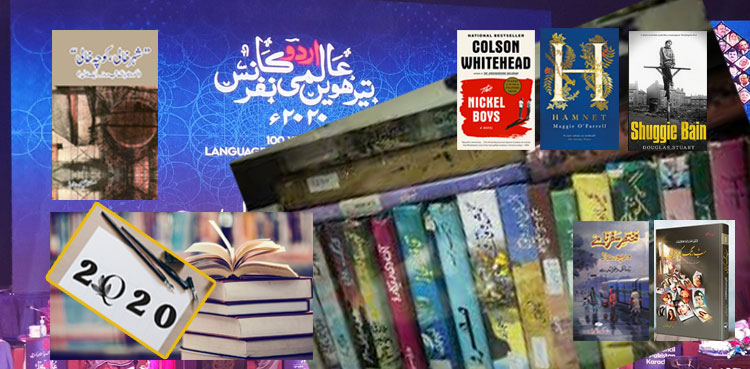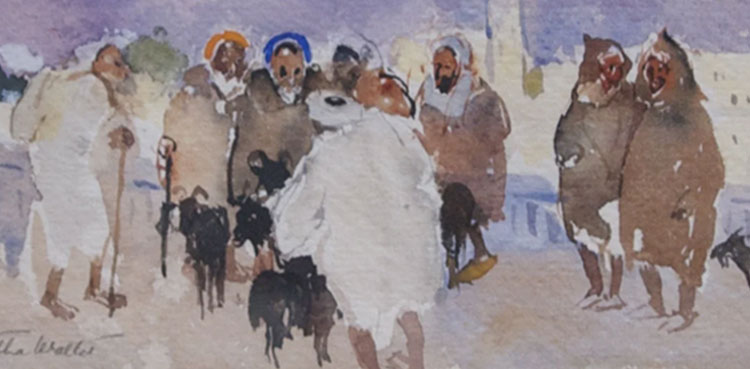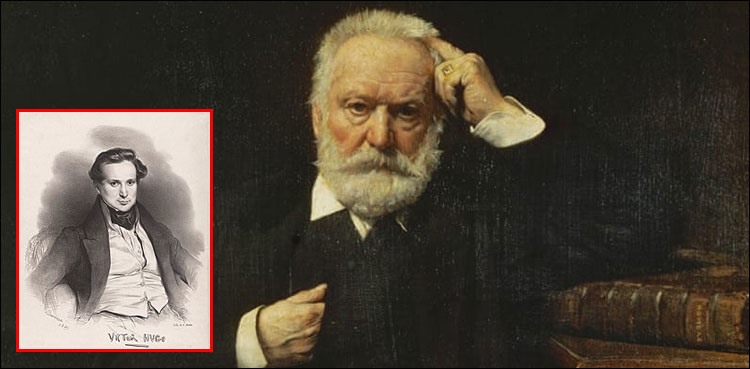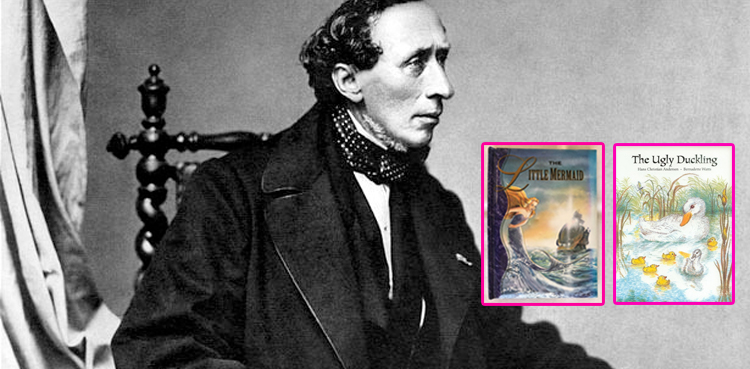تحریر: عارف عزیز
رواں صدی کی اس دہائی کا یہ آخری سال، اگلی کئی دہائیوں تک مختلف شکلوں میں ہمارے سامنے آتا رہے گا اور کرونا کی وبا فنونِ لطیفہ، بالخصوص اصنافِ ادب کا موضوع ہو گی۔
قومی اور مقامی زبانوں کے تخلیق کار کووڈ 19 کے خوف میں مبتلا انسان کے رویّوں میں تبدیلی کو حزنیہ اور طربیہ داستانوں میں پیش کریں گے، حقیقی واقعات پر مبنی کہانیاں لکھی جائیں گی، شاعری تخلیق ہوگی اور قارئین وبا کے دنوں میں انسان کے ہر روپ کو پڑھ سکیں گے۔
اس برس جہاں موضوعات کو تخیّل کی گرفت میں لے کر تخلیق کے سانچے میں ڈھالنے تک ادبی سفر جاری رہا، وہیں یہ ہلاکت خیز سال سماجی حسیّت، تہذیبی شعور اور تمدّنی اسباب و عوامل پر تسلسل کے ساتھ آئندہ بھی لکھنے کا موقع دے کے رخصت ہورہا ہے۔
اگر ہم 2020ء میں عالمی ادب اور پاکستان میں تخلیقی سفر پر نظر ڈالیں تو کئی اہم اور قابلِ ذکر تقاریب کا انعقاد، میلے اور ادبی سرگرمیاں ہی نہیں طباعت و اشاعت کا سلسلہ بھی بندشِ عامّہ (لاک ڈاؤن) کے سبب متاثر رہا۔ اکثر تقریبات ملتوی کردی گئی تھیں اور بعد میں محدود پیمانے پر منعقد ہوئیں۔ متعدد ادبی میلوں اور تقاریب کی منسوخی کا اعلان کیا گیا اور بعض آن لائن انجام پائیں۔
آئیے، وبا کے دنوں میں عالمی ادب پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔
دنیا کے معتبر انعام، نوبیل کی تقریب
2020ء میں ادب کا نوبیل انعام لوئس گلک کے نام ہوا۔ سویڈش اکیڈمی آف نوبیل پرائز کا یہ اعزاز دنیا بھر میں مشہور اور نہایت معتبر تصور کیا جاتا ہے۔ 8 اکتوبر 2020ء کو اکیڈمی نے امریکا کی خاتون شاعر لوئس گلک کو نوبیل انعام دینے کا اعلان کیا۔
ان کا مکمل نام لوئس ایلزبتھ گلک ہے، اور عمر 77 برس۔ انھوں نے 1943ء میں نیویارک میں آنکھ کھولی تھی۔
کووڈ 19 کی وجہ سے انعام یافتگان باقاعدہ اور رسمی تقریب میں اپنی پزیرائی سے محروم رہے اور انھیں بھی ویڈیو لنک کے ذریعے تقریب سے جڑنا پڑا۔ لوئس گلک نے اپنی نوبیل شیلڈ اور انعام امریکا میں وصول کیا۔
لوئس گلک نے انگریزی کے علاوہ جرمن، سویڈش اور ہسپانوی زبانوں میں بھی کتابیں لکھیں۔ ان کا اصل میدان شاعری ہے، لیکن ادب کی دیگر اصناف میں بھی خوب طبع آزمائی کی۔ ان کی تصانیف کا متعدد زبانوں میں ترجمہ ہوچکا ہے۔
وہ اپنی شاعری اور ادبی مضامین سمیت مختلف تصانیف پر متعدد عالمی ایوارڈز اپنے نام کرچکی ہیں۔ ان میں اعلیٰ امریکی ادبی ایوارڈ بھی شامل ہے۔
بحیثیت شاعرہ ان کی وجہِ شہرت، اپنی تخلیقات میں بچپن اور خاندانی زندگی کو خوب صورتی سے موضوع بنانا ہے۔ نوبیل اکیڈمی نے ان کی اسی شعری انفرادیت کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ گلک انقلابی تبدیلی اور ازسرِنو جنم کی شاعرہ ہیں۔ ان کا شاعرانہ لہجہ واضح اور سادگیِ حُسن سے لبریز ہے، جو انفرادیت کو آفاقیت کی طرف لے جاتا ہے۔
اب بُکر پرائز کی طرف بڑھتے ہیں
بُکر پرائز، ڈگلس اسٹورٹ کو دیا گیا ہے اور یہ انعام ان کے ناول ‘شوگی بین’ کی وجہ سے انھیں ملا ہے۔ بُکر کی تقریب نومبر کے مہینے میں ہوئی۔
کرونا کی وجہ سے بُکر پرائز کے فاتحین بھی دیگر شرکا کی طرح آن لائن ہی تقریب کا حصّہ بن سکے۔
بُکر پرائز برطانیہ کا وہ اہم ادبی اعزاز ہے جس کی انعامی رقم انگریزی زبان کے ایسے مصنّفین کے لیے ہوتی ہے جن کی تحریر برطانیہ یا آئرلینڈ میں شایع ہوئی ہو۔
ڈگلس اسٹورٹ اسکاٹش ہیں اور ان کا ناول ’شوگی بَین‘ انہی کے آبائی شہر گلاسگو کی ایک کہانی بيان کرتا ہے۔ جیوری کے مطابق ’شوگی بَین‘ ایک ایسا ناول ہے جو ’ہمّت دلاتا ہے اور زندگی بدل دینے کی طاقت رکھتا ہے۔
اس ناول کا مرکزی کردار شوگی ہے۔ یہ کہانی 1980ء کی دہائی میں لے جاتی ہے جب ایک غریب گھرانے کے بچے کو اس کی شرابی ماں سے چھوٹی عمر میں محروم ہونا پڑتا ہے۔ یہ ڈگلس کا پہلا ناول ہے۔
بُکر پرائز کے لیے جو تحاریر شارٹ لسٹ ہوئی تھیں، ان کا بنیادی موضوع عصرِ حاضر کے چیلنجز تھے جن میں غربت اور طبقاتی نظام بھی شامل تھے۔
انٹرنیشنل بُکر کا تذکرہ
انٹرنیشنل بُکر پرائز کے فاتحین کا اعلان بھی وبا کے دنوں میں ہوا۔ یہ انعام کسی تخلیق کے انگریزی ترجمہ پر دیا جاتا ہے، نیدر لینڈز کی ماریکا لوکاس کے ناول کو ایک برطانوی لکھاری اور مترجم نے انگریزی میں ترجمہ کیا تھا جسے انعام کے لیے منتخب کیا گیا۔
پلٹزر پرائز کی تقریب اور اس کے فاتحین
2020ء کے مئی میں یہ مشہور امریکی ایوارڈ فکشن نگار کولسن وائٹ ہیڈ کے نام ہوا۔ وہ اس سے پہلے بھی ایک ادبی تخلیق پر یہ انعام جیت چکے ہیں۔
‘دا نکل بوائز’، ان کا وہ ناول ہے جو امریکا میں پیش آنے والے ایک حقیقی واقعے پر مبنی ہے۔ یہ کہانی اصلاحی مقصد اور جذبہ خدمت کے ساتھ کھولے جانے والے ایک اسکول کی ہے۔ ریاست فلوریڈا کے ایک قصبے کے اس اسکول میں 111 برس سے تدریس کا سلسلہ جاری تھا اور پھر انکشاف ہوا کہ یہاں کئی طالبِ علم بدترین جسمانی تشدد اور جنسی درندگی کا نشانہ بنے جب کہ قتل کے چند واقعات کا تعلق بھی اسی اسکول سے ہے۔
فکشن کے میدان میں وومنز پرائز
ستمبر کی 9 تاریخ کو اس ایوارڈ کی فاتح کا اعلان کیا گیا اور جو نام سامنے آیا، وہ میگی اوفیریل تھا۔ ان کا تعلق شمالی آئرلینڈ سے ہے۔ انھیں یہ انعام ‘ہیمنٹ’ نامی ناول پر دیا گیا۔ اس ادبی انعام کا آغاز 1996ء میں ہوا تھا۔
اب ادبی نشستوں اور کتب میلوں کی طرف چلتے ہیں
مختلف ممالک میں لاک ڈاؤن ختم کیے جانے کے باوجود ادبی تقاریب اور کتب میلوں کا انعقاد آسان اور محفوظ نہیں سمجھا جارہا تھا، یہی وجہ ہے 2020ء میں فرینکفرٹ کا کتب میلہ بھی نہیں سجایا جاسکا۔
فرینکفرٹ، جرمنی کا مالیاتی مرکز، اور بڑا شہر ہے جو اپنے پانچ روزہ عالمی ادبی اجتماع اور کتب میلے کے لیے بھی پہچانا جاتا ہے۔ اس ادبی میلے کا آغاز 1949ء میں ہوا تھا اور یہ فرینکفرٹ بک فیئر کے نام سے مشہور ہے۔
اس میلے میں دنیا بھر سے علم و ادب کے شیدا، نام وَر ادبی شخصیات، ناشر اور اشاعتی اداروں کے نمائندے شریک ہوتے ہیں اور اس موقع پر ادبی نشستوں کے ساتھ یہاں بک اسٹالوں پر کتابیں سجائی جاتی ہیں۔ اس سال یہ میلہ اکتوبر کے مہینے میں ڈیجیٹل میڈیا پر سجایا گیا جس میں خاص طور پر ناشر اور مشہور کتب فروش شریک ہوئے۔
پاکستان کے شہر لاہور میں ادبی تقریب
فروری کے مہینے میں جب پاکستان میں کرونا کی وبا نے زور نہ پکڑا تھا اور اس کی ہلاکت خیزی ہم پر عیاں نہیں ہوئی تھی، تب لاہور میں ادبی میلہ سجایا گیا تھا۔ اس موقع پر علم و ادب کے رسیا اور کتابوں کے شائق اکٹھے ہوئے تھے۔ نام وَر قلم کاروں اور آرٹسٹوں نے میلے میں شرکت کی تھی۔
اس میلے کا اہم اور خصوصی سیشن، "موجودہ دور میں نئی نسل کو کتب بینی کی طرف کیسے راغب کیا جائے” تھا جسے سویڈش ایمبیسی اور یونیسکو کا تعاون حاصل تھا۔
ماہرینِ تعلیم، اساتذہ، معروف علمی اور ادبی شخصیات نے اس سیشن میں اپنے خیالات کا اظہار کیا اور اس سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کی کہ بچّوں کو کس طرح مطالعے کا عادی بنایا جاسکتا ہے۔
ساحلی شہر کراچی کا ادبی میلہ
کراچی کے ساحل سے قریب ایک سبزہ زار پر فروری کی 28 تاریخ سے یکم مارچ تک ادبی میلہ سجا رہا جس میں درجنوں کتابوں کی تقریبِ رونمائی اور اہم ادبی موضوعات پر مباحث ہوئے۔
اس ادبی میلے کی افتتاحی تقریب کے مہمانِ خاص وفاقی وزیر شفقت محمود تھے۔ یہ اپنی نوعیت کا گیارہواں ادبی میلہ تھا جو اسکاٹ لینڈ کے مصنف اور تاریخ داں ولیم ڈلرمپل کی ایسٹ انڈیا کمپنی کےعروج و زوال پر لکھی گئی کتاب کے نام رہا۔
اس میلے میں انفاق فاؤنڈیشن کی جانب سے "اردو ادبی ایوارڈ” بھی دیا گیا، جس کے لیے سید کاشف رضا کی چار درویش اور ایک کچھوا، حسن منظر کی اے فلکِ ناانصاف اور عطیہ داؤد کی سندھ ادب: ایک مختصر تاریخ نام زد ہوئیں۔ جیوری میں نام ور ادیب اصغر ندیم سید، ڈاکٹر ناصر عباس اور حمید شاہد شامل تھے۔ ان کا فیصلہ حسن منظر کے حق میں سامنے آیا اور ایوارڈ ان کے نام ہوا۔
انگریزی کتب کے ‘کے ایل ایف گیٹز فارما فکشن‘ پرائز کے لیے شہریار شیخ کی ‘کال می ال‘، عظمٰی اسلم خان کی ‘دی مرکیولیس‘ اور محمد حنیف کی ‘ریڈ برڈ‘ میں سے جیوری میں شامل غازی صلاح الدّین، محترمہ حوری نورانی اور ڈاکٹر نادیہ چشتی مجاہد نے ریڈ برڈ کے حق میں فیصلہ دیا۔
ادبی میلے کے دوسرے روز سیر حاصل مباحث کے علاوہ اہم تقریب ولیم ڈلرمپل کی کتاب ’فارگاٹن ماسٹرز، انڈین پینٹنگ فار دی ایسٹ انڈیا کمپنی‘ کی رونمائی تھی۔ یہ کتاب ایسٹ انڈیا کمپنی کی برصغیر آمد اور اس کے پس منظر کو بیان کرتی ہے جو اس میلے میں بیسٹ سیلر قرار پائی۔ تیسرے دن بھی ادبی نشستوں کے علاوہ کتابوں کا تعارفی سلسلہ جاری رہا۔
وبا کے دنوں میں تیرھویں عالمی اردو کانفرنس
آرٹس کونسل آف پاکستان، کراچی کے زیرِ اہتمام 3 دسمبر کو 13 ویں عالمی اردو کانفرنس کی افتتاحی تقریب منعقد ہوئی۔ آرٹس کونسل کے صدر احمد شاہ وبا کے دنوں میں عالمی اردو کانفرنس کے انعقاد میں کام یاب رہے اور کانفرنس میں ایس او پیز کا خیال رکھتے ہوئے حسبِ پروگرام مختلف سیشن انجام پائے جنھیں ڈیجیٹل پروگرام کے تحت براہِ راست بھی نشر کیا گیا۔
پاکستان کے نام ور قلم کاروں اور آرٹسٹوں نے کانفرنس میں شرکت کی جب کہ ملک اور بیرونِ ملک مقیم لکھاری اور فن کار آن لائن بھی اس عالمی اردو کانفرنس کا حصّہ بنے۔
مختلف موضوعات پر منعقدہ سیشن کے دوران زاہدہ حنا، پیرزادہ قاسم، سحر انصاری، شاہ محمد مری، افتخار عارف، زہرہ نگاہ، اسد محمد خان، انور مقصود، نور الہدیٰ شاہ، حسینہ معین اور دیگر نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ ہندوستان سے نام ور محقّق و ادیب شمیم حنفی، گوپی چند نارنگ نے ویڈیو لنک کے ذریعے اپنی شرکت یقینی بنائی۔
اس سال بھی علاقائی زبانوں کا ادب زیرِ بحث آیا۔ اس حوالے سے سندھی، بلوچی، سرائیکی، پشتو اور پنجابی ادب پر مختلف سیشن منعقد ہوئے۔
چار روزہ عالمی اردو کانفرنس کے دوران حسبِ پروگرام کتابوں کا تعارف اور ان کی رونمائی ہوئی اور مضامین پڑھے گئے۔ یہ کانفرنس 6 دسمبر تک جاری رہی۔
پاکستانی ادب کی چند جھلکیاں
پاکستان میں رواں سال مختلف ادبی تخلیقات طباعت و اشاعت کے بعد قارئین تک پہنچیں، جو نقد و نظر کی محتاج ہیں۔ مختلف اصنافِ ادب میں نوجوان اور غیر معروف لکھاریوں کی کتابوں کی اشاعت کے علاوہ چند اہم اور نام وَر تخلیق کاروں کی کتب بھی منظرِ عام پر آئیں۔ مذکورہ ادبی میلوں میں ان تخلیقات پر مباحث اور تنقیدی مضامین اس حوالے سے اہمیت رکھتے ہیں۔
مشہور ناولوں اور مقبول سفر ناموں کے خالق مستنصر حسین تارڑ کی رواں برس دو کتابیں شایع ہوئیں۔ ایک ‘روپ بہروپ’ ہے جس میں انھوں نے اپنے دو ناولٹ قارئین تک پہنچائے ہیں، جب کہ وبا کے دنوں میں ان کی جو دوسری کتاب شایع ہوئی، وہ ایک ناول ہے جو وبا میں گزرے شب و روز پر لکھا گیا ہے۔ مصنّف نے اسے ‘ شہر خالی، کوچہ خالی’ کا نام دیا ہے۔
جمع و تدوین، اشاعت و طباعت کا سلسلہ
اگر سال کے آغاز سے اختتام تک اثر پذیر یا مقبول ادب کی بات کریں تو حسن رضا گوندل کی کاوش قابلِ ذکر ہے جو شکیل عادل زادہ کے پرستار اور سب رنگ ڈائجسٹ کے دیوانے رہے ہیں۔
سب رنگ کراچی سے شایع ہونے والا وہ ماہ نامہ ڈائجسٹ تھا جس نے اردو ڈائجسٹوں میں مقبولیت اور اشاعت کا ریکارڈ قائم کیا۔ نام وَر ناول اور افسانہ نگار شکیل عادل زادہ اس کے بانی مدیر ہیں جنھوں نے یہ ڈائجسٹ 1970ء میں نکالنا شروع کیا تھا۔ اس ڈائجسٹ میں طبع زاد اور عالمی ادب سے منتخب کردہ کہانیوں کا اردو ترجمہ شایع کیا جاتا تھا۔
حسن رضا گوندل نے کِیا یہ کہ عالمی ادب کی وہ شاہ کار کہانیاں جنھیں اردو زبان میں ترجمہ کے بعد سب رنگ میں شایع کیا گیا تھا، اکٹھا کرکے انھیں دو جلدوں میں قارئین کے سامنے رکھ دیا۔ ان کی مرتّب کردہ کہانیوں کی ایک جلد سال کے آغاز پر اور دوسری کرونا کی وبا کے دوران شایع ہوئی۔
اسی طرح اگر ہم رفتگاں کی مشہور تصانیف کی تدوین اور ان کی اشاعت کی بات کریں تو 2020ء میں جو "زندہ کتابیں” سامنے آئیں، ان کی تعداد 42 ہے۔ یہ کام راشد اشرف نے انجام دیا ہے۔ انھوں نے ہر خاص و عام میں مقبول اصنافِ ادب سے کتابوں کا انتخاب کرکے انھیں نئی جلد میں باندھ دیا ہے۔
یہ کتابیں اُن یگانہ روزگار اور صاحبانِ کمال کی تصنیف کردہ ہیں، جن کے طرزِ نگارش، سحر انگیز اسلوب اور فکر و فن سے نئے قلم کاروں کا تعارف ضروری ہے۔ راشد اشرف نے اسی مقصد اور جذبے کے تحت انھیں ازسرِ نو طباعت کے زیور سے آراستہ کیا ہے۔ ان میں پراسرار واقعات اور شکاریات کے موضوع پر بھی کتب شامل ہیں۔
زندہ کتابیں کے پلیٹ فارم سے بک اسٹالوں تک پہنچنے والی کتب کی فہرست میں سے چند یہ ہیں۔ آپ بیتیاں جن میں ‘ورودِ مسعود’ جو مسعود حسن خان کے قلم سے نکلی ہے، عارف نقوی کی ‘جلتی بجھتی یادیں’، اور سابق سفارت کار سید سبطِ یحییٰ نقوی کی یادداشتوں کا مجموعہ ‘جو ہم پہ گزری’ شامل ہیں۔ ‘کال کوٹھری’ حمید اختر کی کتاب ہے۔
ڈاکٹر بسم اللہ نیاز احمد کی ایک اہم کتاب ‘اردو گیت: تاریخ، تحقیق اور تنقید کی روشنی میں’ بھی اسی سلسلے کے تحت شایع کی گئی ہے۔
شخصی خاکے عام دل چسپی کے ساتھ مشہور و معروف شخصیات کی زندگی اور جہانِ فن میں ان کے سفر کے بارے میں بتاتے ہیں۔ ‘آشنائیاں کیا کیا’ حمید اختر کی ایسی ہی تصنیف ہے، آصف جیلانی کی ‘نایاب ہیں ہم’ اور ‘بیدار دل لوگ’ شاہ محی الحق فاروقی کی کتاب ہے۔
نام ور علمی و ادبی شخصیت ڈاکٹر مظہر محمود شیرانی کی کتاب ‘وہ کہاں گئے’ بھی اس اشاعتی لڑی میں شامل ہے۔
راشد اشرف نے ‘شکاریات کی ناقابلِ فراموش داستانیں’ بھی کتابی شکل میں پیش کی ہیں۔ انھوں نے 60 اور 70 کی دہائی میں ڈائجسٹوں میں شایع ہونے والی کہانیوں کا انتخاب کرکے انھیں چار جلدوں میں جکڑ دیا ہے۔
مختصر سفر نامے اور رپورتاژ کے لیے راشد اشرف نے تقسیم سے قبل اور بعد کے رسائل کو کھنگالا اور انھیں بھی کتابی شکل دی ہے۔