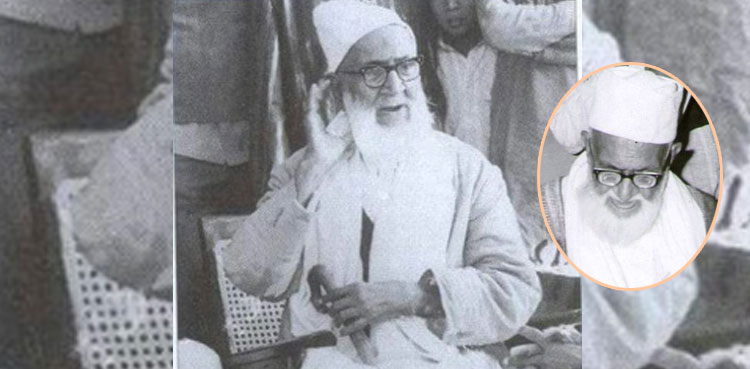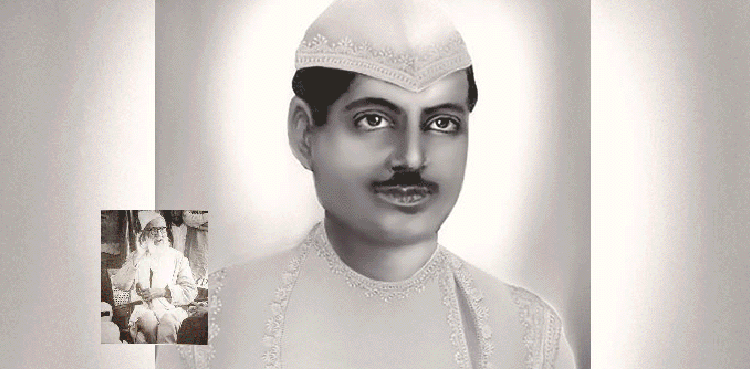لسانُ العصر اردو زبان کے نامور شاعر اکبر الہ آبادی کا لقب ہے۔ اکبر الہ آبادی نے اپنے دور میں اردو شاعری کو ایک نئی راہ دکھائی اور ان کا ظریفانہ کلام بہت مشہور ہوا۔ وہ مشرقیت کے دلدادہ تھے اور مغربی تہذیب کی کورانہ تقلید کے بڑے مخالف تھے۔
غیرمنقسم ہندوستان کے مشہور عالمِ دین، بے مثل ادیب اور شاعر عبدالماجد دریا بادی نے ‘پیامِ اکبر’ یعنی حضرت اکبر الہ آبادی کی کلیاتِ سوم پر ایک مضمون رقم کیا تھا جس سے یہ اقتباسات ہمیں اکبر کی شخصیت اور ان کے فن کو سمجھنے میں مدد دیتے ہیں۔ ملاحظہ کیجیے۔
"لسانُ العصرحضرت اکبر مغفور زمانۂ حال کے ان چندر بزرگوں میں تھے جن کا مثل و نظیر کہیں مدتوں میں جا کر پیدا ہوتا ہے۔
ان کی ذات ایک طرف شوخی و زندہ دلی اور دوسری طرف حکمت و روحانیت کا ایک حیرت انگیز مجموعہ تھی یا یوں کہیے کہ یک طرفہ معجون۔ آخر آخر ان کی شاعری نہ شاعری رہی تھی، نہ ان کا فلسفہ فلسفہ۔ ان کا سب کچھ بلکہ خود ان کا وجود مجسم حکمت و معرفت کے سانچہ میں ڈھل گیا تھا۔
ان کی گفتگو جامع تھی حکمت و ظرافت کی، ان کی صحبت ایک زندہ درس گاہ تھی تصوف و معرفت کی۔ روز مرہ کے معمولی فقروں میں وہ وہ نکتے بیان کر جاتے کہ دوسروں کو غور و فکر کے بعد بھی نہ سوجھتے اور باتوں باتوں میں ان مسائل کی گرہ کشائی کر جاتے جو سال ہا سال کے مطالعہ سے بھی نہ حل ہو پاتے۔
خوش نصیب تھے وہ جنہیں ان کی خدمت میں نیاز مندی کا شرف حاصل تھا۔ جن کی رسائی اس چشمۂ حیات تک نہ ہو سکی، انہیں آج اپنی نارسائی و محرومی پر حسرت ہے اور جن کی ہو چکی تھی انہیں یہ حسرت ہے کہ اور زیادہ سیراب کیوں نہ ہو لیے۔”
عبدالماجد دریا بادی نے اکبر کی ظرافت و زندہ دلی کا تذکرہ ان الفاظ میں کیا ہے۔
"اکبر کی شہرت و مقبولیت کی سب سے بڑی نقیب ان کی ظرافت تھی، ان کے نام کو قہقہوں نے اچھالا، ان کی شہرت کو مسکراہٹوں نے چمکایا۔ ہندوستان میں آج جو گھر گھر ان کا نام پھیلا ہوا ہے، اس عمارت کی ساری داغ بیل ان کی شوخ نگاری و لطیفہ گوئی ہی کی ڈالی ہوئی ہے۔ قوم نے ان کو جانا مگر اس حیثیت سے کہ وہ روتے ہوئے چہروں کو ہنسا دیتے ہیں۔ ملک نے ان کو پہچانا مگر اس حیثیت سے کہ وہ مرجھائے ہوئے دلوں کو کھلا دیتے ہیں۔ اس میں ذرا کلام نہیں کہ اکبر ظریف اور بہت بڑے ظریف تھے۔ لیکن جس زمانہ کے کلام پر یہاں خصوصیت کے ساتھ تبصرہ مقصود ہے، یہ زمانہ ان کی ظرافت کے شباب کا نہ تھا۔ جب تک خود جوان رہے شوخ طبعی بھی جوان رہی۔ عمر کا آفتاب جب ڈھلنے لگا تو ظرافت کا بدرِ کامل بھی رفتہ رفتہ ہلال بنتا گیا۔ اب اس کی جگہ آفتابِ معرفت طلوع ہونے لگا۔ بالوں میں سفیدی آئی، صبحِ پیری کے آثار نمودار ہوئے، تو ظرافت نے انگڑائیاں لیں اور زندہ دلی کی شمع جھلملانے لگی۔ حکمت کی تابش اور حقیقت کی تڑپ دل میں پیدا ہوئی۔ جمال حقیقی کی جلوہ آرائیوں نے چشمِ بصیرت کو محوِ نظارہ بنایا۔ سوزِ عشق نے سینہ کو گرمایا، ذوقِ عرفان نے دل کو تڑپایا، اور نورِ معرفت کی شعاعیں خود ان کے مطلعِ قلب سے اس چمک دمک کے ساتھ پھوٹیں کہ تماشائیوں کی آنکھیں قریب تھا کہ چکا چوند میں پڑ جائیں۔
لیکن ہے یہ کہ قسّامِ ازل نے ذہانت و فطانت، شوخی و زندہ دلی کی تقسیم میں ان کے لیے بڑی فیاضی سے کام لیا تھا۔ اس لیے پیرانہ سالی میں بھی ایک طرف ذاتی صدمات و خانگی مصائب کا ہجوم، اور دوسری طرف مشاغلِ دین و تصوف کے غلبہ کے باوجود یہ جذبات فنا ہرگز نہیں ہونے پائے۔ شمع جھلملا ضرور رہی تھی مگر بجھی نہ تھی یا آفتاب ڈھل ضرور چکا تھا مگر غروب تو نہیں ہوا تھا۔ بدر، ہلال بننے لگا تھا لیکن بے نور نہیں ہوا تھا، چمن سے بہار رخصت ہونے کو تھی تاہم خزاں کا سایہ بھی ابھی نہیں پڑنے پایا تھا۔ زندہ دلی نہ صرف قائم تھی بلکہ اس وقت کے ساتھ اس شدت کے ساتھ کہ دیوان پڑھنے والے متحیر اور کلام سننے والے ششدر رہ گئے۔”
اکبر کے کلیات پر تبصرہ کرتے ہوئے مضمون نگار آگے لکھتے ہیں۔
"اکبر ظریف تھے۔ ’’ہزال‘‘ و فحاش نہ تھے۔ دلوں کو خوش کرتے تھے۔ چہروں پر تبسم لاتے تھے۔ جذباتِ سفلی کے بھڑکانے کی کوشش نہ کرتے۔ ان کی ظرافت ہزل گوئی کے مترادف نہ تھی۔ اکثر صورتو ں میں معنویت سے لبریز ہوتی تھی، کہیں کہیں زبانی محاورہ، لفظی مناسبت، ترکیب کی ندرت قافیہ کی جدت کے زور سے شعر کو لطیفہ بنا دیتے تھے۔ سیاسی مسائل میں رائے بڑی آزاد رکھتے تھے لیکن جتنا کہہ جانے میں جری تھے، اتنا ہی سنانے میں چھاپنے میں پھیلانے میں محتاط تھے۔ قدم اتنا پھونک پھونک کر رکھتے کہ مخلصوں اور نیاز مندوں تک کو حیرت کی ہنسی آ جاتی۔ اور جو اتنے معتقد و باادب تھے وہ تو جھنجھلاہٹ میں خدا جانے کیا کچھ کہہ سن ڈالتے۔”