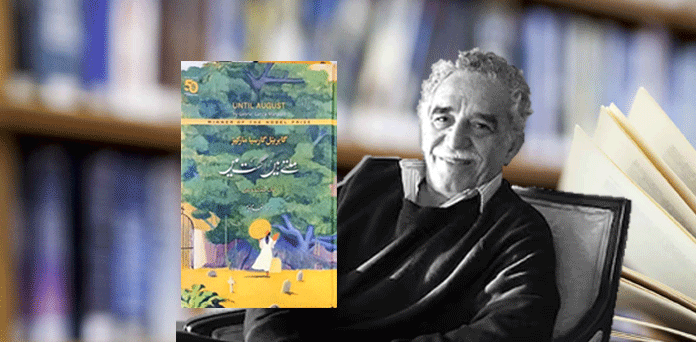اردو میں غیر ملکی ادب کے تراجم کا سلسلہ کم و بیش اردو فکشن جتنا پرانا ہے۔ آپ میر امن دہلوی تک جائیں یا ان سے بھی قبل ملا وجہی تک، اردو ترجمہ اور فکشن کا ساتھ بہت پرانا اور ابتدائی ہے۔ گزشتہ چند برسوں سے تراجم کے سلسلے میں ایک نمایاں جوش و خروش دیکھا جا رہا ہے، شاید اشاعتی اداروں کی جانب سے اس سلسلے میں ایک مثبت اشارہ پایا جاتا ہے، اگرچہ یہ مترجِمین کے لیے اب بھی کوئی منافع بخش عمل نہیں ہے۔ شاید کوئی پبلشر آپ سے آپ کا ناول اتنے اطمینان کے ساتھ قبول نہ کرے جتنے اطمینان کے ساتھ کوئی ترجمہ قبول کرے۔
تراجم کے بارے میں بہت سی باتیں کی جاتی ہیں لیکن اس سلسلے میں جو سب سے اہم بات ہے، وہ یہ ہے کہ، تراجم کے ذریعے ثقافتی ڈسکورس کی منتقلی ممکن ہو جاتی ہے۔ کسی زبان میں ڈسکورس کی تشکیل کے عمل کو اس زبان کے علم کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا، لیکن ادب ایک ایسی شے ہے جو اپنے ترجمے کی صورت میں ایک اجنبی اور غیر متعلقہ ڈسکورس کو بھی مانوس اور متعلقہ محسوس کرا دیتا ہے۔ اگر کوئی اس امر سے واقف ہے کہ ہماری زبان اور ہماری زندگی میں ڈسکورسز کا کتنا عمل دخل اور اثر ہے، وہ تراجم کی اس اہمیت کو بھی بہ خوبی سمجھ سکتا ہے۔ چناں چہ ہمارے درمیان اگر کوئی اچھا مترجم موجود ہے تو اسے مختلف ثقافتوں کے درمیان ایک مذاکرات کار کا درجہ حاصل ہے۔ جو دو زبانوں اور دو ثقافتوں کے درمیان معاملہ کررہا ہے۔
ایک جملہ ایسا ہے جو ثقافتی ہی نہیں بلکہ ہمارے سماجی، سیاسی اور معاشی مظاہر میں بھی کلیشے کی مانند دہرایا جاتا ہے۔ وہ جملہ ہے: ”یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔“
اسی طرح مترجمین کے بارے میں بھی بہت سی باتیں کی جاتی ہیں لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ کیا اس میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ لفظ کی بجائے معنی کے فہم تک رسائی کرے؟ مصنف نے اگر کسی لفظ کو ڈسکورس بنا کر پیش کیا ہے تو محض اس کا قاموسی معنیٰ ترجمے کے عمل کی تکمیل نہیں کر سکتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے تراجم اسی لیے ہمیں بے مزہ محسوس ہوتے ہیں اور لگا کرتا ہے جیسے مصنف نے ادب لکھتے ہوئے بھی اس کی زبان کو اُسی کے محاسن سے پاک رکھا ہے۔
ایک جملہ ایسا ہے جو ثقافتی ہی نہیں بلکہ ہمارے سماجی، سیاسی اور معاشی مظاہر میں بھی کلیشے کی مانند دہرایا جاتا ہے۔ وہ جملہ ہے: ”یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔“ یا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہمیں ہر کام آسان چاہیے، یا یہ کہ جتنا لکھا ہے، اُسے کافی سمجھا جائے۔ میرا خیال ہے کہ اگر کوئی شخص ناول لکھ رہا ہے تو یہ اس کے تخلیقی جذبے کی سنجیدگی کا غماز عمل ہے۔ لیکن اگر وہ غیر ملکی ادب کا ترجمہ کر رہا ہے تو اس میں تخلیقی جذبہ کارفرما تو ہے ہی، اس میں فکری سنجیدگی کی ایک اعلیٰ سطح بھی کارفرما ہے۔ اس کے بغیر ترجمے کا سارا عمل ہی بے معنی اور مہمل ہو جاتا ہے۔ تو یہاں سنجیدگی کا اتنا بار ہے، ایسے میں ترجمے کے عمل کے سلسلے میں یہ جملہ بولنا یا لکھنا کہ ”یہ کوئی آسان کام نہیں“ خود ایک مہمل بات ہے۔ ترجمہ کتنا ہی مشکل کام کیوں نہ ہو، مترجم کا بے پناہ جذبہ اسے اس کے لیے ممکن بنا دیتا ہے۔
ترجمہ خود میری پروفیشنل لائف کا ایک اہم حصہ رہا ہے۔ میں ٹائم اور نیوز ویک کی ٹائٹل اسٹوریز ترجمہ کرتا رہا ہوں۔ آرٹ بک والڈ کے کالم ترجمہ کرتے ہوئے کئی بار مجھے دانتوں تلے پسینہ آیا۔ نوبیل انعام یافتہ شیمس ہینی کی نظمیں ترجمہ کرتے ہوئے اس عمل میں مستور بے پناہ سنجیدگی کی ضرورت کو میں نے گہرائی سے محسوس کیا۔ اور حال ہی میں ژاک دریدا کے ایک مضمون کا ترجمہ کرتے ہوئے میں نے اس اضطراب کو محسوس کیا جو کسی اور زبان کے متن کے زیادہ سے زیادہ درست مفہوم تک رسائی کے لیے بار بار ایڈیٹنگ کے عمل سے گزرتے ہوئے پیدا ہوتا ہے۔
میڈیا سے وابستگی نے ترجمے کے عمل کی کچھ باریکیوں سے بھی روشناس کرایا۔ ان میں ایک یہ بھی شامل ہے جس کی مثال میں نے اس کتاب میں مارکیز کے تعارف والے صفحے پر پائی۔ لکھا ہے کہ مارکیز کی دیگر تصانیف میں ”وبا کے دنوں میں محبت“ ”ایک پیش گفتہ موت کی روداد“ وغیرہ شامل ہیں۔ جب کہ مارکیز نے ان عنوانات سے کوئی ناول نہیں لکھے۔ ہم سمیت پوری دنیا تک یہ ناول انگریزی زبان میں پہنچے ہیں۔ کسی بھی ناول کا ترجمہ کرتے ہوئے کتاب پر عنوان کا بھی ترجمہ کیا جاتا ہے اور کیا جانا چاہیے، لیکن مصنف کے ناولوں کی فہرست اگر مذکور کرنی ہو تو پھر ان عنوانات کا ترجمہ تکلیف دہ ہو جاتا ہے۔ کیوں کہ انٹرنیٹ پر ہم انگریزی عنوان ہی لکھ کر اس کے بارے میں دستیاب تمام معلومات تک رسائی کر سکتے ہیں۔ اچھی بات یہ ہے کہ انعام ندیم کے تعارف میں کتابوں کے عنوانات میں یہ غلطی نہیں دہرائی گئی ہے۔
ترجمہ کرتے ہوئے ایک بہت عام غلطی بار بار دہرائی جاتی ہے، لفظ کا ترجمہ ہو جاتا ہے لیکن احساس کی ترجمانی رہ جاتی ہے۔ مترجم کو متن کی قرات کے دوران الفاظ اور جملوں کے قاموسی مفہوم پر پوری توجہ مرکوز کرنی پڑتی ہے لیکن اچھا مترجم ہمیشہ یہ دیکھتا ہے کہ کوئی لفظ یا جملہ پڑھ کر جو مفہوم اس کے ذہن میں آ رہا ہے، وہ تو ایک طرف، لیکن اسے پڑھ کر اسے محسوس کیا ہوا ہے، یہ اس کے لیے کہیں زیادہ اہم ہوتا ہے۔ کیوں کہ ادبی تراجم تب تک مکمل نہیں ہو پاتے جب تک متن کے پیدا کردہ احساس تک رسائی نہیں کی جاتی۔ ہم ایسے بھی تراجم دیکھتے ہیں جو نہ تو ہمارے اندر کوئی قابل قدر احساس پیدا کرتے ہیں، نہ ان سے مصنف کے فن کے بارے میں کوئی قابل قدر خیال جنم لیتا ہے۔ مجھے انعام ندیم کا یہ ترجمہ پڑھتے ہوئے خوشی ہوئی کہ انھوں نے مارکیز کے احساس کو منتقل کرنے کی کوشش کی ہے۔
 ابھی جب میں ثقافتی ڈسکورس کی بات کر رہا تھا، تو شاید کسی کے ذہن میں اس کے شناخت کیے جانے کا سوال اٹھا ہو۔ یعنی یہ کسی بھی چیز کے مفہوم پر کس طرح اثر انداز ہوتا ہے؟ ایک جگہ تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ اسے بالکل ٹھیک ٹرانسلیٹ کر لیں، اور ایک جگہ آپ کو اس سے بچنا ہوتا ہے کہ کہیں کسی لفظ کا ترجمہ کرتے ہوئے اضافی ڈسکورس شامل نہ ہو جائے۔ میں اس کی مثال اس کتاب سے دینا چاہتا ہوں۔ اردو ترجمے میں اینا مگدالینا جب سفر سے گھر لوٹتی ہے تو شوہر سے بات کرتے ہوئے دو بار لفظ ’’طہارت‘‘ ادا کرتی ہے۔ یہ لفظ پڑھتے ہوئے ذہن کو جھٹکا لگتا ہے کہ کیا وہ شریعت محمدی پر عمل پیرا تھی! طہارت اور پاکیزگی ایسی اصطلاحات ہیں جو جسم کی صفائی سے کہیں بڑھ کر مفہوم کی حامل ہیں۔ اگر اینا مگدالینا کا مقصد صرف یہ بتانا تھا کہ اس کے جسم سے پسینے کی وجہ سے بو آ رہی ہے، تو اس کے لیے زبان کسی اور لفظ کا تقاضا کرتا ہے، جو اضافی مفاہیم سے Loaded نہ ہو۔
ابھی جب میں ثقافتی ڈسکورس کی بات کر رہا تھا، تو شاید کسی کے ذہن میں اس کے شناخت کیے جانے کا سوال اٹھا ہو۔ یعنی یہ کسی بھی چیز کے مفہوم پر کس طرح اثر انداز ہوتا ہے؟ ایک جگہ تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ اسے بالکل ٹھیک ٹرانسلیٹ کر لیں، اور ایک جگہ آپ کو اس سے بچنا ہوتا ہے کہ کہیں کسی لفظ کا ترجمہ کرتے ہوئے اضافی ڈسکورس شامل نہ ہو جائے۔ میں اس کی مثال اس کتاب سے دینا چاہتا ہوں۔ اردو ترجمے میں اینا مگدالینا جب سفر سے گھر لوٹتی ہے تو شوہر سے بات کرتے ہوئے دو بار لفظ ’’طہارت‘‘ ادا کرتی ہے۔ یہ لفظ پڑھتے ہوئے ذہن کو جھٹکا لگتا ہے کہ کیا وہ شریعت محمدی پر عمل پیرا تھی! طہارت اور پاکیزگی ایسی اصطلاحات ہیں جو جسم کی صفائی سے کہیں بڑھ کر مفہوم کی حامل ہیں۔ اگر اینا مگدالینا کا مقصد صرف یہ بتانا تھا کہ اس کے جسم سے پسینے کی وجہ سے بو آ رہی ہے، تو اس کے لیے زبان کسی اور لفظ کا تقاضا کرتا ہے، جو اضافی مفاہیم سے Loaded نہ ہو۔
انعام ندیم نے چھ ناول ترجمہ کیے ہیں، اور ان کا یہ پہلا ترجمہ ہے جو میں پڑھ سکا ہوں۔ انھوں نے انگریزی جملے کی ساخت کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے اردو ترجمہ کیا ہے۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ مارکیز نے کس قسم کے جملوں کی مدد سے کہانی سناتے ہوئے جذبات سے بھری ہوئی سچویشنز تخلیق کی ہیں۔ مارکیز کی داستان گوئی ہمارے اس دور کی ایک مثالی داستان گوئی ہے۔ یہ بات میں نہ صرف دوسروں کی تقلید میں کہہ رہا ہوں بلکہ خود میری بھی اس وجہ سے یہی رائے ہے کہ ان کے ناول پڑھتے ہوئے میں ان میں پوری طرح خود کو کھو دیتا ہوں۔ مارکیز کا یہ فن اس ناولٹ میں بہت ہی سکڑی ہوئی حالت میں ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے مارکیز نے بے حد اختصار سے کام لیا ہے، جس کی وجہ سے مجھے ایسا محسوس ہوا کہ انھوں نے ایک طویل داستان کی تلخیص پیش کی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ایک تلخیص میں تمام داستانوی رنگوں کو برقرار رکھنا ممکن نہیں ہے، ایسے میں انگریزی کے مقابل اردو جیسی چھوٹی زبان میں اس کی منتقلی کسی چیلنج سے کم امر نہیں۔ انعام ندیم نے اس چیلنج کو قبول کیا، اور مارکیز کے ناول کا انگریزی ترجمہ Until August کے عنوان سے مارکیٹ میں آتے ہی ڈیڑھ ماہ کے اندر اندر اس کا اردو ترجمہ ’’ملتے ہیں اگست میں‘‘ کے عنوان سے پیش کر دیا۔
مارکیز جس طرح جنسی سرگرمیوں کو بے باکی کے ساتھ بیان کرتے ہیں، وہ اردو مترجم کے لیے سچ مچ کے کسی چیلنج سے کم نہیں ہوتا۔ مترجم کو کہیں کچھ چھپانا پڑتا ہے اور کہیں مدھم کرنا۔
یہ ناول ایک خاتون کی جنسی سرگرمیوں کی ایک ایسی داستان ہے جس کا بنیادی سرا ایک پُراسرار معاملے سے جڑا ہے۔ یہ مارکیز کا دستخطی اسٹائل ہے، وہ اپنے ناولوں میں جادوئی حقیقت نگاری کا عنصر اسی طرح لے کر آتے ہیں۔ مارکیز جس طرح جنسی سرگرمیوں کو بے باکی کے ساتھ بیان کرتے ہیں، وہ اردو مترجم کے لیے سچ مچ کے کسی چیلنج سے کم نہیں ہوتا۔ مترجم کو کہیں کچھ چھپانا پڑتا ہے اور کہیں مدھم کرنا۔ انعام ندیم نے ایسے حصوں سے گزرتے ہوئے پوری طرح اپنے ہنر کا اظہار کیا ہے اور بعض مقامات کو رواں اور خوب صورت نثر میں منتقل کیا ہے۔ مجموعی طور پر یہ ایک اچھا اور دل پذیر ترجمہ ہے، اور اسے بک کارنر نے بہت خوب صورتی سے چھاپا ہے۔ اس کتاب کی ایک منفرد خصوصیت یہ بھی ہے کہ انعام ندیم نے صرف ناول ہی نہیں، بلکہ وہ مسودہ جسے مارکیز نے خود ایڈٹ کیا تھا، وہ بھی اس کتاب کا حصہ بنا دیا ہے۔