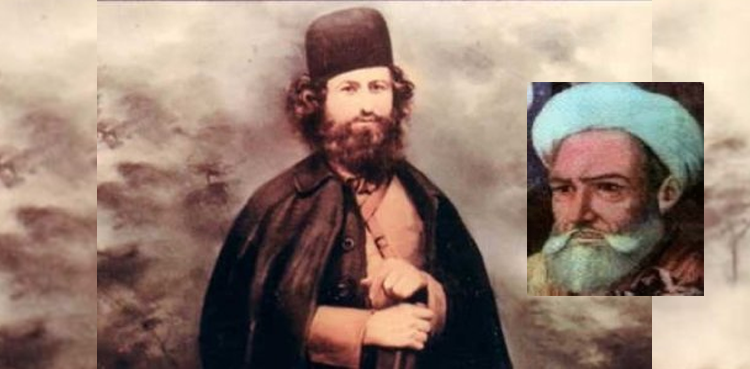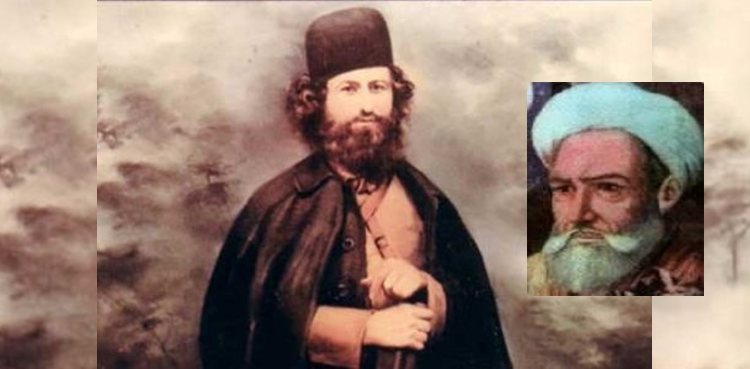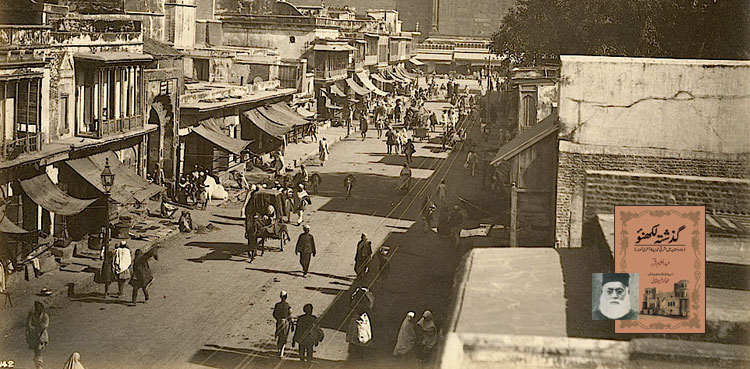ہماری رائے میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں اس قدر شاعر گذرے ہوں گے جس قدر کہ فارس میں پائے گئے ہیں۔ بہت سی کتابیں فارسی نظم میں ایسی ہیں کہ پڑھنے کے لئے زندگی انسان کی کافی نہیں ہے۔ لیکن سب شاعر ایسے نہیں ہیں کہ ان کی تصنیفات لائق پڑھنے کے ہیں لیکن چند ایسے ہیں جو لاثانی ہیں اور جن کی تصنیفات لائق پڑھنے کے ہیں۔ مثلاً حافظ، فردوسی اور سعدی وغیرہ۔
واضح ہو کہ پہلے لوگ ایران کے دین محمدی نہیں رکھتے تھے۔ وہ آتش پرست تھے اور اس وقت میں بہت سی کتابیں تاریخ وغیرہ کی نظم میں بیچ زبان فارسی کے تھیں اور ان نظم کی کتابوں میں بہت خوبی اور فصاحت سے حال دلیروں اور بادشاہوں سلف کا لکھا ہوا تھا اور از بسکہ بعض آدمی بڑے شجاع اور زوردار زمانۂ سلف میں ملک ایران میں گذرے تھے تو شاعروں نے ان کو دیو ٹھہرا دیا ہے۔ ساتویں صدی عیسوی میں مسلمانوں نے ایران کو فتح کیا۔ اس وقت بہ سبب لحاظِ دین کے خلیفہ اور حکام اہلِ اسلام نے اکثر پرانی کتابوں ایرانی کو غارت کیا اور اس ترکیب سے قدیم اشعار اور نظم کی کتابیں ملک فارس میں کا نام و نشان نہیں رہا۔
ایسے برے حال میں نویں صدی عیسوی تک فارس رہا اور اس وقت خاندان عباسی کو تنزل ہوا اور کئی صوبہ دار اہل اسلام میں سے خاندان شاہی سے آزاد ہوگئے اور علیحدہ علیحدہ بادشاہ بن بیٹھے اور ان بادشاہوں نے قدر دانی علوم وفنون کی بخوبی کی لیکن اس وقت تک کوئی بڑا شاعر فاضل نہ نمودار ہوا تھا لیکن جب آخر کو دسویں صدی عیسوی میں محمود غزنوی نے شرقی اضلاع ایران کے فتح کئے تو اس عہد میں ہم فردوسی کا نام سنتے ہیں۔ حقیقت میں یہ بڑا شاعر تھا اور ایران کے فنِ شاعری کا رونق دینے والا۔
یہ شخص سنہ 940 عیسوی میں بیچ گاؤں شاداب کے کہ ضلع طوس میں جو ملک خراسان میں واقع ہے، پیدا ہوا تھا۔ اس کا باپ بطور باغبان کے حاکم طوس کا نوکر تھا اور فردوسی کا یہ طریقہ تھا کہ وہ اپنی محنت مزدوری کرتا جاتا اور دل میں مختلف مضامین سوچا کرتا اور تحصیل علوم میں بھی مشغول رہتا اور اس طرح سے بہت سے سال گزر گئے۔ اخیر کو ایک شخص ان کے ہمسایوں میں سے فردوسی اور اس کے برادران سے عداوت رکھنے لگا تھا اور ان سے اکثر تنازع رکھتا تھا اور اس باعث سے فردوسی بہت پریشان خاطر ہوا اور اپنے بھائی سے کہا کہ اپنے وطن کو چھوڑ کر کسی اور ملک میں چل بسو۔ لیکن یہ بات اس کے بھائی نے قبول نہ کی اور فردوسی اکیلا وطن چھوڑ کر طرف غزنی کے راہی ہوا، اور وہاں ان دنوں سلطان محمود سلطنت کرتا تھا۔ یہ بادشاہ قدر دان علم کا تھا اور اہلِ علم اور ہنر کی بہت خاطر کرتا۔ چنانچہ اس کے دربار میں بہت سے شاعر اور فاضل موجود رہتے تھے۔
اس اوقات میں ایک پرانی تاریخ جس میں حال بادشاہوں ایران کا جو قبل از پیدائش حضرت پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گزرے تھے مندرج تھا، ظاہر ہوئی تھی اور سلطان محمود نے یہ چاہا تھا کہ کوئی شاعر سب حال اس پرانی تاریخِ ایرانِ مذکور کو شاعری میں اچھی طرح سے بیان کرے اور اس کتاب کے ذریعے سے اس کی نیک نامی ہمیشہ رہے۔ اکثر شاعروں نے کچھ کچھ نمونہ اپنی اپنی لیاقتوں کا سلطانِ مذکور کی خدمت میں پیش کیا اور فردوسی بیان کرتا ہے کہ جب میں شہر غزنی میں وارد ہوا تو میں نہایت حیران ہوا کہ میں کس طور سے رسائی سلطان تک حاصل کروں اور اپنی لیاقت اس کے روبرو ظاہر کروں لیکن اخیر کو ایک کتاب مسمی ’’ماسہ نامہ‘‘ کہ جس کے نام کی ہم کو صحّت نہیں ہے، ایک نسخہ اس کے ہاتھ آیا، اس میں سے اس نے چند مقاموں کو نظم میں لکھ کر ایک اپنے دوست کی معرفت سلطان محمود کی خدمت میں بھیجا اور محمود نے ان اشعار کو ملاحظہ کرکے انھیں نہایت پسند کیا اور فرمایا کہ تاریخِ مذکور زمانہ سلف ایران کے فردوسی تیار کرے اور سلطان نے قرار کیا کہ فی شعر ایک اشرفی دوں گا اور فردوسی نے یہ معلوم کر کے خوشی خوشی اس کارِ عظیم کو اس امید سے کہ بذریعہ اس ترکیب کے ایک تو ہمیشہ کو نیک نامی اور دوم دولت حاصل ہوگی، اختیار کیا۔
فردوسی ہمہ تن اس کتاب کے تیار کرنے میں مصروف ہو گیا اور تیس برس تک محنت کرتا رہا اور آخر کو وہ کتاب مذکورہ تاریخ کی کہ جس کا نام ’’شاہنامہ‘‘ رکھا گیا، تیار ہوئی لیکن اس عرصہ میں بہت سی تبدیلیاں واقع ہوئی تھیں۔ جو پرانے دوست فردوسی کے تھے وہ یا تو راہی ملک عدم کے ہوگئے تھے یا ان میں سے جوش و خروش دوستی کا جاتا رہا تھا اور بعض موقوف ہو گئے تھے اور دربارِ سلطان میں نئی نئی صورتیں نظر آتی تھیں اور یہ نئے اشخاص بڈھے فردوسی کو دیکھ کر اس کی حقارت کرتے تھے جو بہ سبب تیزیٔ فکروں اور کمال محنت کے بہت کم زور اور ناتواں ہو گیا تھا اور علاوہ از ایں بد نصیبی فردوسی کا سبب یہ بھی ہوا کہ ایک شخص ایاز تھا، اسے بادشاہ بہت چاہتا تھا۔ اس شخص اور فردوسی میں دشمنی ہوگئی اور اس واسطے اس نے سلطان کے کان میں بڑی بڑی باتیں نسبت فردوسی کے پھونکیں اور یہ بیان کیا کہ فردوسی بادشاہ کے خلاف ہے اور دینِ محمدی سے پھرا ہوا ہے اور واسطے مضبوطی اس کلام کے اس نے یہ کہا کہ فردوسی نے اپنی کتاب شاہنامہ میں طریقہ زر دشت کی تعریف لکھی ہے۔
اگرچہ اور امور میں محمود بڑا عاقل تھا لیکن اس نے غیب فردوسی کو مان لیا اور جب اس شاعر بزرگ نے شاہنامہ کو تمام کرکے سلطان کی نذر کیا تو اس نے کچھ تعریف یا آفرین اس کی محنت پر نہ کی اور انعام مقرری کا تو کچھ ذکر بھی نہ کیا۔ فردوسی نے بہت مدت تک انتظار کیا کہ بادشاہ اسے اقرار کیا ہوا انعام بخشے تاکہ وہ اپنے وطن طوس جاکر اپنی باقی زندگی کو آرام سے بسر کرے لیکن سلطان نے اسے ایک کوڑی بھی نہ دی۔ آخرکار فردوسی نے چند اشعار کہے کہ مضمون ان کا یہ تھا کہ سلطان جو کہ مثال ایک بحر کے ہے اور گو میں نے اس میں غوطہ مارا لیکن موتی میرے ہاتھ نہ لگا تو وہ میری قسمت کی خطا ہے اور نہ سلطان کی فیاض کے بحر کی۔
لیکن چند عاقل آدمیوں نے سچ کہا ہے کہ جب کہ محمود ’’شاہنامہ‘‘ کے ملاحظہ سے نہ نرم ہوا تو چند اشعار کا تو اسے کیا خیال ہو، تو محمود نے بجائے اپنے اقرار پورا کرنے کے فردوسی کو ایک رنج دیا۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ سلطان نے جو یہ فردوسی سے اقرار کیا تھا کہ میں فی شعر ایک اشرفی دوں گا تو شاہنامہ کے ساٹھ ہزار اشعار ہیں تو بموجب اقرار کے اسے ساٹھ ہزار اشرفی فردوسی کو دینی لازم تھیں لیکن برعکس اس کے سلطان محمود نے بجائے ساٹھ ہزار اشرفی ساٹھ ہزار درہم فردوسی کے پاس بھیجے اور یہ کہا کہ یہ انعام تیاریٔ شاہنامے کا ہے۔ جس وقت یہ روپیہ پہنچا اس وقت فردوسی حمام میں غسل کر رہا تھا اور یہ خبر سن کر نہایت رنجیدہ اور غضب ناک ہوا اور سلطان کو بہت سی گالیاں سنائیں اور اس سب روپے کو اپنے نوکروں میں جو اس وقت موجود تھے تقسیم کر دیا۔
یہ دیکھ کر جو افسر یہ درہم لے کرآئے تھے واپس بادشاہ کے پاس گئے اور سب ماجرا بیان کیا۔ یہ سن کر محمود نہایت برہم ہوا اور حکم دیا کہ اس وقت فردوسی کو ہاتھی کے پاؤں کے نیچے کچلوا کر مروا ڈالو لیکن فردوسی نے بہت ہی عاجزی کی اور اپنی زندگی سلطان سے بخشوائی لیکن محنت بیس برس کی برباد گئی اور تمام اس کی امیدیں جاتی رہیں اور وہ دربار سے گھر کو چلا آیا اور از بسکہ اس کے دل میں نہایت رنج تھا تو اس نے ایک ہجو سلطان کی لکھ کر اور اس پر اپنی مہر کر کے ایک کو حاضرینِ دربار کے پاس بھیج دی اور یہ کہا کہ جب سلطان امورِ ریاست کے باعث بہت دق ہو، اس وقت یہ کاغذ اس کے ہاتھ میں دے دینا۔ اس ہجو میں سلطان کی نہایت برائی لکھی ہے اور اس میں یہ بھی اشارہ تھا کہ محمود بیٹا ایک غلام کا ہے۔
جب سلطان محمود نے یہ ہجو ملاحظہ کی تو وہ نہایت غضب میں آیا اور اس نے فردوسی کی تلاش میں اپنے آدمیوں کو ہر سمت میں بھیجا۔ اس وقت میں فردوسی نے شہر بغداد میں پناہ لی تھی اور جو وہاں خلیفہ تھے انہوں نے اس شاعر کی بڑی خاطر کی اور فردوسی نے ان کی تعریف میں ایک ہزار شعر اپنی کتاب شاہنامے میں زیادہ کر دیے۔ ان دنوں میں قادر باللہ خلیفہ بغداد میں تھے اور ان کے پاس محمود غزنوی نےایک سخت پیغام واسطے حوالہ کر دینے فردوسی کے بھیجا اور چونکہ خلیفہ مذکور اس قدر طاقت نہ رکھتا تھا کہ سلطان غزنوی کا مقابلہ کرسکے تو اس باعث سے فردوسی یہاں سے بھی بھاگا اور منزلیں طے کرتا ہوا مدت تک آوارہ پھرا کیا اور یہ خوف اس پر ہر وقت طاری رہا کہ کوئی ملازم محمود کا اسے گرفتار نہ کرے۔
اخیر کو جب وہ بہت مفلس اور بیمار ہو گیا تب اس نے طرف اپنے وطن طوس کے کوچ کیا اس ارادے سے کہ قبل از مرنے کے ایک دفعہ اپنے وطن کو اور دیکھ لوں۔ اس وقت میں فردوسی کی ایک بیٹی تھی اور یہ اس کے ساتھ تھی اور اسی کے باعث اس ایّامِ پیری میں ذرا تشفی تھی۔ پس وہ اپنے وطن طوس میں پہنچ گیا۔ یہاں وہ اپنی اوائل عمر میں بطور باغباں کے نوکر تھا۔ اس نے یہیں وفات پائی اور اسی مقام میں دفن ہوا۔
جب سلطان غزنوی نے حالِ وفات فردوسی کا سنا، اس نے بہت افسوس کیا۔ اب اس نے ساٹھ ہزار اشرفیاں اس کی بیٹی مذکور کے پاس بھیج دیں لیکن اس شاعر کی بیٹی بھی اسی قدر عالی مزاج جس قدر کہ اس کا باپ رکھتا تھا، رکھتی تھی اور اس عورت نے یہ اشرفیاں قبول نہ کیں اور کہا کہ ہمیں بادشاہوں کی دولت سے کیا غرض ہے۔
(متحدہ ہندوستان کے نام وَر ریاضی داں، اور تحقیقی مضمون نگار ماسٹر رام چندر کی تحریر)