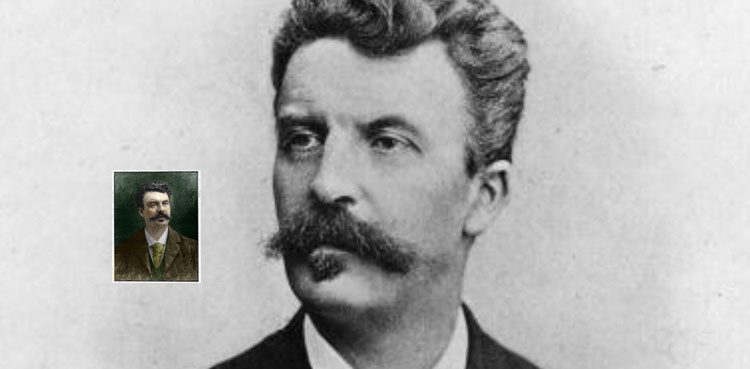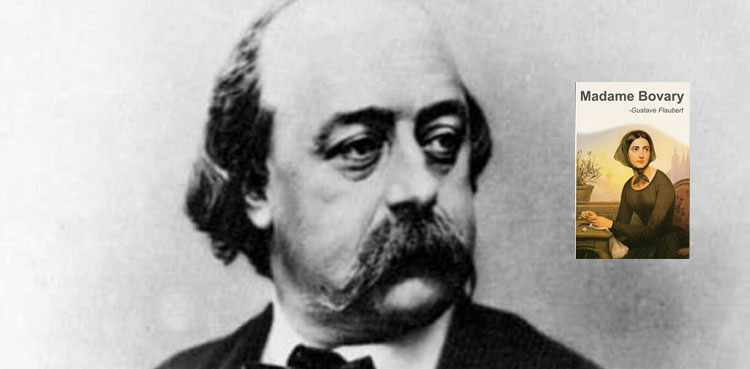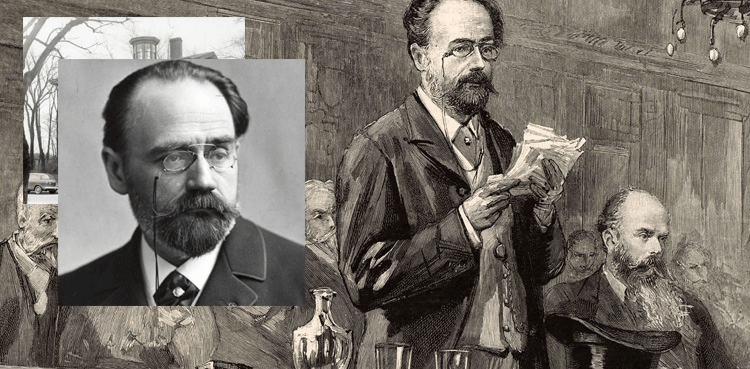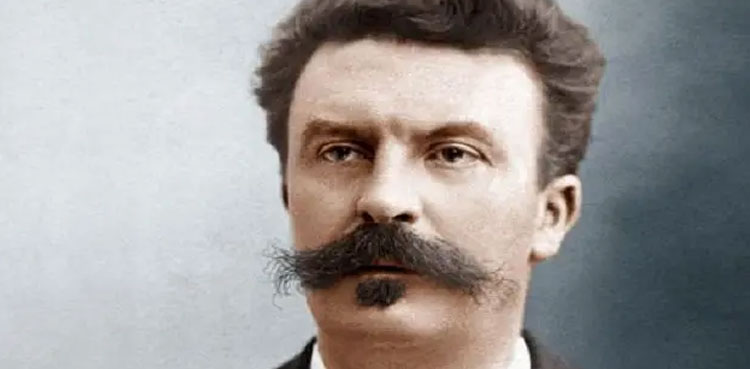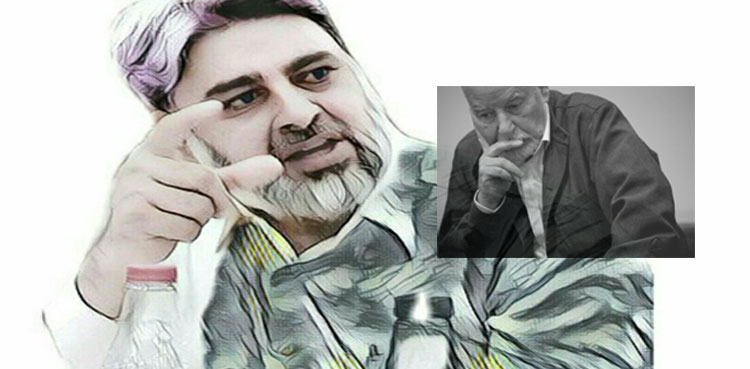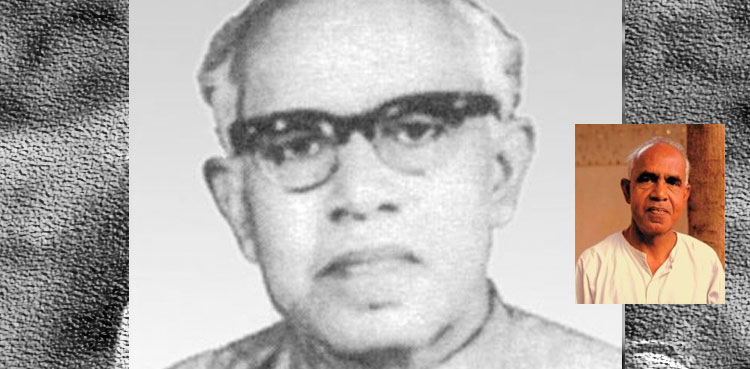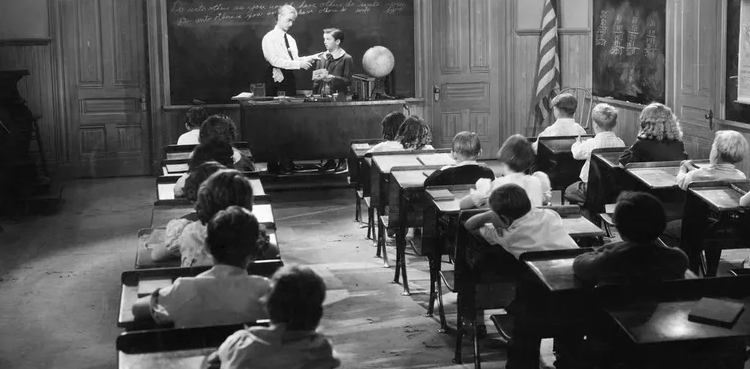سفر کا سب سے دل چسپ پہلو مختلف لوگوں سے ملنا ہوتا ہے۔ یہ اتفاقی ملاقاتیں کبھی کبھی پورا سفر یادگار بنا دیتی ہیں۔
ماضی کی یادیں ہماری عمر ایک بار پھر برسوں پیچھے دھکیل دیتی ہیں۔ نہ جانے کتنوں نے سفر کی راتیں، رَت جگوں میں بسر کی ہوں گی۔ کسی دور افتادہ گاﺅں میں جہاں ابھی اسٹیم انجن نہیں پہنچا ہے، تمام رات کوچ کا سفر اور کوچ کے سفر میں کسی خوب صورت خاتون کی ہم سفری۔
کوچ کی مٹیالی روشنی میں اس کی نیند سے بوجھل آنکھیں۔ وہ حُسن جو تمام راستے صرف جھلک دکھاتا رہا ہے، وہ حُسن جو راستے میں کہیں سے دفعتا سوار ہو کے آپ کا ہم سفر بن جاتا ہے اور جب سحر نمودار ہونے لگتی ہے، کتنا اچھا لگتا ہے، اپنی ہم سفر کو نیند سے بیدار ہوتے دیکھنا پھر وہ اپنی نشست پر محتاط ہوکر بیٹھ جاتی ہے اور یہ باور کراتی ہے کہ اس کی توجہ آپ پر نہیں بلکہ راستے کے قدرتی مناظر پر ہے۔
میری یادداشت میں سفر کے ایسے کئی لمحے محفوظ ہیں جو آج بھی مجھے ایک سرور انگیز بے چینی عطا کرتے ہیں۔
ان دنوں میں فرانس کے ایک دور دراز پہاڑی سلسلے میں پیدل سفر کر رہا تھا۔ یہ سلسلہ نہ بہت اونچا تھا نہ ہی بنجر، میں نے ابھی ایک مختصر پہاڑی عبور کی تھی اور اب ایک چھوٹے سے ریستوران میں داخل ہو رہا تھا، میری نظر ایک ضعیف عورت پر پڑی۔ ایک اجنبی، کوئی قابلِ ذکر شخصیت بھی نہیں۔ وہ تنہا ایک میز پر بیٹھی لنچ کر رہی تھی۔
کھانے کا آرڈر دے کے میں نے اسے ذرا غور سے دیکھا۔ اس کی عمر تقریباً ستّر سال ہوگی۔ نکلتا ہوا قد جوانی کی دل کشی کے آثار اب بھی اس کے چہرے پر نظر آرہے تھے، سفید بال سلیقے سے پرانے فیشن کے مطابق بنائے گئے تھے۔ اس کا لباس انگریز سیاح عورتوں جیسا تھا، یہ لباس اس کی شخصیت سے قدرے مختلف تھا جیسے اب لباس کی اس کی نظر میں زیادہ اہمیت نہ رہ گئی ہو۔
اسے دیکھ کر ایک قدیم روایتی خاتون ذہن میں ابھرتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بے چینی تھی اور چہرے پر حوادثِ زمانہ کے زخم صاف نظر آتے تھے۔ میں نے اسے بہت غور سے دیکھا۔ یہ اکیلی ان تکلیف دہ پہاڑی سلسلوں میں کیوں گھوم رہی ہے؟ میں ابھی اس کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ اس نے کھانا ختم کیا اور بل ادا کرکے شال درست کرتی ہوئی باہر نکل گئی۔
باہر ایک گائیڈ اس کا منتظر تھا۔ میں ان دونوں کو دور تک وادی کی جانب جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ دو گھنٹے بعد میں ایک وسیع سبزہ زار میں ٹہل رہا تھا۔ سبزہ زار کے کنارے کنارے شفاف دریا بہہ رہا تھا۔ منظر اتنا خوش نما تھا کہ وہیں بیٹھ جانے کو دل چاہ رہا تھا، معاً میں نے اسی عورت کو دیکھا۔
وہ دریا کے کنارے نظریں نیچی کیے ایک مجسمے کی طرح ساکت کھڑی تھی۔ وہ دریا کی طرف یوں دیکھ رہی تھی جیسے اس کی گہرائی میں کچھ تلاش کررہی ہو۔ میں اس کے قریب سے گزرا تو ایسا محسوس ہوا جیسے اس کی آنکھوں میں آنسو مچل رہے ہوں۔ مجھے دیکھ کر وہ تیزی سے درختوں کے قریب کھڑے ہوئے گائیڈ کی طرف چلی گئی۔
دوسرے دن شام کے وقت میں سیورولز کے قلعے کی سیر کررہا تھا۔ یہ قدیم قلعہ وادی کے درمیان ایک اونچے ٹیلے پر ایک دیو ہیکل مینار کی طرح کھڑا تھا۔
میں اکیلا کھنڈروں میں گھوم رہا تھا۔ اچانک ایک دیوار کے پیچھے مجھے کسی سائے کا گمان ہوا اور کسی ہیولے کی جھلک دکھائی دی جیسے اس ویران قلعے کے کسی مکین کی بے چین روح ہو۔ میں کچھ ڈرا، لیکن پھر ایک دَم میرا ڈر جاتا رہا۔ میں نے اسے پہچان لیا یہ وہی عورت تھی۔
وہ رو رہی تھی، زار و قطار رو رہی تھی، اس کے ہاتھوں میں رومال تھا جس سے وہ بار بار آنسو پونچھتی۔ میں نے لوٹ جانا مناسب سمجھا، لیکن ابھی میں پلٹنے ہی والا تھا کہ اس نے مجھے مخاطب کیا۔
”ہاں موسیو! میں رو رہی ہوں، لیکن ہمیشہ نہیں روتی ایسا شاذ و نادر ہوتا ہے۔“
”معاف کیجیے گا خاتون! میں آپ کی خلوت میں مخل ہوا۔“ میں شرمندگی سے ہکلانے لگا۔ میری سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ کیا کہوں۔
”ہاں…. نہیں۔“ اس نے کہا۔
وہ رومال آنکھوں پر رکھ کے ہچکیاں لینے لگی۔ میں گھبرا گیا۔ اس نے اپنی آنکھیں صاف کیں، خود پر قابو پایا اور اپنی روداد سنانے لگی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ جلد از جلد اپنا غم کسی دوسرے کے ساتھ بانٹنا چاہتی ہے جیسے غم کا بوجھ تنہا سہارنا اب اس کے لیے مشکل ہو۔
”یادش بخیر، ایک زمانہ تھا کہ میں بہت خوش و خرم تھی، میرا اپنا ایک گھر تھا، میرے اپنے شہر میں، لیکن اب میں وہاں اپنے گھر جانا نہیں چاہتی، وہاں وقت گزارا اتنا کرب ناک ہے کہ اب میں ہمیشہ سفر میں رہنے کی کوشش کرتی ہوں۔
وہ آہستہ آہستہ میرے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ میں خاموشی سے سن رہا تھا۔ ”میرا ایک بیٹا تھا، میرے اس حال زار کی وجہ وہی ہے، اسی کے باعث میں اس حالت کو پہنچی ہوں مگر آہ، بچے کچھ نہیں جانتے، کچھ نہیں جان سکتے، انسان کے پاس خوشی کا کتنا مختصر وقت ہوتا ہے، میں اگر اپنے بیٹے کو اب دیکھوں تو شاید ایک نظر میں اسے پہچان بھی نہ سکوں۔
”آہ، میں اس سے کتنا پیار کرتی تھی، کتنا چاہتی تھی اسے، ہر وقت اسے سینے سے لگائے رہتی، اسے ہنستاتی، بہلاتی پوری پوری رات جاگ کر اسے سوتے ہوئے دیکھتی رہتی، لوگ مجھے دیوانی سمجھتے، میرا مذاق اڑاتے لیکن میں ایک پل بھی اسے خود سے جدا نہ کرتی، میں نے اس کے بغیر کہیں آنا جانا ترک کر دیا، کیا کرتی اس سے الگ ہو کر مجھے چین ہی نہیں آتا تھا۔
وہ آٹھ سال کا ہوا تو اس کے باپ نے اسے بورڈنگ میں داخل کرادیا اس کے بعد سب کچھ ختم ہوگیا، وہ میرا نہیں رہا۔ اوہ میرے خدا! وہ صرف اتوار کو آتا اور بس۔
”پھر وہ پیرس چلا گیا، وہاں کالج میں اس کا داخلہ ہوگیا، اب وہ سال میں صرف چار مرتبہ آتا، میں ہر دفعہ اس میں نمایاں تبدیلی دیکھتی ہر بار وہ کچھ زیادہ بڑا ہوجاتا، میں اسے اپنی آنکھوں کے سامنے بڑھتے اور پھلتے پھولتے نہیں دیکھ رہی تھی، ہر بار وہ جب بھی آتا پہلے سے بدلا ہوا لگتا، اب وہ بچہ نہیں تھا لڑکا تھا، میں اس کا بچپنا کھو بیٹھی تھی، یہ دولت مجھ سے لوٹ لی گئی تھی، اگر وہ میرے ساتھ ہی رہتا تو جو محبت اسے مجھ سے ہوتی وہ اتنی آسانی سے نہیں بھلائی جاسکتی تھی۔
”میں اسے سال میں صرف چار بار دیکھتی تھی۔ ذرا غور کرو، ہر دفعہ اس کی آمد پر اس کا جسم اس کی آنکھیں، اس کی حرکتیں اس کی آواز، اس کی ہنسی وہ نہیں رہتی تھی جو گزشتہ آمد کے موقع پر ہوتی تھی۔ ہر دفعہ وہ نیا بن کر آتا۔
ایک سال وہ آیا تو اس کے گالوں پر بال آگئے تھے، میں حیرت زدہ رہ گئی اور تم یقین کرو، غم زدہ بھی ہوئی، کیا یہی میرا ننھا سا منا سا بچہ ہے، میری کوکھ سے جنم لینے والا جس کے سر پر ملائم ملائم گھنگریالے بال تھے۔ میرا پیارا بیٹا، میرے جگر کا ٹکڑا جسے میں ایک کپڑے میں لپیٹ کر اپنے گھٹنوں پر سلاتی تھی، یہ طویل قامت نوجوان نہیں جانتا کہ اپنی ماں کو کیسے پیار کیا جاتا ہے، ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہ مجھ سے صرف اس لیے محبت کرتا ہے کہ یہ اس کا فرض ہے۔
ذرا غور کرو، وہ اپنی ماں سے محبت ایک ڈیوٹی سمجھ کر کرتا تھا، وہ مجھے ماں کہہ کر صرف اس لیے پکارتا تھا کہ یہی روایت تھی۔
میرے شوہر کا انتقال ہوگیا، پھر میرے ماں باپ کی باری آئی، پھر میں اپنی دو بہنوں سے ہاتھ دھو بیٹھی، موت کسی گھر میں داخل ہوتی ہے تو کوشش کرتی ہے کہ جلد از جلد زیادہ سے زیادہ کام ختم کرلے تاکہ پھر ایک طویل مدت تک اسے دوبارہ نہ آنا پڑے۔ پورے خاندان میں وہ صرف ایک یا دو افراد اس لیے زندہ چھوڑ جاتی ہے کہ وہ اپنے پیاروں کی یاد میں زندگی بھر روتے رہیں۔
”میں بھی تنہا زندہ رہی، میرا جوان بیٹا بہت فرض شناس تھا۔ میں اس کے پاس چلی گئی، لیکن اب وہ ایک نوجوان مرد تھا، اس کے اپنے مشاغل تھے، اپنی مصروفیات تھیں، اس نے مجھے یہ احساس دلانا شروع کردیا کہ میں اس کے ساتھ رہ کر اس کے لیے مشکلات پیدا کرتی ہوں۔ آخر میں وہاں سے لوٹ آئی۔ اس کے بعد میں نے اسے زیادہ نہیں دیکھا، نہ دیکھنے کے برابر دیکھا۔
”اس نے شادی کرلی، میں بہت خوش تھی۔ ماں بھی عجیب ہوتی ہے۔ اولاد کی طرف سے ہمیشہ خوش فہمی میں مبتلا رہتی ہے۔ مجھے خیال ہوا کہ اب ہم پھر ایک ساتھ رہ سکیں گے، میں اپنے پوتے، پوتیوں کے ساتھ کھیلوں گی، ننھے ننھے گلابی گلابی روئی کے گالے اپنی گود میں پروان چڑھاﺅں گی۔
میں وہاں پہنچی اس کی بیوی ایک انگریز لڑکی تھی، وہ روز اول سے مجھے ناپسند کرتی تھی۔ کیوں؟ شاید اس لیے کہ وہ سمجھتی تھی کہ میں اس کے شوہر کو اس سے زیادہ چاہتی ہوں اس طرح ایک دفعہ پھر مجھے اس کے گھر سے نکلنا پڑا، میں ایک بار پھر تنہا رہ گئی، ہاں موسیو! میں ایک بار پھر بالکل تنہا رہ گئی تھی۔
پھر وہ انگلستان چلا گیا، اپنی بیوی کے والدین کے پاس، وہ ان لوگوں کے ساتھ رہنے لگا۔ میں نے حسرت سے سوچا اب وہ ان کا ہو کر رہے گا جیسے وہ میرا نہیں ان کا بیٹا ہو، انھوں نے اسے مجھ سے چھین لیا، چرا لیا، وہ وہاں سے ہر ماہ مجھے خط لکھتا، شروع شروع میں کبھی کبھی وہ مجھ سے ملنے بھی آتا، لیکن اب اس نے آنا بالکل چھوڑ دیا ہے۔
”اب مجھے اپنے بیٹے کو دیکھے ہوئے چار سال ہوچکے ہیں۔ آخری بار جب میں نے اسے دیکھا تھا تو اس کے چہرے پر جھریاں سی پڑنے لگی تھیں اور بالوں میں کہیں کہیں سفیدی جھلکنے لگی تھی، میں اسے اس حال میں دیکھ کر حیران رہ گئی تھی، کیا یہ ممکن ہے؟ کیا یہ آدمی، یہ تقریباً بوڑھا آدمی میرا بیٹا ہے! ماضی کا چھوٹا سا گلابی گلابی گل گوتھنا سا۔
”اب میں شاید اسے کبھی نہ دیکھ سکوں۔ اب میں اپنا تمام وقت سفر میں گزارتی ہوں، کبھی مشرق میں، کبھی مغرب میں، بالکل تنہا جیسے تم دیکھ رہے ہو۔“
اس نے مجھ سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا۔ ”گڈ بائی موسیو!“ مجھے رخصت کر کے وہ وہیں راستے میں کھڑی رہ گئی، میں خاموشی سے آگے بڑھ گیا، کچھ دور جانے کے بعد میں نے مڑ کر دیکھا وہ ایک ٹیلے پر کھڑی دور افق میں دیکھ رہی تھی، جیسے کچھ تلاش کررہی ہو، تیز ہوا سے اس کے کندھے پر پڑی ہوئی شال کا ایک سرا اور اس کا اسکرٹ کسی جھنڈے کی طرح لہرا رہا تھا۔
( فرانسیسی ادیب موپساں کی کہانی کا اردو ترجمہ)