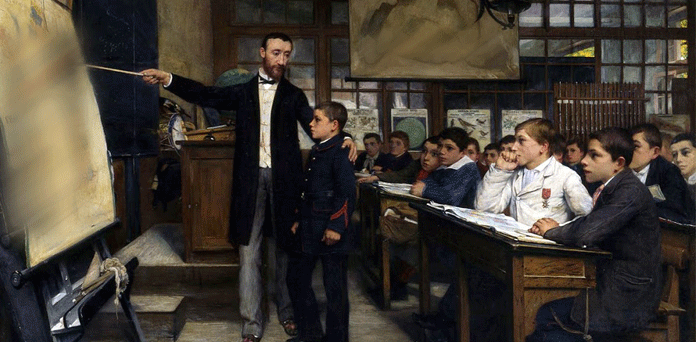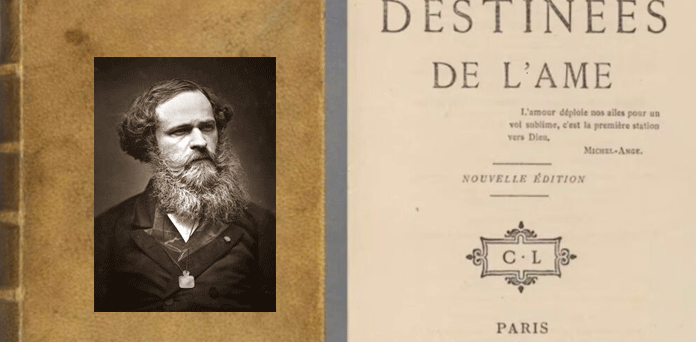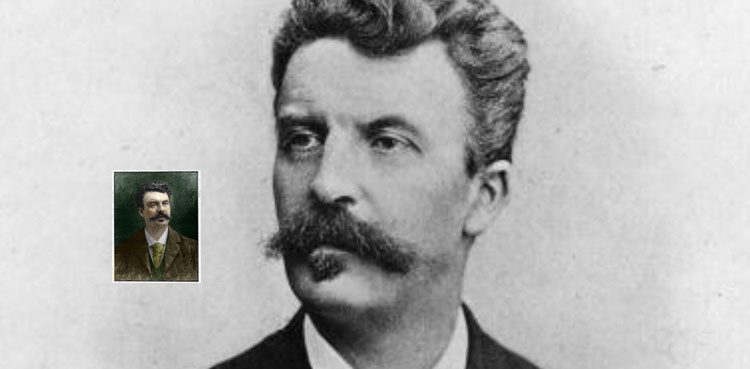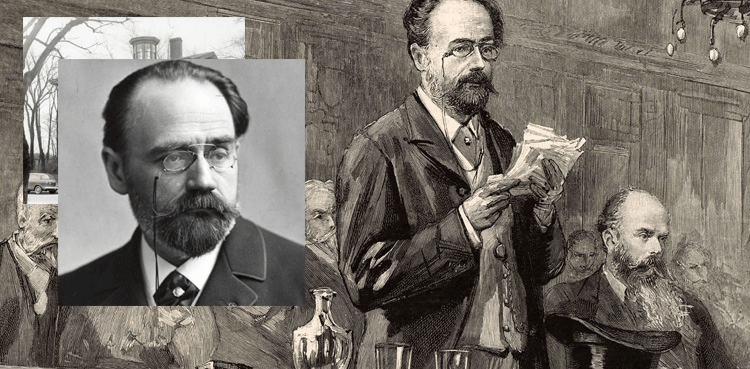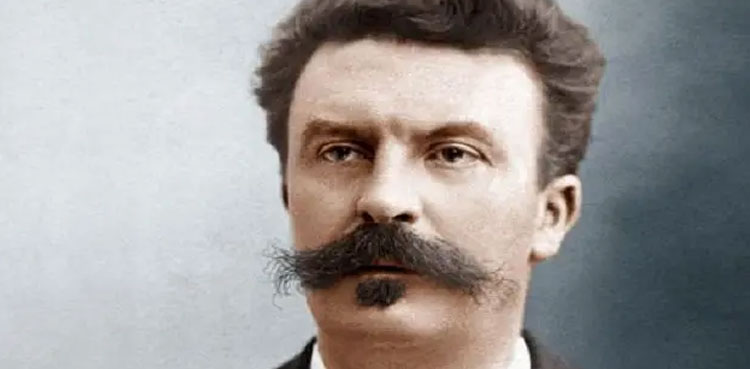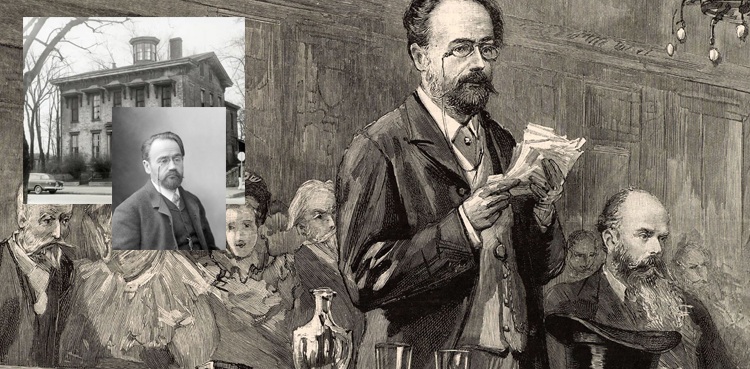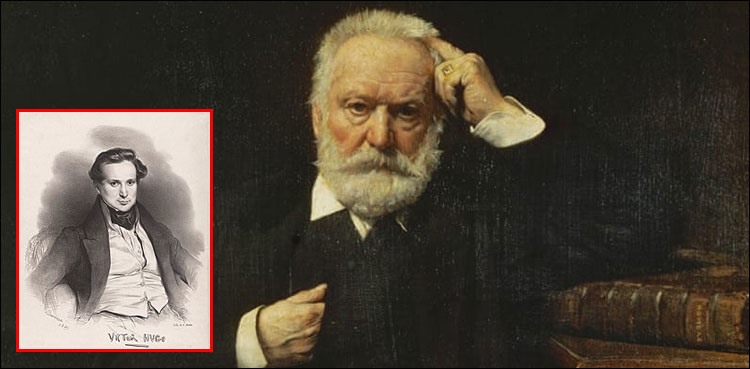الفونزے ڈاؤڈٹ (Alphonse Daudet) نے افسانے اور ناول بھی لکھے، شاعری بھی کی۔ فرانس کا یہ ادیب اور شاعر 1897ء میں چل بسا تھا۔
ڈاؤڈٹ کی ایک کہانی کا اردو ترجمہ ہم یہاں بعنوان آخری جماعت نقل کررہے ہیں۔ اسے منور آکاش نے اس قالب میں ڈھالا ہے۔ کہانی پڑھیے۔
اس صبح مجھے اسکول سے خاصی تاخیر ہو چکی تھی، اور میں ڈانٹ ڈپٹ سے ڈرا ہوا تھا۔ خاص طور پر سَر ہامل نے کہا ہوا تھا کہ وہ اسم، صفت اور فعل کا امتحان لیں گے، اور مجھے ان کے بارے میں ٹھیک سے پتا نہیں تھا۔
ایک لمحے کے لیے میں نے اسکول سے دور رہنے اور کھیتوں میں آوارہ گردی کا سوچا، میں یہ سب اس لیے کرنا چاہتا تھا کہ امتحان سے بچ سکوں مگر میرے اندر مزاحمت کی طاقت نہیں تھی اور میں اتنی تیزی سے اسکول کی طرف دوڑا جتنا تیز میں چل سکتا تھا۔
میں کوتوال کے دفتر کے پاس سے گزرا تو دیکھا یہاں چند لوگ ایک بورڈ کے گرد جمع تھے جس پر نوٹس آویزاں کیا گیا تھا۔ گزشتہ دو سال سے ہماری تمام بری خبریں اسی بورڈ پر آویزاں کی جاتی تھیں۔ ”ہم جنگ ہار گئے“ ہیڈ کوارٹر کی طرف سے فوج میں جبری بھرتی کا حکم، میں نے بغیر رکے سوچا، ”اب کیا ہو گا؟“ پھر جب میں دوڑتے ہوئے چوک کے پاس سے گزرا۔
ایک محافظ لوہار نے جو اپنے شاگردوں کے ساتھ کھڑا ”اعلان“ پڑھ رہا تھا مجھے پکار کر کہا۔ ”بچے…. اتنی جلدی نہ کرو، تم جلد ہی اسکول پہنچ جاؤ گے۔“
میں نے سوچا وہ مذاق کر رہا ہے۔ میں دوڑا سَر ہامل کے چھوٹے سے حصے کی طرف جو اسکول میں اس کے لیے وقف تھا۔ پھولی ہوئی سانس کے ساتھ۔ عام طور پر اسکول کے آغاز کے وقت بہت شور ہوتا تھا جو گلیوں میں بھی سنائی دیتا۔ ڈیسک کھلنے اور بند ہونے کی آوازیں، اکٹھے ہو کر سبق دہرانے کی آوازیں، ہمارے کان اس کے عادی ہو چکے تھے اور استاد کا بید جسے وہ ڈیسک پر مارتے رہتے۔
”ایک دم خاموشی؟“ عام دنوں میں، مَیں اپنے ڈیسک تک پہنچنے تک اس شور پر زیادہ توجہ نہیں دیتا تھا۔ مگر اس دن مکمل خاموشی تھی۔ ایک اتوار کے دن کی طرح۔
اگرچہ میں دیکھ سکتا تھا کمرے کی کھڑکیوں سے کہ میرے ساتھی اپنی جگہوں پر پہلے ہی بیٹھے تھے اور سَر ہامل کمرے میں چہل قدمی کر رہے تھے۔ ایک آہنی رولر اپنی بغل میں دبائے۔ میں نے دروازہ کھولا اور اس مکمل خاموشی کے ماحول میں داخل ہو گیا۔
سَر ہامل نے میری طرف دیکھا، ان کی نظر میں غصہ نہیں تھا بہت تحمل تھا۔
”فوراً اپنی نشست پر پہنچ جاؤ میرے چھوٹے، ہم تمہارے بغیر ہی شروع کرنے والے تھے۔“
میں نشست کی طرف بڑھا اور فوراً بیٹھ گیا۔ اس وقت تک میں اپنی گھبراہٹ پر جزوی طور پر قابو پا چکا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ ہمارا استاد آج اپنا خوب صورت نیلا کوٹ پہنے ہوئے ہے۔ دھاری دار گلو بند اور سیاہ ریشمی کڑھائی والا پاجامہ جسے وہ صرف ان دنوں میں پہنتے جب تقسیمِ انعامات کا موقع ہوتا یا اسکول کے آغاز کا دن۔
اس کے علاوہ جماعت میں گہری سنجیدگی تھی مگر میرے لیے سب سے حیرانی کا باعث کمرے کا وہ پچھلا حصہ تھا جو عام طور پر خالی رہتا تھا۔ وہاں گاؤں کے چند لوگ بیٹھے تھے، اتنے ہی خاموش جتنے ہم۔
تین کونوں والے ہیٹ پہنے معزز بزرگ، سابق کوتوال، سابق پوسٹ ماسٹر اور ان کے ساتھ اور لوگ۔ وہ سب پریشان لگ رہے تھے۔ اور معززین کے پاس پرانے ہجوں والی ایک کتاب تھی جس کے کونے کُترے ہوئے تھے۔ جسے ان میں سے ایک نے اپنے گھٹنوں پر کھول کر رکھا ہوا تھا اور اپنی عینک کو ترچھا کیا ہوا تھا۔
اسی دوران جب میں اس سب پر حیران ہو رہا تھا، سَر ہامل نے آغاز کیا اور یہ اتنا ہی تحمل آمیز اور سنجیدہ آواز میں تھا جسے انہوں نے مجھے خوش آمدید کہتے ہوئے اپنایا تھا۔ انہوں نے ہم سے کہا۔
”میرے بچو! یہ آخری دفعہ ہے جب میں تمہیں پڑھاؤں گا۔ برلن سے حکم آیا ہے کہ السیشن اور لوریانی میں جرمن زبان کے علاوہ کسی اور زبان میں کچھ نہ پڑھایا جائے۔ نیا استاد کل آ جائے گا۔ فرانسیسی کی یہ آخری جماعت ہے۔ تو میری درخواست ہے بہت توجہ سے سنو۔“
ان چند الفاظ نے مجھے مغلوب کر دیا۔ اچھا یہ وہ بدمعاشی تھی جو کوتوالی کے دفتر کے سامنے آویزاں تھی۔
”فرانسیسی میں میری آخری جماعت!“
میں ابھی ٹھیک سے لکھنا نہیں جانتا تھا، تو میں نہیں سیکھ سکوں گا۔ میں یہیں رک جاؤں گا جہاں میں ہوں۔ میں اپنے سے بہت ناراض تھا کہ میں نے کتنا وقت ضایع کیا۔ وہ سبق جو میں نے چھوڑ دیے۔ گھونسوں کے پیچھے بھاگتے، سارا دن دریا میں پھسلتے ہوئے گزار دیا۔
بیچارہ! یہ آخری سبق کا تقدس تھا کہ اس نے یہ لباس پہننا تھا اور اب مجھے گاؤں کے ان معززین کی کمرے میں موجودگی بھی سمجھ آ گئی۔ ایسا لگتا تھا انہیں کبھی کبھی اسکول نہ آنے کا پچھتاوا تھا۔ ہمارے استاد کی ایمان دارانہ چالیس سال کی نوکری کا شکریہ ادا کرنے کا ایک طریقہ تھا اور اجداد کی سرزمین کو عزت دینے کا جو اب برباد ہو رہی تھی۔
میں انہی خیالات میں گم تھا کہ مجھے اپنا نام پکارنے کی آواز آئی۔ یہ میری سبق کی قرأت کرنے کی باری تھی۔ میں اسم کی حالتوں کے اصولوں کو شروع سے آخر تک پڑھنے کے قابل نہیں تھا۔ اونچی آواز میں بغیر اٹکے۔ لفظوں کو پہلے لفظوں سے ملا جلا دیا اور اپنی نشست پر کھڑا جھوم رہا تھا، بھاری دل کے ساتھ سر اٹھانے سے خائف۔ میں نے سر ہامل کو کہتے سنا۔
”میں تمہیں ماروں گا نہیں۔ میرے چھوٹے فرانٹز۔ تم بہت سزا بھگت چکے۔ ایسے ہی ہر دن ہم خود سے کہتے ہیں کہ ابھی کافی وقت ہے۔ میں اسے کل یاد کر لوں گا۔ اور پھر تمہیں پتا ہے کیا ہوتا ہے؟“
آہ ہمارے السیشنوں کی یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم آج کا سبق کل پر ڈال دیتے ہیں۔ اب وہ لوگ ہمارے بارے میں کہتے ہیں۔ ”تم فرانسیسی ہونے کا دعویٰ کیسے کرو گے؟، تم فرانسیسی زبان نہ بول سکتے ہو نہ پڑھ سکتے ہو۔ اس صورت حال میں پیارے فرانٹرز صرف تم نادم نہیں ہو۔ اپنے آپ کو مخاطب کریں تو ان ملامتوں میں ہم سب حصہ دار ہیں۔“
ایک بات سے دوسری بات نکالتے سر ہامل نے فرانسیسی زبان کے بارے میں گفتگو شروع کی۔ انہوں نے کہا یہ دنیا میں خوب صورت ترین زبان تھی۔ نہایت صاف، برقرار رہنے والی، ہم اسے یاد رکھتے ہیں اور کبھی نہیں بھولتے۔“ اس کے بعد سر نے گرامر کی کتاب اٹھائی اور ہمارا سبق پڑھا۔
میں حیران ہوا کہ کتنی آسانی سے میری سمجھ میں آ گیا۔ جو کچھ انہوں نے کہا مجھے نہایت آسان محسوس ہوا۔ بہت آسان۔ میں جانتا ہوں کہ پہلے میں نے اتنے غور سے نہیں سنا اور یہ ان کی وجہ سے بھی تھا کہ اس سے پہلے انہوں نے سمجھاتے وقت اتنے تحمل کا مظاہرہ نہیں کیا۔ ایسا کہا جا سکتا ہے کہ بیچارہ استاد جاتے ہوئے ہمیں سارا علم سونپنے کی خواہش رکھتا ہے۔ ایک ہی پھونک سے ہمارے ذہنوں میں بھرنا چاہتا ہے۔
جب سبق ختم ہوا ہم لکھنے کی طرف آئے اور اس دن سَر کچھ بالکل ہی نئی مثالیں تیار کر کے لائے تھے، جو انہوں نے خوشخط کر کے لکھیں۔
اسکول کی چھت پر کبوتر آہستگی سے بول رہے تھے اور میں نے اپنے آپ سے کہا جیسے میں نے ان کو سنا۔
دیر بہ دیر جب بھی میں نے کاغذ سے نظریں اٹھائیں میں نے سر ہامل کو کرسی پر ساکت بیٹھے پایا۔ سب چیزوں کو گھورتے ہوئے جیسے وہ اپنے ساتھ اس چھوٹے سے اسکول کو بھی اٹھا لے جانا چاہتے ہیں۔
ذرا سوچو! چالیس سال سے وہ یہاں ہیں۔ اس کی بہن کمرے میں چکر کاٹ رہی ہے اور سامان باندھ رہی ہے کیوں کہ کل انہوں نے جانا ہے۔ اس خطے سے ہمیشہ کے لیے۔ تاہم ان میں آخر تک جماعت کو پڑھانے کی ہمت تھی۔ لکھنے کے بعد وہ تاریخ کے مضمون کی طرف آئے اور تمام چھوٹے بچوں نے مل کر گایا با…. بی…. بی…. بو…. بو…. وہاں کمرے کے پچھلے حصے میں بوڑھے معززین نے اپنی عینکیں پہن لیں اور قدیم ہجوں والی کتاب کو دونوں ہاتھوں سے تھام لیا۔ انہوں نے بھی بچوں کے ساتھ ہجے کرتے ہوئے آواز ملائی۔ میں نے دیکھا سر بھی اپنی آواز ساتھ ملا رہے تھے۔ ان کی آواز جذبات سے بھرا گئی۔ اور میرے لیے ان کو ایسے دیکھنا ایک مزاحیہ بات لگ رہی تھی۔ ہم سب ہنس رہے تھے، رو رہے تھے، آہ…. میں اس آخری جماعت کو ہمیشہ یاد رکھوں گا۔
اچانک گرجے کی گھڑی نے بارہ بجائے، دعا پڑھی گئی۔ سر ہامل موت کی طرح زرد، اپنی کرسی سے اٹھے، اس سے پہلے وہ مجھے کبھی اتنے لمبے محسوس نہیں ہوئے۔
”میرے دوستو“ انہوں نے کہا…. ”میرے دوستو، میں …. میں ….“ مگر کسی چیز نے ان کی آواز کو گھوٹ دیا۔ وہ اپنا جملہ مکمل نہ کر سکے۔
وہ تختۂ سیاہ کی طرف بڑھے، چاک کا ایک ٹکڑا اٹھایا، اور اپنی تمام ہمت جمع کر کے اتنے بڑے حروف میں لکھا جتنا وہ لکھ سکتے تھے۔
”فرانس دائم آباد“
پھر وہ اپنا سر دیوار کے ساتھ لٹکائے وہاں کھڑے رہے، بغیر کچھ بولے۔ انہوں نے ہمیں اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا، ”بس…. اب جاؤ۔“