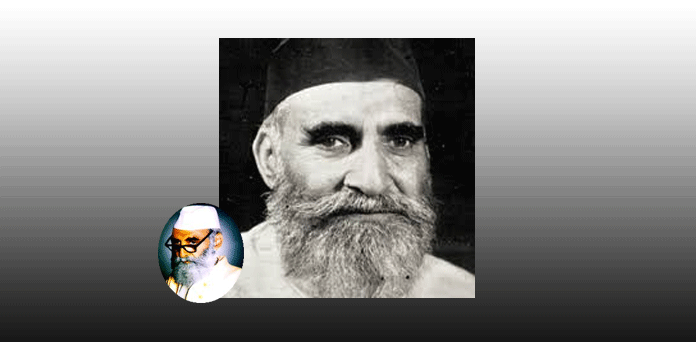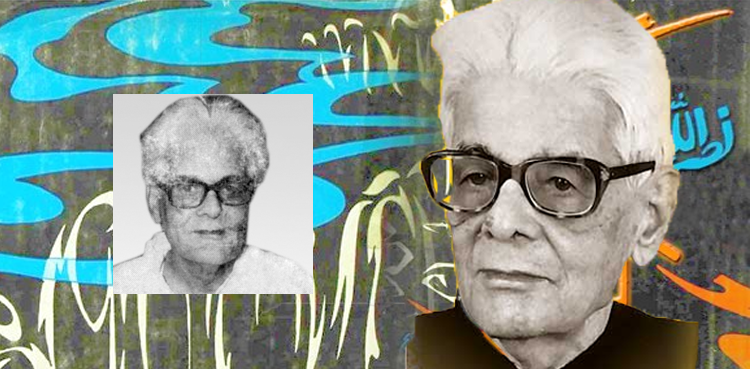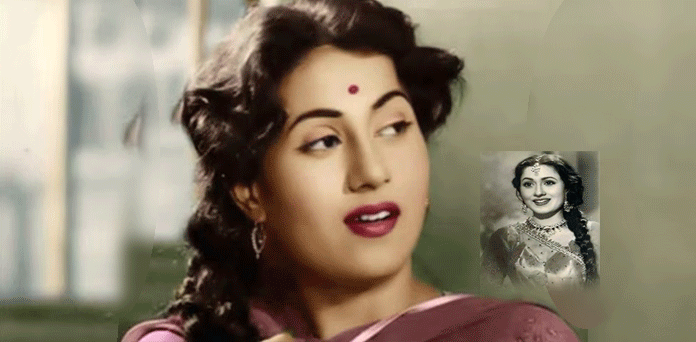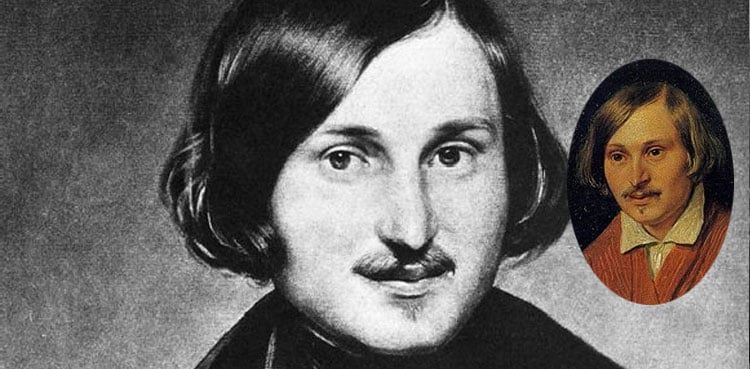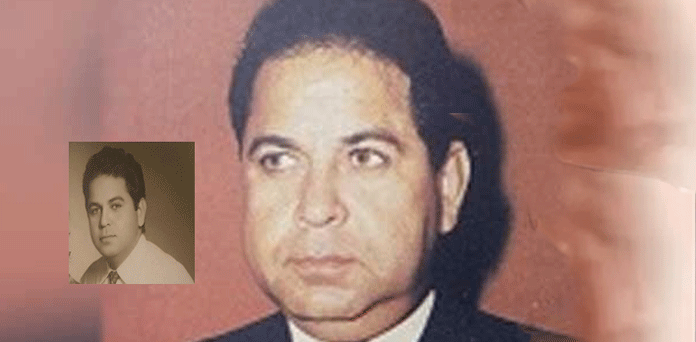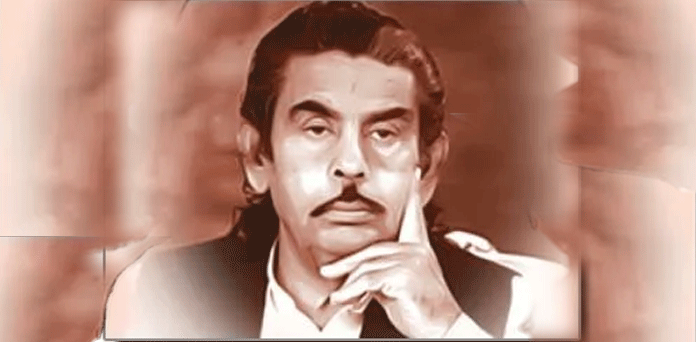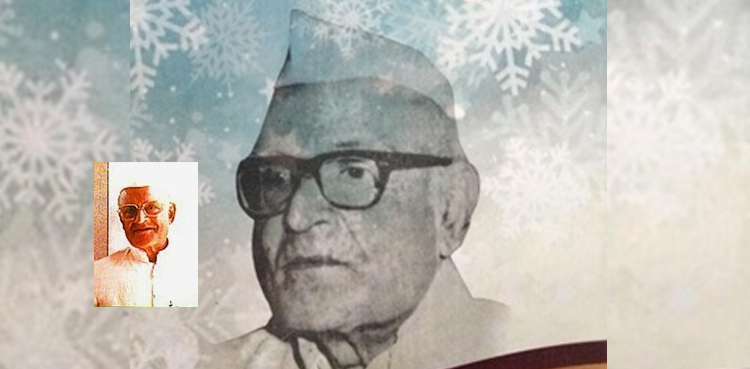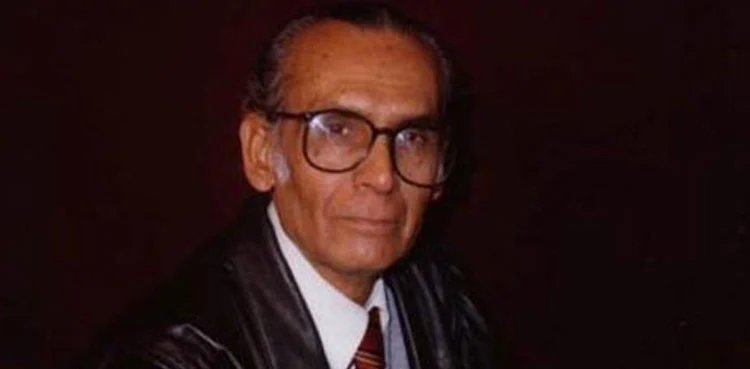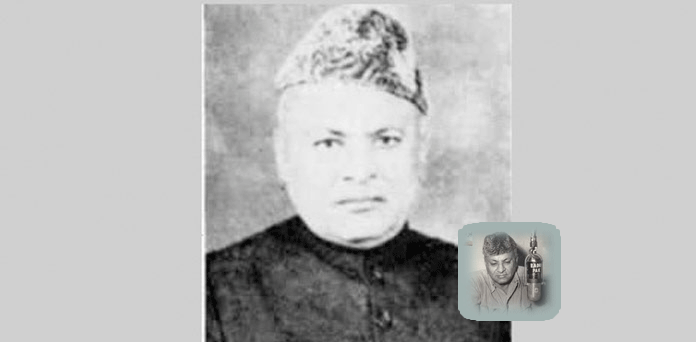صہباؔ اختر کے اشعار آج شاید ہی ادب اور شاعری کا شغف رکھنے والے کسی نوجوان کو یاد ہوں اور بہت ممکن ہے کہ اکثریت ان کے نام سے بھی واقف نہ ہو، لیکن یہ تعجب خیز بھی نہیں۔ آج نئی نسل کے لیے کئی نام نئے ہیں کہ یہ یہی وقت کی گردش اور الٹ پھیر ہے، لیکن تقسیمِ ہند کے بعد پاکستان میں جو شاعر مشہور ہوئے، ان میں صہبا صاحب کا نام ضرور شامل ہے۔ انھیں شاعرِ پاکستان بھی کہا گیا اور یہ ان کا امتیاز ہے۔
صہبا اختر کو مشاعرہ پڑھنے کے ان کے خاص انداز کی وجہ سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ جو طنطنہ، رعب اور گھن گرج ان کی آواز میں تھی، وہ انہی سے مخصوص ہے۔ ان سے پہلے اور ان کے بعد کوئی اس لحن میں غزل یا نظم نہیں پڑھ سکا۔ آج اردو کے ممتاز شاعر صہبا اختر کا یومِ وفات ہے۔
صہبا اختر نے غزل کے علاوہ حمد و نعت، مرثیہ گوئی، دوہے، رباعی جیسی اصنافِ سخن میں طبع آزمائی کی اور گیت نگاری کے ساتھ ان کی ملّی شاعری نے انھیں بڑی شہرت دی۔ صہبا اختر کے مجموعہ ہائے کلام میں اقرا، سرکشیدہ، سمندر اور مشعل شامل ہیں۔ بعد از مرگ صہبا صاحب کے لیے صدارتی تمغا برائے حسنِ کارکردگی کا اعلان کیا گیا تھا۔
صہبا صاحب کو غزل اور نظم گوئی میں کمال و شہرت نصیب ہوئی۔ ان کی بیشتر نظمیں وطن سے محبت اور اس مٹی سے پیار کا والہانہ اظہار ہیں۔ اس کے ساتھ وہ ان مسائل کو بھی شاعری میں خوب صورتی اور شدت سے بیان کرتے ہیں کہ جو ان کی نظر میں وطن کی صبحِ درخشاں کو تیرگی اور تاریکی کا شکار کرسکتے ہیں۔ ان کا لحن اور جذبہ ان کی شاعری میں دو آتشہ کی کیفیت پیدا کرتے ہیں۔
صہباؔ اختر کا اصل نام اختر علی رحمت تھا۔ وہ 30 ستمبر 1931ء کو جموں میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد منشی رحمت علی اپنے زمانے کے ممتاز ڈراما نگاروں میں شمار ہوتے تھے۔ یوں انھیں شروع ہی سے علمی و ادبی ماحول ملا اور صہبا اختر کم عمری میں شعر کہنے لگے۔ انھوں نے بریلی سے میٹرک کا امتحان پاس کیا تھا، علی گڑھ سے بی اے کی سند لی اور قیامِ پاکستان کے بعد کراچی آگئے۔ ہجرت کے بعد ان کے خاندان نے نامساعد حالات کا سامنا کیا، یہاں صہبا اختر کو بالآخر محکمۂ خوراک میں ملازمت مل گئی اور اسی محکمے سے ریٹائر ہوئے۔
احمد ندیم قاسمی نے اپنے مضمون میں صہباؔ صاحب کے بارے میں لکھا تھا:’’صہبا اختر کے ہاں جذبے اور احساس کے علاوہ ملکی اور ملی موضوعات کا جو حیرت انگیز تنوع ہے وہ انھیں اپنے معاصرین میں بہرحال ممیز کرتا ہے۔ نظم ہو یا غزل مثنوی ہو یا قطعہ وہ اپنے موضوع میں ڈوب کر اس کے آفاق پر چھا کر شعر کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے کلام میں قاری یا سامع کے دل و دماغ کو اپنی گرفت میں لینے کی جو توانائی ہے، وہ اس دور میں بے مثال کہی جا سکتی ہے۔ بظاہر وہ بلند آہنگ شاعری کرتے ہیں لیکن اس طرح کا خیال عموماً ان لوگوں کا ہوتا ہے جنھوں نے صہبا اختر کو مشاعروں میں پڑھتے سنا مگر ان کے کلام کے مطالعے سے محروم ہیں۔ یہی احباب صہبا اختر کے کلام کو یکجا دیکھیں گے تو انھیں معلوم ہو گا کہ یہ شاعر جو مشاعروں میں گرجتا اور گونجتا ہے اپنے کلام کی گہرائیوں میں کتنا اداس اور تنہا ہے۔ ‘‘
صہبا صاحب کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ اپنے آپ میں گم رہنے والے، نہایت کم گو تھے اور دوسروں کے متعلق یا اپنے ہم عصر شعراء کی عیب جوئی یا کسی پر نکتہ چینی کبھی نہیں کرتے تھے۔
ایک مشاعرے کا احوال اور صہبا صاحب کا یہ تذکرہ پڑھیے: ’’غالباً 1955ء کا ذکر ہے، نواب شاہ میں ایک بڑے مشاعرے کا انعقاد ہوا۔ کراچی سے شرکت کرنے والوں میں ایک چھیل چھبیلا جوان العمر شاعر بھی تھا۔ گھنے گھنے، گھنگریالے سیاہ اور چمکتے دمکتے بال، گول مٹول سا بھرا بھرا چہرہ، خمار آلود شربتی آنکھیں، ستواں ناک، متناسب لب اور دل کش قد و قامت کے ساتھ ساتھ تنومند جسم پر ململ کا کڑھا ہوا کرتا اور صاف و شفاف لٹھے کا ڈھیلا پاجامہ۔ یہ تھی صہبا اختر کی سج دھج، جنھوں نے اپنی باری آنے پر بڑی لمبی بحر کی غزل چھیڑی اور وہ بھی منجھے ہوئے ترنم سے۔ حاضرین منتظر ہیں کہ ذرا کہیں رکیں تو داد و تحسین سے نوازے جائیں۔ اُدھر بھائی صہبا اختر کی محویت کا یہ عالم کہ جیسے ایک ہی سانس میں پوری غزل سنا ڈالیں گے۔ مسئلہ پوری غزل کا نہیں بلکہ مطلع ہی ایسی بحرِ طویل کو تسخیر کر رہا تھا کہ سانس لینے کی فرصت کسے تھی۔ بہرکیف غزل خوب جمی اور داد بھی بہت ملی۔
صہبا اختر کی غزل ملاحظہ کیجیے۔
چہرے شادابی سے عاری آنکھیں نور سے خالی ہیں
کس کے آگے ہاتھ بڑھاؤں سارے ہاتھ سوالی ہیں
مجھ سے کس نے عشق کیا ہے کون مرا محبوب ہوا
میرے سب افسانے جھوٹے سارے شعر خیالی ہیں
چاند کا کام چمکتے رہنا اس ظالم سے کیا کہنا
کس کے گھر میں چاندنی چھٹکی کس کی راتیں کالی ہیں
صہباؔ اس کوچے میں نہ جانا شاید پتّھر بن جاؤ
دیکھو اس ساحر کی گلیاں جادو کرنے والی ہیں
صہبا اختر ایک عرصہ تک ریڈیو پاکستان کے لیے بھی پابندی سے لکھتے رہے۔ ان کے تحریر کردہ فلمی گیت بہت مقبول ہوئے۔ ان کے گیتوں میں اک اڑن کھٹولا آئے گاایک لال پری کو لائے گا، دنیا جانے میرے وطن کی شان، چندا تجھ سے ملتا جلتا اور بھی تھا اک چاند، پریتم آن ملو، تنہا تھی اور ہمیشہ سے تنہا ہے زندگی اور چاند کی سیج پہ تاروں سے سجا کر سہرا شامل ہیں۔
صہباؔ اختر 19 فروری 1996ء کو انتقال کرگئے تھے۔ انھیں کراچی میں گلشنِ اقبال کے ایک قبرستان میں سپردِ خاک کیا گیا۔