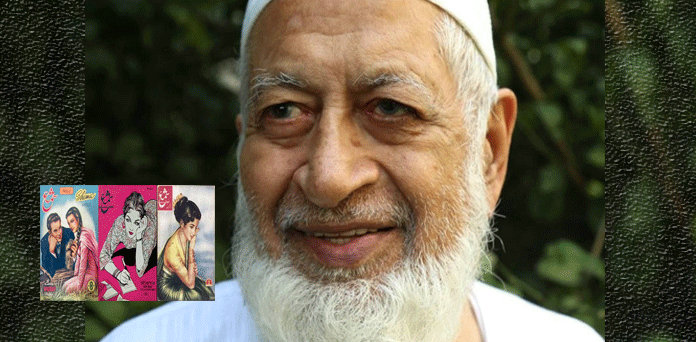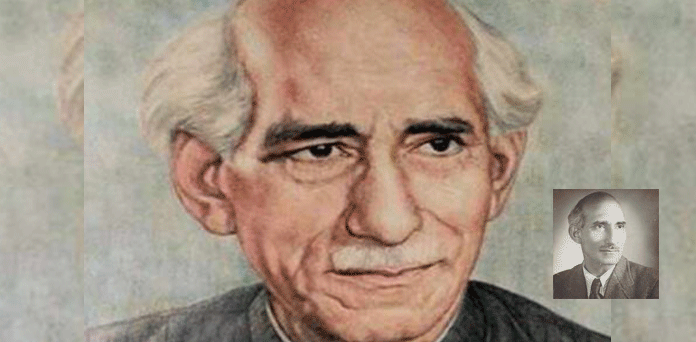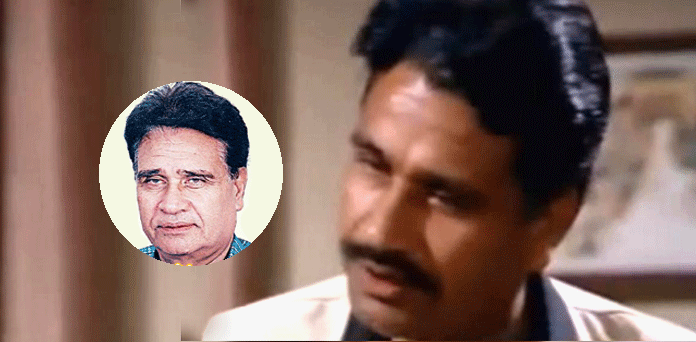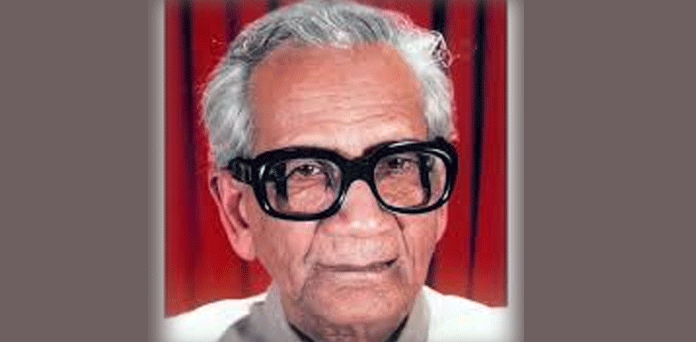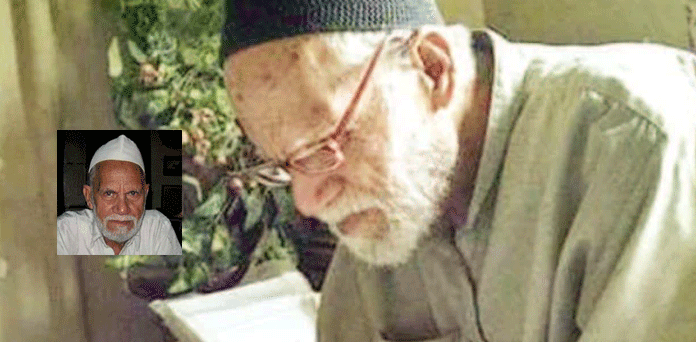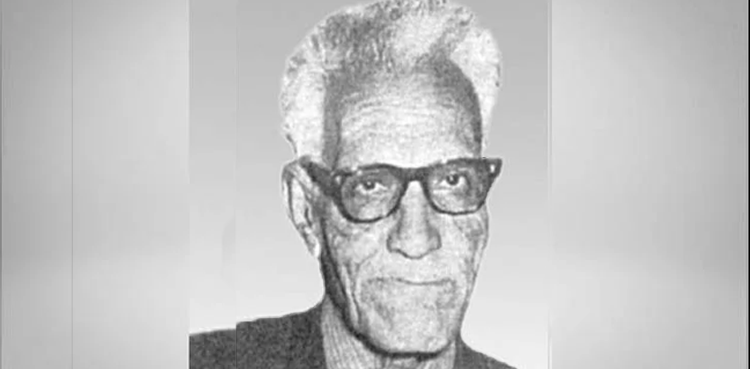اردو دنیا میں ادیب، شاعر اور دیگر اہلِ قلم اپنی تحریروں اور تصانیف کی وجہ سے شہرت اور مقام حاصل کرتے ہیں اور ان کے گزر جانے کے بعد بھی ان کا ذکر کیا جاتا ہے، لیکن بہت کم ناشر و مدیر ایسے ہیں جنھیں یونس دہلوی کی طرح سراہا گیا ہے۔ یونس دہلوی بھارت کے سب سے بڑے اور مقبول ترین اردو رسائل کے سلسلے کے ناشر اور مدیر تھے۔ وہ ایک عام ناشر اور مدیر نہیں تھے بلکہ فلمی دنیا کے کئی ستارے اور اہلِ قلم یونس دہلوی کے حلقۂ احباب میں شامل رہے۔
یونس دہلوی کی برسی کی مناسبت سے آج یہ تحریر قارئین کے لیے پیش کی جارہی ہے۔ ہم آغاز کریں گے عظیم اختر کے یونس دہلوی سے متعلق مضمون کے ابتدائیہ سے جس میں وہ رقم طراز ہیں: "یونس دہلوی نے اردو رسائل و جرائد کی دنیا میں معمّوں کی ابتدا کر کے ایک ماہرِ نفسیات کی طرح مالی بحران اور اقتصادی شکنجوں میں جکڑے ہوئے اردو داں طبقے پر ایک حربہ آزمایا اور معمے بھر کر آسانی کے ساتھ دولت حاصل کرنے کی عام انسانی خواہش کو جگا دیا۔”
یونس دہلوی جس اشاعتی ادارہ کے مالک تھے، اس کی بنیاد تقسیمِ ہند سے قبل ان کے والد یوسف دہلوی نے رکھی تھی۔ یونس دہلوی کے زیرِ نگرانی شمع پبلشنگ ہاؤس کے تحت مقبولِ عام فلمی رسالہ شمع ہی نہیں کھلونا، بانو، شبستان جیسے رسائل کی اشاعت کئی سال جاری رہی۔ یہ رسائل بھارت کے علاوہ پاکستان اور ریاست ہائے متحدہ امریکا میں بھی خریداروں تک پہنچتے تھے اور لاکھوں کی تعداد میں ان کی اشاعت ہوتی تھی۔ شمع وہ رسالہ تھا جو ہر خاص و عام میں مقبول تھا۔ بالی وڈ کی مشہور شخصیات جن میں دلیپ کمار، اشوک کمار، راج کمار، آشا پاریکھ، نوتن، نرگس، راج کمار، سنجیو کمار، محمد رفیع، ملکہ پکھراج اور فلمی دنیا کے کئی چہرے یونس دہلوی کے احباب میں شامل تھے اور ان کے گھر بھی آنا جانا تھا۔
ناشر و مدیر یونس دہلوی 2019ء میں آج ہی کے روز اس دارِ فانی سے رخصت ہو گئے تھے۔ لیکن ان کا اشاعتی ادارہ 1994ء تک نہایت کام یابی سے چلنے کے بعد خاندان میں اختلافات کے بعد بکھر چکا تھا۔ یونس دہلوی کو کئی اعزازات سے نوازا گیا۔ وہ بھارت اور اردو دنیا کی ایک مشہور شخصیت رہے۔ عظیم اختر لکتے ہیںکہ رسالہ شمع کی مقبولیت کا راز وہ معّمے اور ذہنی آزمائش کے سلسلے تھے جو یونس دہلوی کے ذہن کی اختراع تھے۔ وہ لکھتے ہیں:
"لفظوں کی سانپ سیڑھی کے اس کھیل میں خطیر رقموں کے انعامات کی پرکشش اور ترغیب دلانے والی پیش کش نے دیکھتے ہی دیکھتے ہزاروں لوگوں کو اپنے سحر میں جکڑ لیا اور شمع کا سرکولیشن چند ہی سالوں میں ایک لاکھ سے تجاوز کر گیا۔ یہ ماہنامہ "شمع” کے شباب کا دور تھا۔ شمع کے اسی دورِ شباب میں یونس دہلوی نے ماہنامہ "ساقی” کے مدیر جناب شاہد احمد دہلوی کی سنتوں کو تازہ کرتے ہوئے نہ صرف "شمع” میں شائع ہونے والی غزلوں، نظموں اور کہانیوں کے تخلیق کاروں کو بلکہ ‘شمع بک ڈپو’ کی طرف سے شائع ہونے والے ناولوں کے ناول نگاروں کو باقاعدہ رائلٹی دینے کا بھی سلسلہ شروع کیا جس کا اس زمانے میں تصور بھی ممکن نہیں تھا۔”
ماہ نامہ شمع کی اس پذیرائی نے اس دور کے ہر چھوٹے بڑے اور معروف و غیر معروف شاعر اور افسانہ نگار کو شمع کے صفحات میں جگہ پانے کا خواہش مند بنا دیا تھا۔
"تخلیقی کاوشوں پر رائلٹی اور کثیر الاشاعت رسالے میں چھپنے کی للک نے معمے بازی کی دعوت عام دینے والے ماہ نامہ شمع کو فلمی اور نیم ادبی پرچے کا روپ دے دیا تھا۔ معمے چوں کہ خالص یونس دہلوی کے ذہن کی اختراع تھے، اس لیے معمے کی شکل میں لفظوں کی سانپ سیڑھی کے اس کھیل کو مرتب کرنے کے علاوہ شمع میں چھپنے والی کہانیوں کا انتخاب بھی وہ بذاتِ خود کیا کرتے تھے۔ صرف شعری حصّے کی ترتیب کے لیے وہ ایک عرصہ تک ابّا جی مرحوم حضرت مولانا سلیم اختر مظفر نگری کی مدد لیتے رہے لیکن ان کے انتقال کے بعد شعری حصّے کے انتخاب کے لیے ان کی نگاہِ انتخاب جناب بسمل سعیدی ٹونکی جیسے استاد اور کہنہ مشق شاعر پر پڑی۔ یونس دہلوی بذاتِ خود ایک قلم کار اور ادیب نہیں تھے لیکن وہ فلمی ستاروں کی رومانی کہانیاں اور باہمی تعلقات کے لذّت آمیز قصے پڑھنے والوں اور معموں کے شوقین پروانوں کو ذہنی آسودگی پہنچانے والی کہانیوں کے ایک اچھے پارکھ تھے۔”
"معمے کی اختراع نے شمع کو چند ہی سالوں میں کہیں سے کہیں پہنچا دیا لیکن جب لوگوں کو دولت مند بنانے کی اس سہل سے نسخے پر "جوا ایکٹ” (Gamble Act) کی پرچھائیاں پڑیں تو قانونی مجبوریوں کے تحت معمہ بند کرنا پڑا جس کے نتیجے میں سرکولیشن بری طرح متاثر ہوئی۔ مالکان کو اس حقیقت کا ادراک ہوا کہ شمع کی تمام تر مقبولیت اور بڑھتی ہوئی سرکولیشن صرف معموں کی وجہ سے تھی اور معموں کے بغیر شمع اپنے پیروں پر کھڑا بھی نہیں رہ سکتا۔ چنانچہ معموں کے شائقین کو معمے بازی کی ڈور میں پرونے کے لیے ادبی معمّوں کا ڈول ڈالا گیا لیکن یہ ادبی معمّے شمع کے ان معمّوں کا بدل ثابت نہ ہو سکے جس کی وجہ سے شمع شہرت و مقبولیت کی تمام حدوں کو پھلانگ گیا تھا۔”
ان ادبی معمّوں کو جاری رکھنا مالكانِ ‘شمع’ کی کاروباری اور تجارتی مجبوری تھی۔ ہر ماہ غیر معمولی تعداد میں حاصل ہونے والی آمدنی کے قصۂ پارینہ بن جانے کی وجہ سے اخراجات میں کٹوتیوں کا دور شروع ہوا اور مسلسل نقصان کے نام پر آخر ایک دن اردو دنیا میں اپنے انمٹ اور خوب صورت چھاپ چھوڑ کر خاموشی سے "شمع” بند ہو گیا۔
ہندوستان، پاکستان کے اردو رسائل و جرائد کی دنیا میں ہر ماہ ڈیڑھ پونے دو لاکھ کی تعداد میں چھینے اور غیر معمولی شہرت و عوامی مقبولیت کے حامل "شمع” کو فلمی اساس کی وجہ سے صرف پاپولر میگزین کے زمرے میں رکھ کر اس کے شعری و نثری حصے سے ہمیشہ بے اعتنائی برتی گئی۔ حالانکہ یونس دہلوی نے اپنی تمام تر مدیرانہ صلاحیتوں کو بروئے کار لاکر ہمیشہ اچھی خوب صورت شعری و نثری کاوشوں کو شمع کے صفحات میں جگہ دی۔
شمع میں چھپنے والی بہت سی کہانیاں آج اردو ادب کی بہترین اور نمائندہ کہانیوں میں شامل کی جاتی ہیں۔ اسی طرح یونس دہلوی کی زیرِ ادارت شائع ہونے والا ہفت روزہ "آئینہ” اردو دنیا میں اپنی طرز کا پہلا ہفت روزہ تھا جو دیدہ زیب گیٹ اپ اور اپنے مشمولات کے اعتبار سے اردو میں حرفِ اوّل اور حرفِ آخر ثابت ہوا۔
یونس دہلوی نے اپنی نفاست پسندی اور ذوقِ سلیم کی وجہ سے شمع کے ادارے سے نکلنے والے دوسرے ماہ ناموں کو بھی خوب صورت بنانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی لیکن بنیادی طور پر چونکہ ایک تجارتی اور کاروباری ذہن رکھتے تھے، اس لیے معموں کے بند ہونے اور آمدنی کے ذرائع سکڑنے کی وجہ سے اس کاروبار کو خیر باد کہہ کر کاروبار کی ایک نئی دنیا آباد کر لی جہاں گم نامی کے علاوہ کچھ اور نہیں تھا۔