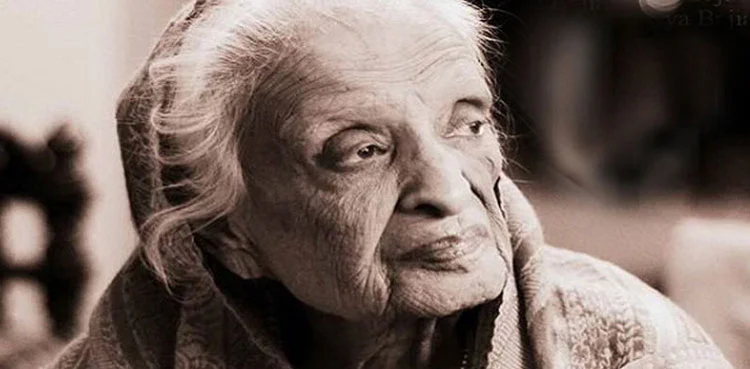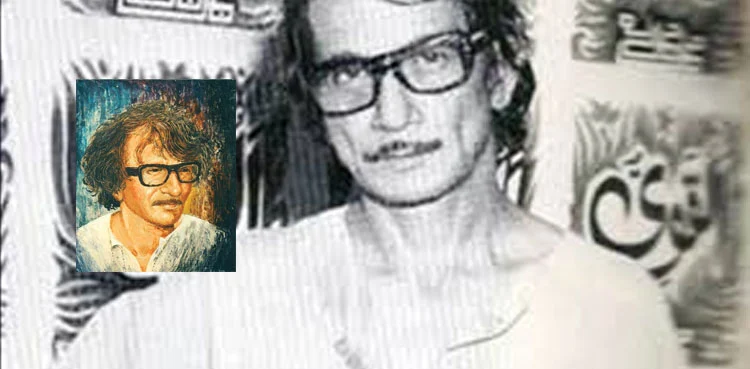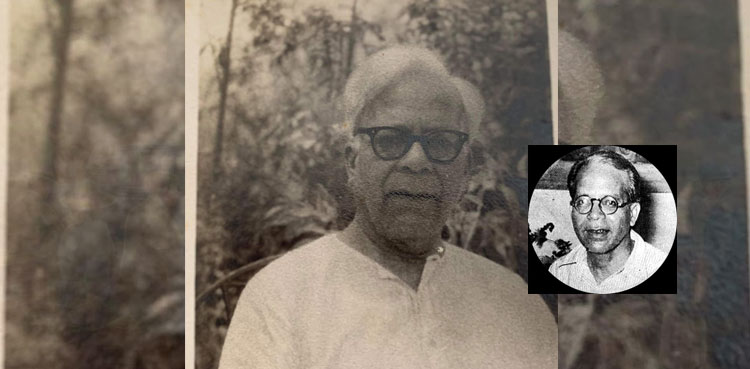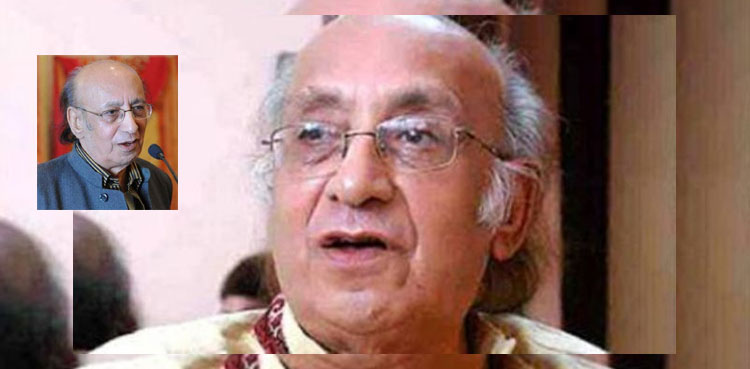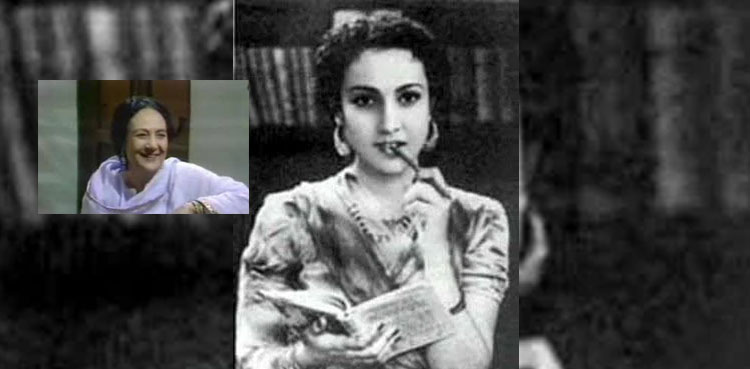قیامِ پاکستان کے بعد سردار عبدالرّب نشتر پاکستان کی پہلی کابینہ کا حصّہ رہے اور پنجاب کے گورنر بنائے گئے۔ زندگی کے آخری ایّام میں وہ مسلم لیگ کی صدارت کررہے تھے۔
سردار عبدالرّب نشتر نے متحدہ ہندوستان میں برطانیہ کے راج کے خلاف تحریکوں اور سیاسی ہنگامہ خیزی کے جس دور میں خود کو میدانِ عمل میں اتارا تھا، اس میں جلد ان پر واضح ہو گیا کہ ہندو، ملک کے طول و عرض میں موجود مسلمانوں کے ساتھ تعصّب ختم نہیں کرسکتے اور انگریزوں کو نکال کر یہاں اپنا راج قائم کرنا چاہتے ہیں۔ تب انھوں نے آل انڈیا مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کر لی۔ وہ اپنی فہم و فراست، سیاسی سوجھ بوجھ کے لیے مشہور تھے اور جلد ہی مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت کے پلیٹ فارم سے بھی خود کو منوا لیا اور اپنی دیانت داری اور اخلاص کے باعث ان کا شمار قائدِ اعظم کے قابلِ اعتماد رفقا میں ہونے لگا۔
اس سیاسی جماعت کی صف میں وہ ایسے نمایاں ہوئے کہ قائدِ اعظم کے ساتھ اہم جلسوں اور سیاسی قائدین سے ملاقاتوں میں شریک ہونے لگے۔
کہتے ہیں شخصیت کردار سے بنتی ہے اور سردار عبدالرّب نشتر نے قائدِ اعظم اور دیگر لیگی قائدین کو اپنے قول و فعل، راست گوئی اور کردار کی مضبوطی سے اپنا گرویدہ بنا لیا اور تاریخ میں مسلمانوں کے ایک مخلص اور اہم لیڈر کے طور پر ان کا نام رقم ہوا۔
سردار عبدالرّب نشتر ایک مدبّر، شعلہ بیان مقرر اور تحریکِ پاکستان کے صفِ اوّل کے راہ نما اور ایک اچھے شاعر بھی تھے۔ انھوں نے 13 جون 1899ء کو پشاور کے ایک مذہبی گھرانے میں آنکھ کھولی تھی اور دین کی تربیت کے ساتھ انھیں جدید تعلیم سے روشناس کروایا گیا۔ انٹرمیڈیٹ کا امتحان پاس کرنے کے بعد ایل ایل بی کی ڈگری 1925ء میں حاصل کی اور وکالت کا لائسنس لیا۔ جس وقت وہ علی گڑھ میں پڑھ رہے تھے، ان کے والد کا انتقال ہوگیا۔ تب انھوں نے پشاور میں وکالت شروع کر دی۔
علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں دورانِ تعلیم بھی اُن کی فکری اور نظریاتی بنیادوں پر تربیت ہوتی رہی اور عنفوانِ شباب میں وہ مولانا محمد علی جوہر اور مولانا ابو الکلام آزاد جیسے اکابرین کے قریب رہے۔ سامراج دشمنی گویا اُن کے خون میں تھی جو زمانۂ طالب علمی ہی میں اِن بزرگوں کے زیرِ اثر دو آتشہ ہوگئی۔
وکالت کے دوران انھوں نے سیاست میں آنے کا فیصلہ کیا تو اس وقت کی مشہور و مقبول تحریکِ خلافت سے وابستہ ہوئے اور عملی سفر کا آغاز کیا، اسی زمانے میں انھیں مسلمانانِ ہند کو درپیش مسائل اور مشکلات کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھنے کا موقع ملا۔ انھیں مسلمانوں کے خلاف ہندوؤں کی سازشوں اور ان کے رویّوں کا بھی اچھی طرح اندازہ ہوگیا۔
1929ء میں جب صوبہ سرحد میں انتخابات کا اعلان کیا گیا تو سردار عبدالرب نشتر خلافت کمیٹی کی طرف سے میونسپل کمیٹی کے رکن منتخب ہوئے اور مسلسل 1938ء تک رُکن رہے۔ بعد میں سردار عبدالرب نشتر نے آل انڈیا مسلم لیگ کی رکنیت اختیار کی اور 1944ء میں اس تنظیم کی مجلسِ عاملہ کے رکن بنائے گئے۔ 1946ء کے انتخابات کے بعد بننے والی عبوری حکومت کے لیے نمائندہ بھی نام زد ہوئے جب کہ 3 جون کے اعلان کے حوالے سے’’پارٹیشن کمیٹی‘‘ کے ارکان میں سردار عبدالرّب نشتر بھی شامل تھے۔
انھیں غیر منقسم ہندوستان کے وزیرِ مواصلات کے منصب پر بھی فائز رہنے کا موقع ملا تھا اور قیامِ پاکستان کے بعد وہ لیاقت علی خان کی کابینہ میں بھی اِسی وزارت کے لیے منتخب کیے گئے۔
14 فروری 1958ء کو سردار عبدالرّب نشتر کراچی میں وفات پاگئے تھے۔