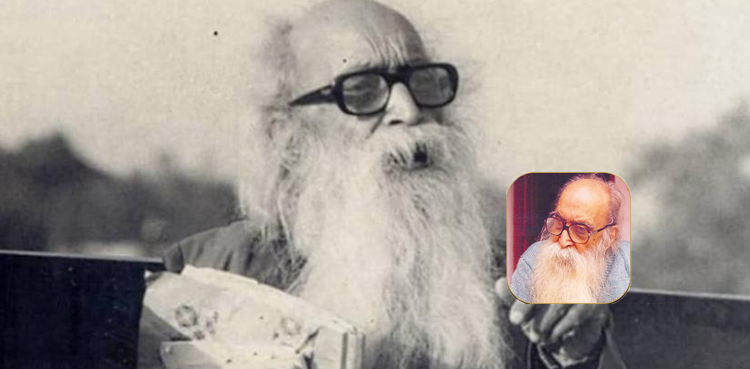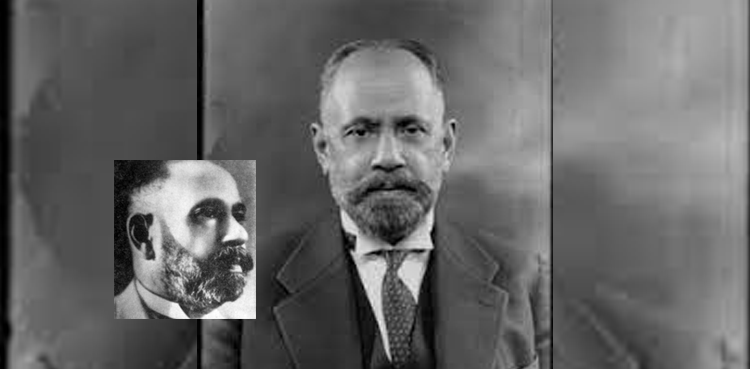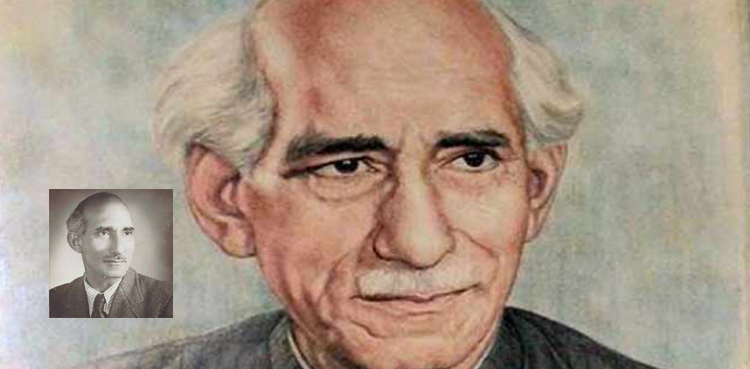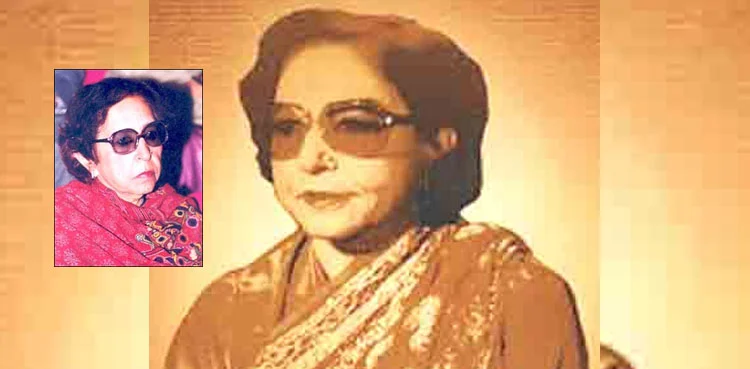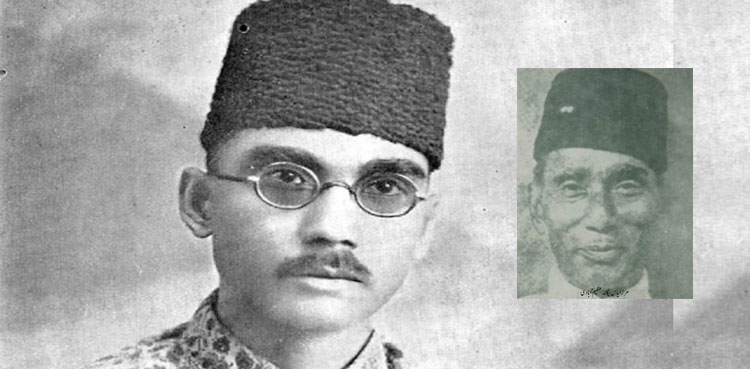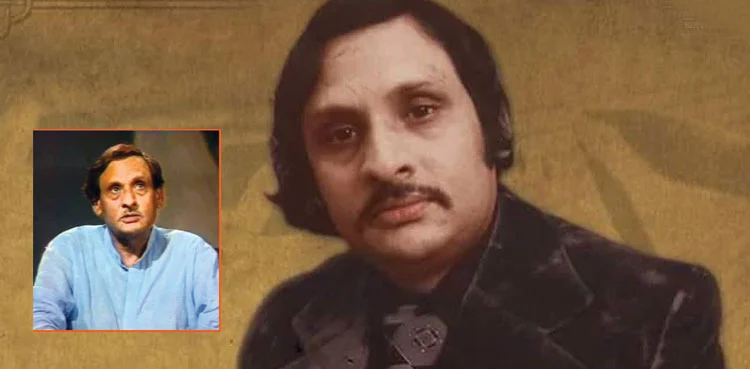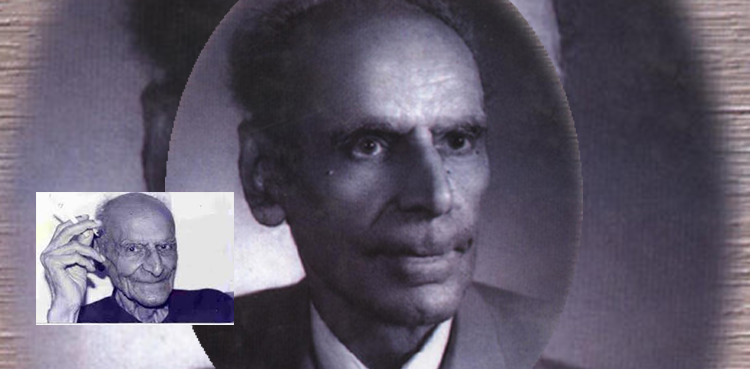دیوندر ستیارتھی اُن چند تخلیق کاروں میں سے ایک ہیں جو اپنی افسانہ نگاری کے علاوہ سنیاسی کا روپ دھار کر برصغیر کے مختلف شہروں میں لوک گیت جمع کرنے کے لیے مشہور ہیں۔ انھوں نے اردو، پنجابی اور ہندی زبانوں میں لکھا۔ ان کے تحریر کردہ خاکے، خود نوشت، سفرنامے اور شاعری بھی شایع ہوئی۔
دیوندر ستیارتھی کی پیدائش ہندوستان میں پنجاب کی آریہ سماجی تہذیب کے ایک کھتری خاندان میں 28 مئی 1908 کو ہوئی۔ ستیارتھی کی ابتدائی تعلیم گاؤں کے اسکول میں ہوئی۔ دسویں جماعت کے بعد ان کا ارادہ لاہور میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کا تھا مگر مالی حالات اور دیگر وجوہات کی بنا پر وہ لاہور نہیں جاسکے۔ ان کا داخلہ پٹیالہ کے کالج میں کروا دیا گیا۔ دیویندر ستیارتھی اپنے معاصرین میں بہت مقبول تھے۔ بہت سے لوگ انھیں مختلف ناموں سے یاد کرتے تھے۔ وہ منٹو کے ہم عصر افسانہ نگار تھے اور منٹو ان کو فراڈ کہتے تھے۔ پرکاش پنڈت نے ادبی رشی کا نام دیا۔ کرشن چندر نے مہا بور کہا۔ بلراج مین را نے آوارہ تخلیق کار کہا۔
سیتارتھی ایک نرالی شخصیت تھے۔ ان کی ایک عادت جس سے ان کے دوست تنگ رہتے، اپنا افسانہ زبردستی سنانا تھی۔ ادیب اور صحافی محمود الحسن کی کتاب ‘لاہور: شہرِ پُرکمال’ میں سیتارتھی سے متعلق ایک دل چسپ قصّہ پڑھنے کو ملتا ہے، ملاحظہ کیجے۔
ستیارتھی سنت نگر میں رہتے تھے۔ اسی علاقے میں کنہیا لال کپور، فکر تونسوی اور ہنس راج رہبر کی رہائش تھی۔ یوں وہ براہِ راست ستیارتھی کی زد میں تھے، اس لیے چھپتے پھرتے۔ راجندر سنگھ بیدی کی قسمت بری تھی کہ ستیارتھی ایک دفعہ ان کے یہاں بیوی اور بیٹی سمیت آن براجے اور کئی دن ٹھیرے۔ بیدی لاہور کینٹ میں چھوٹے سے مکان میں رہتے تھے۔ شام کو تھکے ٹوٹے گھر پلٹتے تو مہمانِ عزیز افسانہ سنانے کو پھر رہے ہوتے، اس پر طرّہ یہ کہ اصلاح کے طالب ہوتے۔ اس عمل میں جو وقت برباد ہوتا سو ہوتا لیکن صبح سویرے بھی تازہ دَم ہو کر ستیارتھی تصحیح شدہ افسانہ بیچارے میزبان کو سناتے۔ ان سب باتوں سے تو بیدی زچ تھے ہی، غصّہ ان کو اس بات پر بھی تھا کہ بیوی بچّوں کے لیے وہ وقت نہ نکال پاتے۔ یہ سب معلومات بیدی کی زبانی منٹو کے علم میں آئیں، جن کی بنیاد پر انھوں نے افسانہ ”ترقّی پسند“ لکھ دیا۔
ستیارتھی نے بیدی کی خلوت میں ایسی کھنڈت ڈالی کہ میاں بیوی کا قرب محال ہو گیا۔ منٹو نے یہ صورتِ حال افسانوی رنگ میں یوں پیش کی کہ ایک دن دھڑکتے دل کے ساتھ، کہ کہیں سے ترپاٹھی (دیوندر ستیارتھی) نہ آجائے، اس نے جلدی سے بیوی کا بوسہ یوں لیا جیسے ڈاک خانے میں لفافوں پر مہر لگائی جاتی ہے۔ یہ بیدی پر سیدھی چوٹ تھی کہ وہ ان دنوں ڈاک خانے میں لفافوں پر مہر لگاتے تھے۔
منٹو کی کہانی کے ردِعمل میں ستیارتھی نے ”نئے دیوتا“ کے عنوان سے افسانہ لکھ ڈالا، اس میں منٹو کے طرزِ زندگی پر طنز تھا۔ مرکزی کردار کا نام نفاست حسن رکھا گیا۔ یہ کہانی ”ادبِ لطیف“ میں چھپی اور بقول ستیارتھی، اوپندر ناتھ اشک اور کرشن چندر کو بہت پسند آئی اور انھوں نے منٹو کو اس پر خوب دق کیا۔ ستیارتھی نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس کہانی کی وجہ سے منٹو ان سے پانچ سال ناراض رہے۔ دونوں کی صلح کرانے میں راجندر سنگھ بیدی اور نذیر احمد چودھری نے کردار ادا کیا۔ ”نئے دیوتا“ کے بارے میں کہا گیا کہ بھلے سے یہ ستیارتھی کے نام سے شایع ہوا ہو مگر اس کے اصل مصنف بیدی ہیں۔ اشک اپنے مضمون ”منٹو میرا دشمن“ میں بتاتے ہیں:
”دوستوں کے درمیان دیوار نہ کھڑی ہوئی بلکہ انھوں نے منٹو کے خلاف ایک مشترکہ محاذ قایم کر لیا اور جس طرح منٹو نے اپنی کہانی میں بیدی اور ستیارتھی کے عادات و اطوار، شکل و شباہت اور ذاتی زندگی کا مذاق اُڑایا تھا، اسی طرح ان دونوں نے مل کر ایک افسانہ لکھ کر منٹو کی ذاتی زندگی اور اس کی خامیوں کو اُجاگر کر دیا۔ کہانی ستیارتھی کے نام سے شایع ہوئی۔ انھوں نے ہی لکھی تھی۔ بیدی نے اس پر نظرِ ثانی کرتے ہوئے کچھ ایسے پنّے لگائے کہ کہانی، جہاں تک کردار نگاری کا تعلّق ہے، بے حد اچھی اُتری، نام ہے ’نئے دیوتا‘ بات یہ ہے کہ افسانہ کسی نے لکھا ہو فنّی اعتبار سے منٹو کے ’ترقی پسند‘ کا پلّہ بھاری ہے۔“
دیوندر ستیارتھی کے لوک گیتوں پر کام کو کنھیا لال کپور بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ ان کا کہنا تھا: ”اللہ میاں کی کچہری میں جب ستیارتھی کو آواز پڑے گی تو ’لوک گیتوں والا ستیارتھی‘ کہہ کر، نہ کہ کہانی کار ستیارتھی کے نام سے۔“ بیدی اس معاملے میں کپور کے ہم خیال تھے۔
ستیارتھی نے حلقۂ اربابِ ذوق میں اپنی کہانی ”اگلے طوفانِ نوح تک“ پڑھی جس میں نذیر احمد چودھری کو بطور پبلشر طنز و مزاح کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ بیدی نے بحث میں حصّہ لیتے ہوئے کہا: ”ستیارتھی کو سات جنم میں بھی کہانی کار کا مرتبہ حاصل نہیں ہوسکتا۔“ اس پر ستیارتھی نے جواب دیا: ”حضرات! جب تک میں کہانی کار نہیں بن جاتا میں بدستور بیدی کو گرو دیو تسلیم کرتا رہوں گا۔“
دیوندر ستیارتھی کی تمام زبانوں میں تصنیفات کی تعداد پچاس کے لگ بھگ ہے۔ وہ 12 فروری 2003 کو بھارت میں وفات پاگئے تھے۔