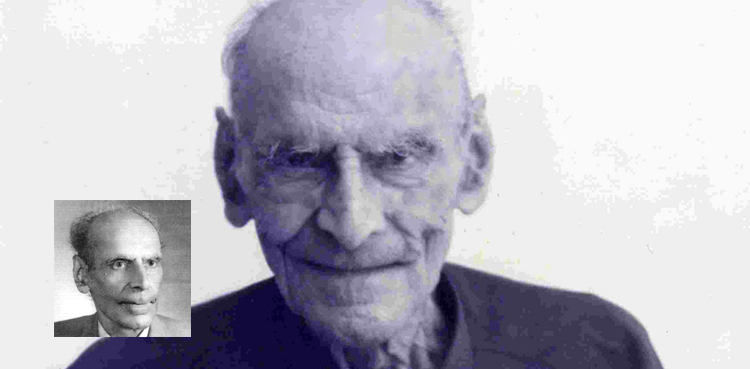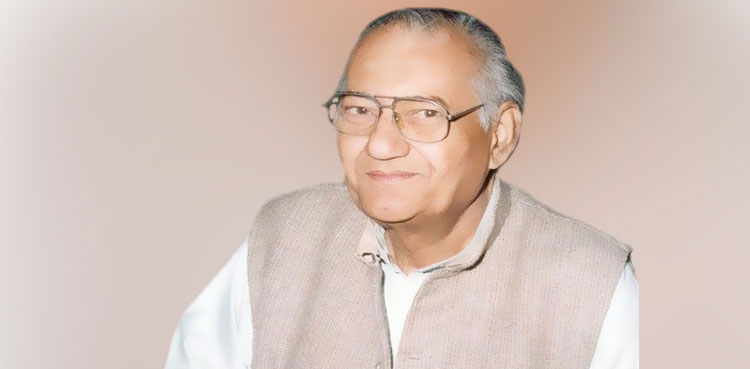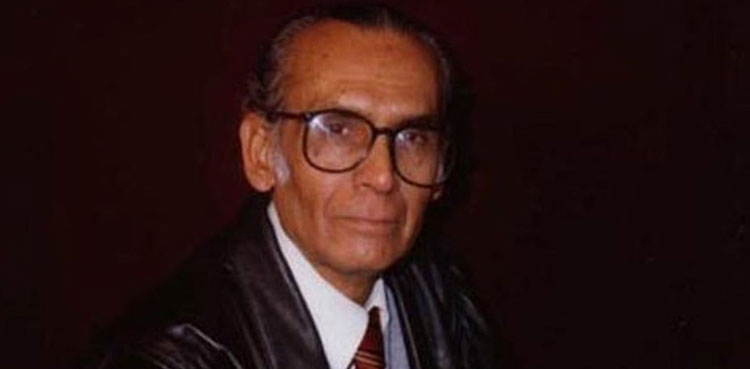یہ اُس آتش بیان کا تذکرہ ہے جو دنیا کو بازیچۂ اطفال خیال کرتا تھا۔ اسے اپنا فارسی کلام بہت پسند تھا، لیکن جو مقبولیت اور شہرتِ دوام اسے حاصل ہوئی، وہ اردو شاعری کی بدولت ہوئی۔ اسے برصغیر کا عظیم شاعر تسلیم کیا گیا۔ آج ہر خاص و عام اسے مرزا غالب کے نام سے جانتا ہے۔
مرزا اسد اللہ خان کا وطن آگرہ تھا، وہی آگرہ جو ایک اعجوبہ و نادرِ زمانہ عمارت تاج محل کے لیے بھی دنیا بھر میں پہچانا جاتا ہے۔ مرزا غالب 27 دسمبر 1797ء کو پیدا ہوئے۔ دلّی میں پرورش پائی۔ کم سنی ہی میں شعر گوئی کا آغاز کردیا تھا۔ غالب کا ابتدائی کلام فارسی زبان و تراکیب اور ان کی مشکل پسندی کی وجہ سے تنقید کی زد میں آیا مگر غالب نے اپنے اس اندازِ بیان کو نہ چھوڑا۔
ناقدین کے مطابق انھوں نے مسلسل تنقید کے بعد اپنے کلام کو کچھ تبدیلی کے ساتھ ضرور پیش کیا، لیکن ان کی مخالفت کم نہ ہوسکی۔ غالب یہ کہنے پر مجبور ہوگئے:
نہ ستائش کی تمنّا نہ صلے کی پروا
گر نہیں ہیں مرے اشعار میں معنی نہ سہی
ادھر دلّی کے حالات ابتر اور خود غالب کی زندگی کی مشکلات بڑھتی جارہی تھیں۔ وہ معاش کی فکر اور تنگ دستی سے پریشان تھے۔ تبھی غالب کی شاعری میں ایک جدّت بھی پیدا ہوئی۔ مگر ان کی شاعری کا رنگ نرالا ہی رہا۔ غالب نے اپنی شاعری میں روایتی موضوعات کو بھی نہایت پُرلطف اور الگ ہی ڈھب سے باندھا اور ایسے مقبول ہوئے کہ آج تک ان کا سحر برقرار ہے۔ مرزا غالب نے سنجیدہ اور گہرے مضامین کو نہایت بے تکلفی سے اپنے اشعار میں باندھا ہے اور یہی ان کی وجہِ انفرادیت ہے۔
ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے
کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور
غالب کے اشعار کی خوبی یہ ہے کہ ہر بار قاری ایک نئے معنٰی اور نئے مفہوم سے آشنا ہوتا ہے۔
اردو زبان کے اس عظیم شاعر کا زمانہ وہ تھا جب مغل حکومت کا شیرازہ بکھر رہا تھا۔ ہندوستان میں ابتری اور انتشار تھا۔ عہدِ طفلی میں غالب اپنے والد سے محروم ہوگئے اور بھائی بھی نہ رہے۔ پرورش کی ذمہ داری ان کے چچا مرزا نصر اللہ بیگ نے اٹھا لی، لیکن غالب آٹھ سال کے تھے کہ چچا بھی فوت ہو گئے۔ یوں بچپن محرومیوں اور مشکلات میں کٹ گیا۔ کم عمری میں ان کی شادی نواب الٰہی بخش کی بیٹی سے ہوگئی تھی۔ شادی ہوئی تو خدا نے متعدد بار اولاد دی جو بچپن میں ہی مٹی کا رزق بن گئی۔ اس پر غالب کی شراب نوشی اور مالی خستگی نے بڑا غضب ڈھایا۔
غالب غزل گو شاعر، قصیدہ نگار اور اچھے نثر نگار تھے۔ خطوط نویسی میں ان کا جواب نہیں۔ انھوں نے خط کو مکالمہ بنا دیا تھا۔ ان کے دواوین 1841ء، 1847ء، 1861ء، 1862ء اور 1863ء میں شائع ہوئے۔ مشکل پسندی کا زمانہ ختم ہوا تو غالب نے سلاست، روانی اور نہایت خوب صورتی سے اپنے خیالات کو غزل میں پیش کرکے اس وقت کے شعرا میں نمایاں مقام حاصل کیا۔ ان کے کلام میں فلسفیانہ انداز، عشق اور تصوف کے موضوعات کا نہایت لطیف اظہار ملتا ہے۔
فارسی کی تراکیب اور مشکل الفاظ کے استعمال کو چھوڑ کر جب غالب نے اردو شاعری پر توجہ دی تو ان کے کلام میں فصاحت اور بلاغت عروج پر تھی جس نے انھیں مقبولیت دی۔
انھیں مغل دربار تک رسائی حاصل ہوئی تو وہ نجم الدّولہ، دبیرُ الملک، مرزا نوشہ اور نظام جنگ جیسے خطاب اور القاب سے نوازے گئے۔ غالب کی شاعرانہ عظمت کا راز صرف ان کے کلام میں حسن اور بیان کی خوبی ہی نہیں بلکہ انھوں نے زندگی کے حقائق اور انسانی نفسیات کو نہایت خوب صورتی سے اپنے اشعار میں سمویا اور اسی لیے ممتاز ہوئے۔ غدر کے بعد والیٔ رام پور کے دربار سے وابستہ ہوگئے جہاں سے آخر عمر تک وظیفہ ملتا رہا۔
غالب بحیثیت نثار بھی اردو ادب میں نہایت اہم مقام رکھتے ہیں اور خاص طور پر ان کے خطوط کا شہرہ ہوتا ہے جس میں انھوں نے نثر کو ایک نیا آہنگ اور اسلوب دیا۔ اس زمانے میں خطوط نگاری پُرتکلف القاب و آداب، مقفع اور مسجع زبان میں کی جاتی تھی، لیکن مرزا غالب نے اپنے دوستوں اور مختلف شخصیات کو لکھے گئے خطوط میں سادہ اور عام زبان کے ساتھ دل چسپ انداز اختیار کیا اور گویا ’’مراسلے کو مکالمہ بنا دیا۔‘‘
مرزا غالب سے کئی لطائف اور تذکرے منسوب ہیں لیکن ہم یہاں وہ واقعہ نقل کررہے ہیں جس سے غالب کی دردمندی اور انسان دوستی عیاں ہوتی ہے۔
"غالب کا عام طریقہ یہ تھا کہ جب تک واقعی اچھا شعر نہ ہوتا، تعریف نہ کرتے اور خاموش بیٹھے رہتے۔
خواجہ حالی فرماتے ہیں کہ اس بنا پر بعض معاصرین ان سے آزردہ رہتے تھے اور ضد میں آکر ان کی شاعری پر طرح طرح کی نکتہ چینیاں کرتے تھے۔ ویسے غالب طبعاً صلح جو تھے اور ہر شخص کی دلداری کا انتہائی خیال رکھتے تھے۔
"تذکرہ غوثیہ” میں ایک واقعہ حضرت غوث علی شاہ پانی پتی کی زبانی مرقوم ہے کہ ایک روز مرزا، رجب علی بیگ سرور، مصنف فسانہ عجائب سے ملے۔ اثنائے گفتگو پوچھا کہ اُردو زبان کس کتاب کی عمدہ ہے۔ جواب ملا کہ "چہار درویش” کی۔
سرور نے "فسانہ عجائب” کا نام لیا۔ غالب کو معلوم نہ تھا کہ خود مصنفِ "فسانہ عجائب” استفسار کررہا ہے۔ بے تکلف جواب دیا۔ "اجی لاحول ولا قوۃ” اس میں لطفِ زبان کہاں۔ ایک تک بندی اور بھٹیار خانہ جمع ہے۔
جب سرور چلے گئے اور غالب کو معلوم ہوا کہ یہ "فسانہ عجائب” کے مصنف تھے تو بہت افسوس کیا اور کہا، "ظالمو پہلے سے کیوں نہ کہا۔”
دوسرے دن غوث علی شاہ صاحب ملے، انھیں سارا قصہ سنایا اور کہا کہ حضرت! یہ امر مجھ سے بے خبری میں سرزد ہوگیا۔ آئیے آج سرور کے مکان پر چلیں اور کل کی مکافات کر آئیں۔
چناں چہ وہاں گئے۔ مزاج پرسی کے بعد غالب نے عبارت آرائی کا ذکر چھیڑا اور بولے، جناب مولوی صاحب رات میں نے "فسانہ عجائب” کو بہ غور دیکھا تو اس کی خوبی عبارت اور رنگینی کا کیا بیان کروں، نہایت ہی فصیح و بلیغ ہے۔ غرض اس قسم کی باتوں سے سرور کو مسرور کیا۔
دوسرے دن ان کی دعوت کی اور غوث علی شاہ صاحب کو بھی بلایا۔
شاہ صاحب یہ واقعہ بیان فرمانے کے بعد کہتے ہیں:
"مرزا صاحب کا مذہب یہ تھا کہ دل آزاری بڑا گناہ ہے۔” لیکن اشعار کی داد میں راہِ حق سے بال برابر بھی انحراف گوارا نہ تھا۔” واضح ہو کہ یہ واقعہ مولانا غلام رسول مہر کی کتاب سے نقل کیا گیا ہے۔
اپنے ایک خط میں غالب نے اپنی مکان سے متعلق پریشانی کا تذکرہ کیا تھا۔ یہ مرزا غالب کے ایک چہیتے شاگرد منشی ہر گوپال المعروف مرزا تفتہ سے منسوب ہے۔ انھیں لکھے گئے غالب کے ایک ایسے ہی خط سے چند سطور ہم یہاں نقل کررہے ہیں۔ اس میں اسد اللہ خان غالب نے اپنے مستقر کی تبدیلی سے متعلق مرزا تفتہ کو اپنی تکلیف اور پریشانی سے آگاہ کیا تھا۔ لکھتے ہیں،
"مالک نے مکان بیچ ڈالا۔ جس نے لیا ہے اس نے مجھ سے پیام بلکہ ابرام کیا کہ مکان خالی کر دو۔ مکان کہیں ملے تو میں اوٹھوں (اٹھوں) بیدرد نے مجھ کو عاجز کیا اور مدد لگا دی۔ وہ صحن بالا خانے کا جس کا دو گز کا عرض اور دس گز کا طول، اس میں پاڑ بندھ گئی۔ رات کو وہیں سویا۔
گرمی کی شدت پاڑ کا قرب، گمان یہ گزرتا تھا کہ یہ کٹکڑ ہے اور صبح کو مجھ کو پھانسی ملے گی۔ تین راتیں اسی طرح گزریں۔ دو شنبہ 9 جولائی کو دوپہر کے وقت ایک مکان ہاتہ (ہاتھ) آ گیا، وہاں جا رہا، جان بچ گئی۔ یہ مکان بہ نسبت اس مکان کے بہشت ہے اور یہ خوبی کہ محلّہ وہی بلی ماروں کا۔
اگرچہ ہے یوں کہ میں اگر اور محلّہ میں بھی جا رہتا تو قاصدانِ ڈاک وہاں پہنچتے، یعنی اب اکثر خطوط لال کنویں کے پتے سے آتے ہیں اور بے تکلف یہیں پہنچتے ہیں۔ بہرحال تم وہی دلّی بلی ماروں کا محلّہ لکھ کر خط بھیجا کرو۔
دو مسودے تمہارے اور ایک مسودہ بے صبر کا یہ تین کاغذ درپیش ہیں۔ دو ایک دن میں بعد اصلاح ارسال کیے جائیں گے۔ خاطر عاطر جمع رہے۔
صبح جمعہ
28 جولائی 1860ء
حالی کی مشہور تصنیف "یادگارِ غالبؔ” سے بھی اس عظیم شاعر کی شخصیت اور اپنے احباب کے لیے ان کی فکر کا اندازہ ہوتا ہے۔ کتاب میں لکھا ہے:
غالبؔ کے ایک امیر دوست جن کی حالت غدر میں بہت سقیم ہوگئی تھی، چھینٹ کا فرغل پہنے ہوئے ملنے آئے۔
غالبؔ نے انھیں کبھی مالیدے یا جامہ دار کے چغوں کے سوا نہیں دیکھا تھا۔
چھینٹ کا فرغل دیکھ کر غالبؔ کا دل بھر آیا، امداد کا خیال پیدا ہوا، لیکن دوست کی دل داری کا تقاضا یہ تھا کہ اس کے ساتھ ایسے طریق پر سلوک کیا جائے کہ اسے اپنی بے چارگی اور بے بسی کا احساس نہ ہو اور پیش کردہ ہدیہ قبول کرتے ہوئے عار نہ آئے۔
غالبؔ نے یہ عرض مدِنظر رکھ کر چھینٹ کے فرغل کی بے حد تعریف کی۔
پوچھا کہ یہ چھینٹ کہاں سے لی ہے اور (دوست سے) درخواست کی کہ مجھے بھی اس کا فرغل بنوا دیا جائے۔
دوست نے بلا تکلف کہا کہ ”اگر آپ کو یہ بہت پسند ہے تو یہی لے لیجیے۔“
غالب نے کہا، ”جی تو یہی چاہتا ہے کہ آپ سے ابھی چھین لوں، لیکن جاڑا شدت سے پڑ رہا ہے، آپ یہاں سے مکان(اپنے گھر تک) کیا پہن کر جائیں گے۔“
اسی کے ساتھ اپنا مالیدے کا نیا چغہ (اپنے دوست کو) پہنا دیا۔
15 فروری 1869ء کو مرزا غالب ہمیشہ کے لیے دنیا چھوڑ گئے تھے، مگر ان کے اعجازِ سخن کا چرچا آج بھی ہے اور آئندہ بھی ہوتا رہے گا۔