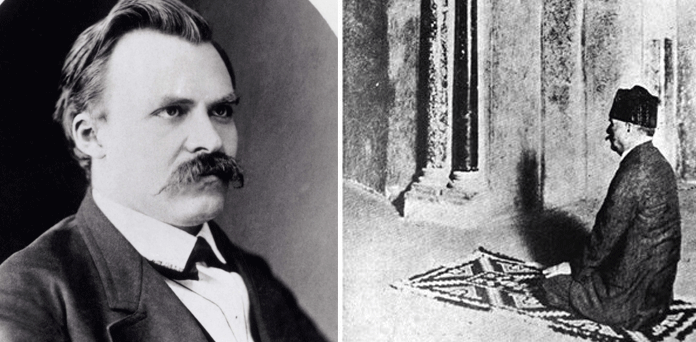شاعرِ مشرق حضرت علامہ اقبالؒ کے فکری مآخذ کے متعلق مختلف قیاس آرائیوں کا سلسلہ ان کی حیات میں شروع ہو گیا تھا جو ابھی تک تھما نہیں ہے۔
خصوصاً ان کے شہرۂ آفاق اور معراجِ انسانیت فلسفۂ خودی کے متعلق مختلف نقّادوں نے مختلف یورپی علمی شخصیات کے نام لیے ہیں۔ زیادہ تر کی تان فرانسیسی فلسفی نطشے پر ٹوٹی ہے جس نے’مردِ کامل‘ کے نام سے عظمتِ انسانی کا فلسفہ پیش کیا تھا۔
ابھی کل ہی میں جوشؔ ملیح آبادی کی کتاب ’یادوں کی بارات‘ پڑھ رہا تھا، اُنہوں نے بھی اقبالؒ پر طنز کے تیر برساتے ہوئے لکھا کہ انہوں نے نطشے کے مردِ کامل کو مسلمان کر کے مردِ مومن بنا دیا ہے۔ خیر جوش صاحب نے تو اس کتاب میں اور بھی بہت کچھ لکھا ہے جس میں اپنے تئیس معاشقوں، اپنی بادہ خوری، شب و روز کی عیاشیوں، قیامِ پاکستان کی مخالفت اور پھر اسی پاکستان میں سرکاری مراعات سے استفادہ اور پھر پاکستان چھوڑ کر ہندوستان لوٹ جانے تک، ان کوئی کل سیدھی دکھائی نہیں دی۔
حقیقت یہ ہے کہ اقبال ؒ مشرق اور مغرب دونوں بحرِ علم کے غواص تھے۔ کارل ماکس، گوئٹے، ارسطو، ابن ِ خلدون، رازی، رومی، نطشے، آئن سٹائن، بائرن، پٹوفی، ہیگل، مزدک سمیت علم و ہنر کے کتنے ہی تابندہ چراغ تھے جن سے اقبالؒ نے اکتسابِ فیض کیا۔ تاہم ان تمام حکما سے علامہ نے اپنے نظریات کو خلط ملط نہیں ہونے دیا، بلکہ ایک بلند پایہ مفکّر اور فلسفی کی حیثیت سے اپنی سوچ اور اپنا نظریہ منفرد اور جداگانہ رکھا۔
کہاں نطشے کا مردِ کامل جو بے روح مشین کی طرح ہے اور کہاں اقبال کا مردِ مومن جس کی خودی کا سرّ نہاں لا ا لہ الا اللہ ہے۔ ویسے بھی شاعرِ مشرق علامہ محمد اقبالؒ کی فکر اور فلسفہ تہذیبِ مشرق کا عکاس ہے جو عمومی طور پر مغربی فکر کے برعکس ہے۔ وہ فرماتے ہیں:
کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ
مشرق سے اُبھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ
علامہ ؒ کے فکر و نظر میں بُو علی اور رازی کا انداز اور رومی کا سوز و ساز ان کے کلام کو الہامی بنا دیتا ہے۔ علامہ اقبالؒ رومی جیسے مردِ عارف کے مدّاح تھے جس کی فکر میں سوز ہے۔ وہ انہیں پیرِ رومی کہتے تھے اور خود کو مریدِ ہندی۔ انہوں نے بُو علی کو عقل و دانش اور رومی کو عشق و مستی کا استعارہ قرار دیا۔ اقبال فرماتے ہیں:
اِسی کشمکش میں گزری مری زندگی کی راتیں
کبھی سوز و سازِ رومی، کبھی پیچ و تاب رازی
یورپ سے لوٹنے کے بعد اقبالؒ کے اندر ایسی انقلابی تبدیلیاں آئیں کہ انہوں نے وطنیت اور قومیت کا جال توڑ کر اسلام کا علم تھام لیا۔ وہ مفکر اسلام، حکیم الامت اور ترجمانُ القرآن بن کر احیائے اسلام اور نشاۃِ اسلامیہ کے علمبردار بن کر نمایاں ہوئے۔ چنانچہ اگلے تیس برس جو ان کی زندگی کے تھے وہ انہوں نے اسلام کے نظامِ فکر، فلسفۂ اسلام اور پیغمبرِ اسلام ﷺ کی شخصیت اور پیغام کو عام کرنے میں صرف کیے۔ اس کے بعد انہوں نے قرآن کے پیغام کو عام کرنے کے لیے جیسے خود وقف کر دیا۔
آغاز ہی سے اقبال کے کلام اور پیام میں قومی اور ملّی شعور نمایاں تھا۔ انہوں نے تاریخِ اسلام، اسلامی علم و فلسفہ، فقہی مباحث اور قرآن و سنت کا گہرائی سے مطالعہ کیا۔ تاریخِ اسلام سے ان کی فکر کو جلا ملی۔ اس علمی آگہی کی وجہ سے ملّتِ اسلامیہ کی عظمتِ رفتہ کے زوال، اس کی زبوں حالی، بیشتر مسلمان ملکوں کی غلامی، جہالت اور یورپ کی غاصبانہ نوآبادیاتی پالیسی نے اقبال ؒ کے عقل و شعور کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ مسلمانوں کے علمی ورثے، اسلامی تاریخ، مسلم مفکرین، علما، حکما کے کارنامے اسلام کے سنہری اصول، مسلمانوں کی فکری تحریکوں اور مغرب کے فلسفے کے عمیق مطالعے نے اقبالؒ کو اپنی بنیاد یعنی سیرت النبیﷺ اور قرآن کے قریب کر دیا۔ قرآن کریم ان کے شعور سے تحت الشعور تک سرایت کرتا چلا گیا۔ انہیں بیشتر مسائل کا حل اس الہامی کتاب میں دکھائی دینے لگا۔وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ قرآن سے ان کا رشتہ گہرے سے گہرا ہوتا چلا گیا۔ حتیٰ کہ قرآن اور صاحبِ قرآن ان کے فکر و فلسفہ کا محور بن گئے۔چنانچہ اقبالؒ قرآن کے ایسے مفسر اور شارح بن کر سامنے آئے جنہوں نے اس الہامی پیغام کو شعری اسلوب میں ڈھال کر نیا رنگ و آہنگ دیا جو تاقیامت اہلِ ایمان کے قلب و ذہن کو گرماتا رہے گا۔ علامہ ؒ کے کلام میں قرآنی پیام بھی ہے اور شعری حسن بھی ہے اور انتہائی موثر پیرایہ بھی جس سے کوئی بھی حساس قاری متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔:
فطرت کا سرودِ ازلی اس کے شب و روز
آہنگ میں یکتا، صفتِ سورۂ رحمٰن
جہاں تک عقلی خیالات کا تعلق ہے، اقبالؒ کے نزدیک استدلالی اور طبیعی عقل حیوانی جذبات کے تابع ہوتی ہے اور انسان کے خیالات اور فکر و نظر میں تنگی کا باعث بنتی ہے جس سے عام قاری کو مغالطہ ہوتا ہے اور وہ ہر قسم کی عقل کو بیکار سمجھنے لگتا ہے۔ اقبالؒ عقلِ جزوی کے قائل نہیں کیونکہ یہ عقلِ ایمانی اور عقلِ نبویﷺ کی نفی کرتی ہے۔ ایسے گمراہ کن فلسفے انسان کو خدا اور خودی دونوں سے دور کر دیتے ہیں۔
اقبالؒ نے اپنی شاعری اور فلسفے کے ذریعے حقیقتِ حیات تک رسائی آسان بنا دی ہے جو انسان کو تختِ معراج تک پہنچا سکتی ہے۔ تاہم یہاں یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ اقبال زندگی کی حقیقت سے آگاہ ہونے کے باوجود وجدان پر زیادہ یقین رکھتے ہیں کیونکہ بنیادی طور پر وہ ایک صوفی ہی تھے۔ اقبال غالباً دنیا کے واحد فلسفی ہیں جو شعر کو ذریعۂ اظہار بنا کر فکر کو فن کی شکل میں پیش کرتے ہیں۔ لیکن انہیں شعر اور فلسفے کے فرق کا ادراک تھا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ آپس میں مدغم ہو کر کہیں بھی تضاد پیدا نہیں کرتے۔ اسی طرح آیاتِ قرآنی بھی ان کے اشعار کی زینت بن کر ان کے نظریۂ حیات کو مزید تقویت عطا کرتی ہیں۔
کتابُ اللہ کی آیات کو اشعار میں استعمال کرنا ایک نہایت دقیق کام ہے لیکن یہ کام علامہؒ نے نہایت مہارت اور خوبی سے کیا ہے۔ اقبالؒ کی عقل اور دانائی فکرِ انسانی تک محدود نہیں بلکہ اس کے مآخذ قرآن و سنت بھی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا پیغام واضح اور ابہام سے پاک ہے۔
(آسٹریلیا میں مقیم افسانہ نگار اور ادبی محقق طارق مرزا کے مضمون ‘اقبالؒ کے فکری مآخذ’ سے اقتباسات)