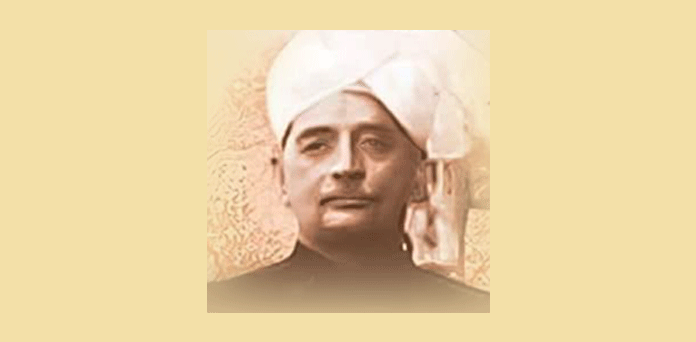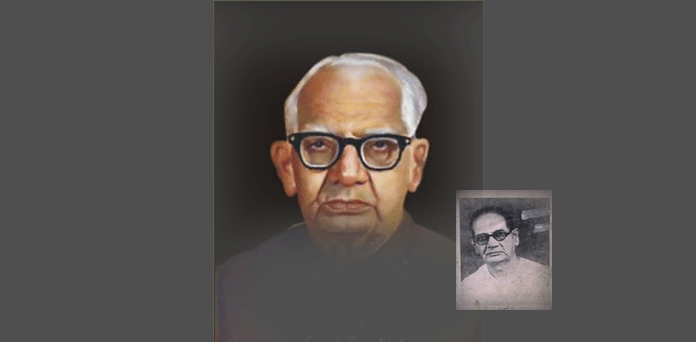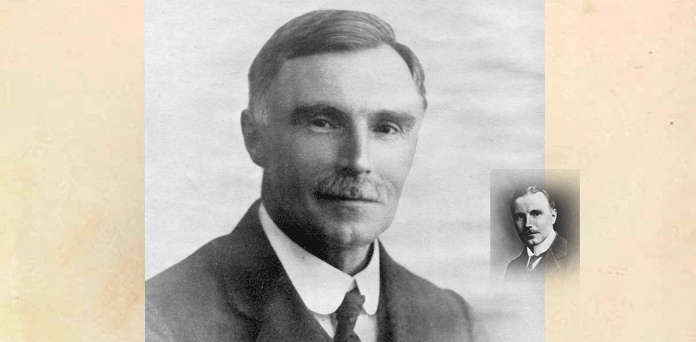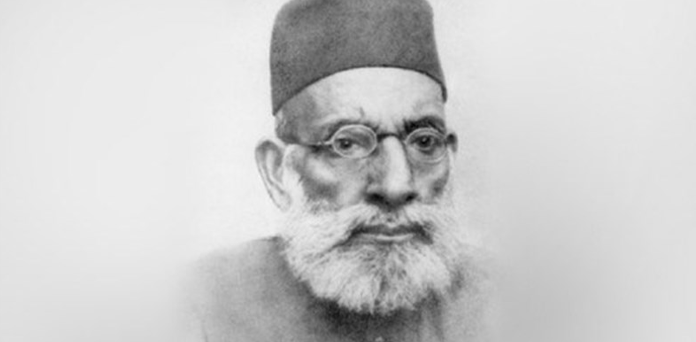علم و ادب کی دنیا میں خواجہ دل محمد اپنے وقت کے ایک نہایت قابل و باصلاحیت شخصیت مشہور تھے۔ وہ بیک وقت شاعر اور مصنف بھی تھے اور ایک ریاضی داں اور ماہرِ تعلیم بھی۔ آج اگرچہ ان کا تذکرہ شاذ ہی ہوتا ہے لیکن خواجہ صاحب جیسی شخصیات کے علمی و ادبی کارناموں سے انکار نہیں کیا جاسکتا بلکہ وہ علم و ادب کی دنیا کا ایک مثالی نام ہیں۔
یہ بھی پڑھیے: خواجہ دل محمد کی نظم اور ڈپٹی نذیر احمد کی چوگوشیہ ٹوپی
کہا جاتا ہے کہ خواجہ صاحب کے مورثِ اعلیٰ کو سلطان محمود غزنوی کے عہد میں مشرف بہ اسلام ہونے کی سعادت نصیب ہوئی اور تب ان کے بزرگ لاہور آکر آباد ہوگئے۔ ان کا آبائی وطن غزنی تھا جب کہ خاندانی پیشہ تجارت۔ اسی خاندان میں خواجہ دل محمد نے لاہور کے کوچہ ’’گیان‘‘ عقب کشمیری بازار میں فروری 1883ء میں آنکھ کھولی۔ وہ خواجہ نظام الدین کے فرزند تھے۔ اس زمانے کے دستور کے مطابق قرآن کی تعلیم پائی اور ناظرہ مکمل کرنے کے بعد اسلامیہ ہائی اسکول شیرانوالہ گیٹ میں میں داخلہ لیا۔ میٹرک تک اسی اسکول سے درجات مکمل کیے۔ یہ وہ دور تھا جب انجمن حمایت اسلام نے اسلامیہ ہائی اسکول کی عمارت کے بالائی حصے میں کالج بھی قائم کیا تھا۔ خواجہ دل محمد نے بعد میں یہیں سے ایف اے اور بی اے کے امتحانات پاس کیے۔ کالج کے زمانے میں شیخ سر عبدالقادر ان کے استادوں میں سے تھے جن کی شخصیت اور علمی قابلیت سے خواجہ دل محمد بھی متاثر ہوئے۔
خواجہ دل محمد کو ریاضی کے مضمون سے فطری مناسبت اور بہت رغبت تھی۔ اسی مضمون میں 1970ء میں ماسٹرز کا امتحان پاس کیا۔ اس کے بعد اسلامیہ کالج ہی میں استاد مقرر ہو گئے۔ علمی دنیا سے ان کی وابستگی ہمیشہ بڑی گہری اور والہانہ رہی۔ وہ نوجوانوں کی تعلیم و تربیت میں گہری دل چسپی لیتے تھے۔ اگرچہ خواجہ دل محمد کی قابلیت اور محنت و لگن کو دیکھتے ہوئے مختلف اوقات میں انھیں گراں قدر مشاہرے پر خدمات انجام دینے کی پیشکش ہوئی۔ لیکن وہ ہمیشہ اسلامیہ کالج سے وابستہ رہے۔ انھوں نے 35 برس تک اس کالج میں تشنگان علم کو فیض یاب کیا۔ 1940ء میں اسی کالج کے پرنسپل مقرر ہوگئے اور 1943 ء میں اپنی ذمہ داریوں سے سبک دوش ہوئے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد رجسٹرار ضلع لاہور مقرر ہوئے۔ 1946ء میں خرابیِ صحت کے باعث یہ ذمہ داری چھوڑ دی۔ 27 مئی 1961ء کو خواجہ دل محمد انتقال کرگئے تھے۔
بحیثیت استاد خواجہ دل محمد بہت کام یاب اور ہر دل عزیز رہے۔ ان کو تدریس کا وسیع تجربہ تھا اور ریاضی جیسا خشک مضمون بہت دل چسپ انداز سے پڑھاتے تھے۔ بحیثیت ریاضی داں ان کی خوب شہرت تھی اور کہتے ہیں کہ اس زمانے میں ان کے پائے کے ماہرِ ریاضیات چند ہی تھے۔
خواجہ دل محمد ملازمت کے ساتھ ساتھ تصنیف و تالیف کے کام بھی انجام دیتے رہے۔ ادبی سفر پر نظر ڈالیں تو وہ شاعری کی خداداد صلاحیت رکھتے تھے۔ انھوں نے ابتدا نعت گوئی سے کی اور بعد میں قومی و اصلاحی نظموں کی وجہ سے بھی پہچانے گئے۔ خواجہ دل محمد کی شاعری کا باقاعدہ آغاز ہی انجمن حمایت اسلام کے سالانہ جلسوں میں ولولہ انگیز شاعری سے ہوا۔ طالب علمی کے زمانے میں خواجہ صاحب ان جلسوں میں نظمیں سناتے تھے جہاں اکابر شعرا جیسے حالی، شبلی، ڈپٹی نذیر احمد وغیرہم موجود ہوتے اور اپنا کلام پیش کرتے تھے۔ خواجہ دل محمد کو ان شخصیات سے داد ملی۔ خواجہ صاحب نے ان نظموں کو 1956ء میں ’’حیات نو‘‘ کے نام سے شائع کیا۔
خواجہ دل محمد کی سیاسی اور سماجی خدمات کا دائرہ بھی وسیع ہے۔ انھوں نے قومی اور سیاسی تحریکوں میں حصہ لیا۔ 1924ء میں خلافت اور کانگریس کی متحدہ کمیٹی کے ٹکٹ پر میونسپل کمیٹی کے الیکشن میں حصہ لیا اور دامے درمے قدمے سخنے مسلمانوں کی مدد کرتے رہے اور اپنی شاعری کے ذریعے مسلمانوں میں آزادی کا جوش اور ولولہ بھی پیدا کرتے رہے۔
خواجہ دل محمد نے پنجاب یونیورسٹی لاہور کی اعلیٰ جماعتوں کا نصاب تیار کرنے میں بھی حصہ لیا۔ پنجاب یونیورسٹی سنڈیکیٹ کے گیارہ برس تک ممبر اور 24 برس تک فیلو آف پنجاب یونیورسٹی رہے۔ الجبرا اور ریاضی پر ان کی متعدد تصانیف تھیں جو نصاب میں بھی شامل رہیں۔ دوسری طرف انجمن حمایت اسلام کے اسلامیہ اسکولوں میں ہندو اور انگریز مصنفین کی کتابیں اس وقت متعارف کروائی گئی تھیں مگر خواجہ دل محمد کی ان تصانیف کی طباعت کے بعد انھیں شامل کرلیا گیا۔ پاکستان بننے کے بعد خواجہ دل محمد کی مرتب کردہ ریاضی کی 32 کتب مختلف مدارج کے نصاب میں شامل رہیں۔