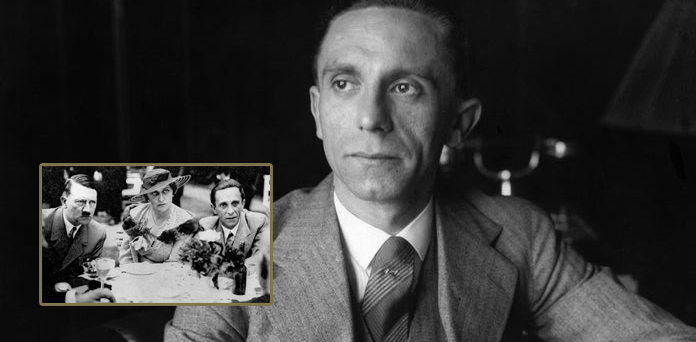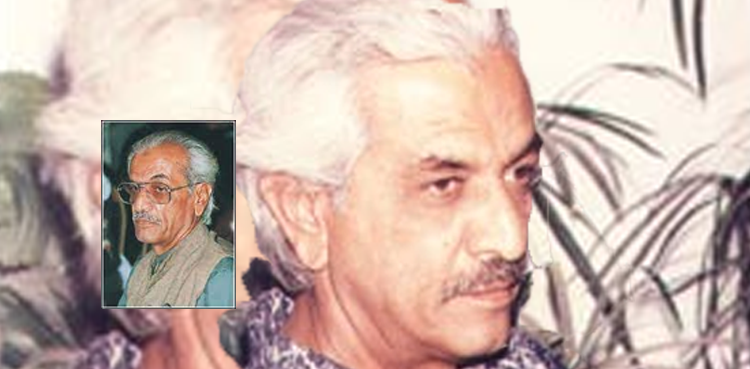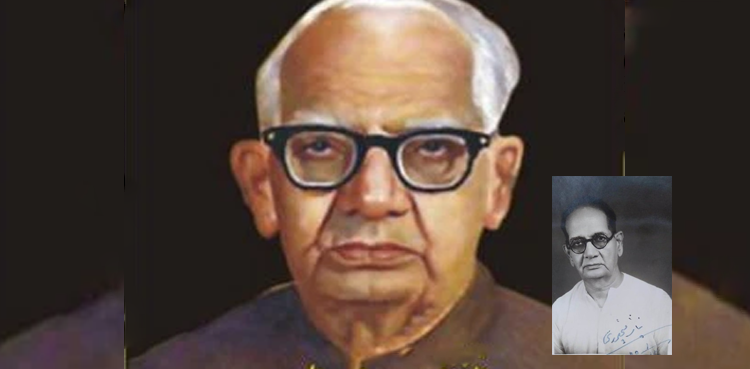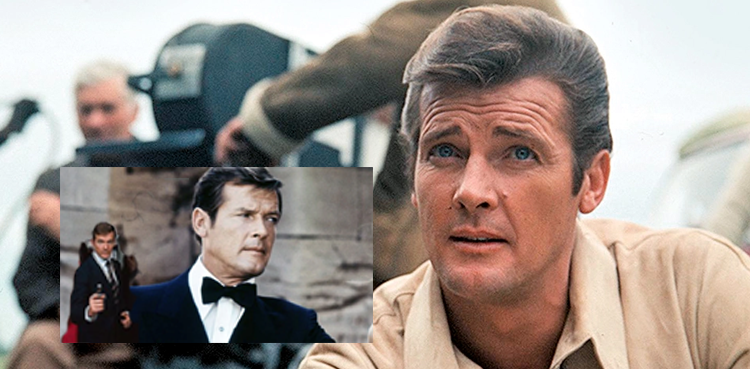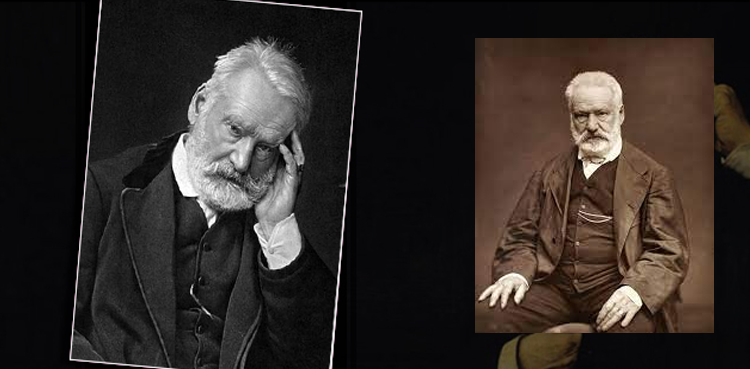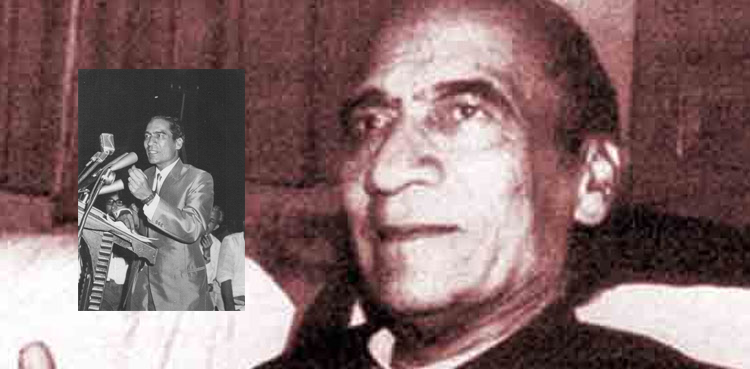ہٹلر کی موت کے اگلے روز جوزف گوئبلز نے بھی خود کُشی کر لی تھی۔ جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ میں تبدیل کرنے کے ماہر گوئبلز کو ہٹلر کا ‘وزیر برائے پروپیگنڈا’ کہا جاتا ہے۔ ہٹلر کی کام یابیوں میں گوئبلز کے پروپیگنڈے کا بڑا دخل تھا۔ گوئبلز نے یکم مئی 1945ء کو زہریلا کیپسول چبا کر اپنی زندگی ختم کر لی تھی۔
30 اپریل کو ہٹلر کی خود کشی کے بعد گوئبلز کی بیوی میگڈا گوئبلز نے اپنے پہلے شوہر سے پیدا ہونے والے بیٹے کو ایک خط ارسال کیا جس میں اسے مطلع کیا کہ وہ اپنے شوہر یعنی گوئبلز اور اپنے بچّوں کے ساتھ خودکشی کرنے والی ہے۔ گوئبلز نے صرف خود کو موت کے سپرد کرنے کا فیصلہ نہیں کیا تھا بلکہ بیوی اور بچّوں کو بھی موت کی نیند سونے پر مجبور کر دیا تھا۔
یہ یکم مئی کی ایک شام تھی۔ ایک ڈاکٹر نے گوئبلز کے چھے بچّوں، ہیلگا، ہلڈا، ہیلمٹ، ہولڈے، ہیڈا اور ہیڈے کو مارفین دی تاکہ انھیں نیند آجائے۔ یہ چار سے 12 سال کی درمیانی عمر کے تھے۔ بعد میں گوئبلز کی بیوی نے ہائیڈروجن سائینائڈ کے قطرے ان بچّوں کے حلق میں اتار دیے اور وہ سب ابدی نیند سو گئے۔ گوئبلز ایک بنکر میں اپنی بیوی میگڈا کا منتظر تھا۔ یہ کام انجام دے کر وہ بنکر پہنچی اور رات کو ساڑھے آٹھ بجے اس جوڑے سائینائڈ کا کیپسول چبایا اور دم توڑ دیا۔
سیاست اور جمہوریت کی تاریخ میں جوزف گوئبلز بہت بدنام ہے۔ وہ ایک ایسا بااثر جرمن وزیر تھا جس نے نازی دور میں جرمنی کے عوام کو ہٹلر کی حکومت اور اس کی پالیسیوں کی حمایت کرنے پر قائل کیا۔ اس کے لیے گوئبلز نے جھوٹ گھڑے اور وہ باتیں مشہور کیں جن میں کوئی حقیقت نہ تھی۔ اس نے ہٹلر کو جرمن قوم کا نجات دہندہ ثابت کرنے کے لیے فرضی واقعات اور ایسے قصّے مشہور کیے جن سے حکومتی اقدامات پر اندرونِ ملک بے چینی اور اضطراب کو جگہ نہ ملے۔ اس نے عوام کے دلوں میں یہودیوں کے خلاف نفرت کو بڑھایا اور ہٹلر کو ان کے سامنے اس طرح پیش کیا کہ وہ خود کو اقوامِ عالم میں برتر اور ہٹلر کی قیادت پر فخر کرنے لگے۔
29 اکتوبر 1897 کو جوزف گوئبلز نے جرمنی کے ایک شہر میں فریڈرک گوئبلز کے گھر میں آنکھ کھولی۔ اس کا باپ کیتھولک عقیدے کا حامل تھا اور ایک فیکٹری میں بطور کلرک کام کرتا تھا۔ گوئبلز کی ماں کا نام کیتھرینا ماریا اوڈن تھا۔ گوئبلز اس جوڑے کی پانچ اولادوں میں سے ایک تھا۔ بچپن میں پولیو وائرس سے متأثر ہونے کے بعد گوئبلز لنگڑا کر چلتا تھا۔ ابتدائی تعلیمی مراحل طے کرنے کے بعد گوئبلز نے 1920 میں ہائیڈلبرگ یونیورسٹی سے جرمن ادب میں ڈگری لی۔ وہ ایک قوم پرست نوجوان تھا۔ زمانۂ طالب علمی میں وہ سوشلسٹ اور کمیونسٹ خیالات رکھتا تھا اور جوانی میں اینٹی بورژوا تھا، لیکن نازی پارٹی میں شمولیت اختیار کرنے کے بعد گوئبلز قومی امتیاز اور جرمن ہونے کے ناتے احساسِ برتری کا شکار ہوگیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس سے قبل وہ اپنے یہودی اساتذہ کی بڑی قدر کرتا تھا اور اس کے دل میں کسی کے لیے نفرت نہیں تھی۔ پہلی عالمی جنگ چھڑی تو گوئبلز کو فوج میں بھرتی ہونے سے بچ گیا کیوں کہ وہ پولیو سے متأثر تھا۔ 1931ء میں اس نے میگڈا رِٹشل نامی ایک امیر گھرانے کی لڑکی سے شادی کرلی اور اس کے بطن سے چھے بچّوں کا باپ بنا۔
جوزف گوئبلز نے نازی پارٹی میں شمولیت اختیار کرنے کے بعد اپنی صلاحیتوں اور نازی کٹّر پن کی وجہ سے اعلیٰ قیادت کی توجہ حاصل کر لی۔ وہ ایک اعلیٰ پائے کا مقرر تھا جس نے پارٹی میں اس کی ترقی کرنے کا راستہ بنایا۔ گوئبلز کو کئی اہم ذمہ داریاں سونپی گئیں اور وہ ان سے بخوبی نمٹتا رہا۔ اس کی مستقل مزاجی، لگن اور صلاحیتوں نے اسے ہٹلر کے قریب کر دیا۔ نازی حکم راں گوئبلز کی تحریر کردہ تقاریر عوام کے سامنے پڑھنے لگا اور اس کی مقبولیت بڑھتی چلی گئی۔ سچ جھوٹ، صحیح اور غلط سے ہٹلر کو کچھ غرض نہ تھی بلکہ وہ پراپیگنڈا پر گوئبلز کی گرفت اور فن تقریر نویسی میں اس کی مہارت سے بہت متاثر تھا۔ یہی وجہ تھی کہ 1926 میں ہٹلر نے گوئبلز کو برلن میں نازی پارٹی کا ضلعی راہ نما مقرر کر دیا۔ جب نازی برسرِ اقتدار آئے تو ہٹلر نے ایک وزارت قائم کی جسے ’چیمبر آف کلچر‘ کی شکل میں عامل بناتے ہوئے گوئبلز کو اس کا سربراہ بنا دیا۔ یہ وزارت پریس اور ادب و فنون کے شعبہ جات کو مکمل طرح سے کنٹرول کرتی رہی اور اسی کے سہارے عوام کی ذہن سازی کی جانے لگی۔ گوئبلز کی کوششوں سے ملک میں نازی ازم کو فروغ اور پذیرائی نصیب ہوئی جب کہ یہودیوں سے نفرت زور پکڑ گئی۔ گوئبلز نے ریڈیو اور فلم کے ذریعے ہٹلر کو نجات دہندہ بنا کر پیش کیا اور اپنی مخالف جماعتوں اور گروہوں کے خلاف اور ہٹلر کے حق میں رائے عامّہ ہموار کی۔
یہ گوئبلز ہی تھا جس نے 1932ء میں ہٹلر کی صدارتی انتخابی مہم جدید انداز سے چلائی۔ لیکن ہٹلر انتخابات ہار گئے۔ اس کے باوجود جرمن پارلیمان میں نازی پارٹی کی نمائندگی میں اضافہ ہوا اور وہ سب سے بڑی جماعت بن گئی۔ جرمنی میں مخلوط حکومت کے قیام کے بعد ہٹلر کو چانسلر مقرر کیا گیا اور 35 سال کی عمر میں گوئبلز کابینہ میں سب سے کم عمر وزیر کے طور پر شامل تھا۔
1937ء اور 1938ء میں گوئبلز کا اثر و رسوخ مختلف وجوہات کی بنا پر کچھ کم ہو گیا تھا۔ لیکن وہ آخری وقت تک ہٹلر کے ساتھ رہا۔ گوئبلز کی خودکُشی کے ساتھ ہی ہٹلر اور اس کے دور کے کئی راز اور بہت سے جھوٹ بھی ہمیشہ کے لیے منوں مٹی تلے دفن ہوگئے۔