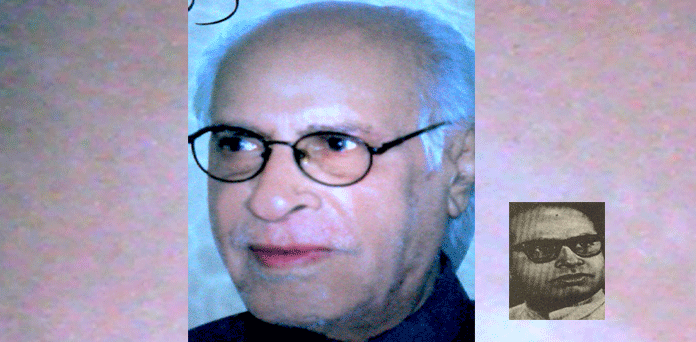سنیل دت کے آبائی گاؤں کا نام خورد ہے جو جہلم شہر سے چودہ میل کی مسافت پر واقع تھا۔ تقسیم سے قبل 6 جون 1929 کو اسی گاؤں میں سنیل دت نے آنکھ کھولی تھی اور بعد میں وہ بولی وڈ کے معروف اداکار اور فلمی ہیرو بنے۔ سنیل دت 25 مئی 2005 کو چل بسے تھے۔
معروف صحافی اور ادیب علی سفیان آفاقی نے سنیل دت کی ابتدائی زندگی، ان کے حالات اور فلمی سفر سے متعلق لکھا ہے، قیام پاکستان سے پہلے کا زمانہ بمبئی کی فلمی صنعت کے لئے ایک سنہری دور تھا۔ بڑے بڑے نامور اور کامیاب ہدایت کار، اداکار، موسیقار اور گلوکار اس دور میں انڈین فلمی صنعت میں موجود تھے۔ ہر شعبے میں دیو قامت اور انتہائی قابل قدر ہستیاں موجود تھیں۔
اس زمانے میں جو بھی فلموں میں کام کرنا چاہتا تھا، ٹکٹ کٹا کر سیدھا بمبئی کا راستہ لیتا تھا۔ ان لوگوں کے پاس نہ پیسہ ہوتا تھا، نہ سفارش اور نہ ہی تجربہ، مگر قسمت آزمائی کا شوق انہیں بمبئی لے جاتا تھا۔ ہندوستان کے مختلف حصوں سے ہزاروں نوجوان اداکار بننے کی تمنا لے کر اس شہر پہنچتے تھے۔ ان میں سے اکثر خالی ہاتھ اور خالی جیب ہوتے تھے۔ بمبئی جیسے بڑے وسیع شہر میں کسی انجانے کم عمر لڑکے کو رہنے سہنے اور کھانے پینے کے لالے پڑ جاتے تھے۔ یہی لوگ آج انڈین فلم انڈسٹری کے چاند سورج کہے جاتے ہیں جنہوں نے بے شمار چمک دار ستاروں کو روشنی دے کر صنعت کے آسمان پر جگمگا دیا۔ ( ہندوستان اور پاکستان کے بھی) اکثر بڑے ممتاز، مشہور اور معروف لوگوں کی زندگیاں ایسے ہی واقعات سے بھری ہوئی ہیں۔
آئیے آج آپ کو ایک ایسے ہی معروف اور ممتاز آدمی کی کہانی سناتے ہیں جسے بر صغیر کا بچہ بچہ جانتا ہے لیکن یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ یہ لوگ کون ہیں؟ کہاں سے آئے تھے، اور کیسے کیسے امتحانوں اور آزمائشوں سے انہیں گزرنا پڑا۔
یہ قصہ سنیل دت کا ہے۔ سنیل دت ہندوستانی لوک سبھا کا رکن رہا، نرگس بھی لوک سبھا کی رکن رہی تھی۔ ہندوستان کی وزیراعظم اندرا گاندھی سے ان کی بہت دوستی تھی اب نرگس رہیں نہ اندرا گاندھی، سنیل دت بھی نہیں رہے۔
علی سفیان آفاقی اپنے مضمون میں لکھتے ہیں، سنیل دت نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ جب وہ بمبئی پہنچے تو ان کی عمر سترہ اٹھارہ سال تھی۔ یہ انٹرویو بمبئی کی ایک فلمی صحافی لتا چندنی نے لیا تھا اور یہ سنیل دت کا آخری انٹرویو تھا۔ سنیل دت جب بمبئی پہنچے تو ان کی جیب میں پندرہ بیس روپے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ بمبئی میں در بدر پھرتے رہے۔ سب سے پہلا مسئلہ تو سَر چھپانے کا تھا۔ بمبئی میں سردی تو نہیں ہوتی لیکن بارش ہوتی رہتی ہے جو فٹ پاتھوں پر سونے والوں کے لئے ایک مسئلہ ہوتا ہے۔ بارش ہو جائے تو یا تو وہ سامنے کی عمارتوں کے برآمدے وغیرہ میں پناہ لیتے ہیں یا پھر فٹ پاتھوں پر ہی بھیگتے رہتے ہیں۔
سوال: تو پھر آپ نے کیا کیا، کہاں رہے؟
جواب: رہنا کیا تھا۔ فٹ پاتھوں پر راتیں گزارتا رہا۔ کبھی یہاں کبھی وہاں۔ دن کے وقت فلم اسٹوڈیوز کے چکر لگاتا رہا مگر اندر داخل ہونے کا موقع نہ مل سکا۔ آخر مجھے کالا گھوڑا کے علاقے میں ایک عمارت میں ایک کمرا مل گیا مگر یہ کمرا تنہا میرا نہیں تھا۔ اس ایک کمرے میں آٹھ افراد رہتے تھے جن میں درزی، نائی ہر قسم کے لوگ رات گزارنے کے لئے رہتے تھے۔
میں نے اپنے گھر والوں سے رابطہ کیا تو انہوں نے مجھے ہر مہینے کچھ روپیہ بھیجنا شروع کر دیا۔ میں نے جے ہند کالج میں داخلہ لے لیا تاکہ کم از کم بی اے تو کرلوں۔ میرا ہمیشہ عقیدہ رہا ہے کہ آپ خواہ ہندو ہوں، مسلمان، سکھ، عیسائی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں مگر ایک دوسرے سے محبت کریں۔ ہر مذہب محبت اور پیار کرنا سکھاتا ہے۔ لڑائی جھگڑا اور نفرت کرنا نہیں۔ میں کالج میں پڑھنے کے ساتھ ہی بمبئی ٹرانسپورٹ کمپنی میں بھی کام کرتا تھا۔ میں اپنا بوجھ خود اٹھانا چاہتا تھا اور گھر والوں پر بوجھ نہیں بننا چاہتا تھا۔
ان دنوں بمبئی میں بہت سخت گرمی پڑ رہی تھی۔ اتنی شدید گرمی میں ایک ہی کمرے میں آٹھ آدمی کیسے سو سکتے تھے۔ گرمی کی وجہ سے ہمارا دم گھٹنے لگتا تھا تو ہم رات کو سونے کے لئے فٹ پاتھ پر چلے جاتے تھے۔ یہ فٹ پاتھ ایک ایرانی ہوٹل کے سامنے تھا۔ ایرانی ہوٹل صبح ساڑھے پانچ بجے کھلتا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ہمیں ساڑھے پانچ بجے بیدار ہوجانا چاہیے تھا۔ ہوٹل کھلتے ہی ہماری آنکھ بھی کھل جاتی تھی۔ ایرانی ہوٹل کا مالک ہمیں دیکھ کر مسکراتا اور چائے بنانے میں مصروف ہوجاتا ۔ ہم سب اٹھ کر اس کے چھوٹے سے ریستوران میں چلے جاتے اور گرم گرم چائے کی ایک پیالی پیتے۔ اس طرح ہم ایرانی ہوٹل کے مالک کے سب سے پہلے گاہک ہوا کرتے تھے۔ وہ ہم سے بہت محبت سے پیش آتا تھا اور اکثر ہماری حوصلہ افزائی کے لئے کہا کرتا تھا کہ فکر نہ کرو، اللہ نے چاہا تو تم کسی دن بڑے آدمی بن جاؤ گے۔ دیکھو جب بڑے آدمی بن جاؤ تو مجھے بھول نہ جانا، کبھی کبھی ایرانی چائے پینے اور مجھ سے ملنے کے لئے آجایا کرنا۔ دوسروں کا علم تو نہیں مگر میں کبھی کبھی جنوبی بمبئی میں اس سے ملنے اور ایک کپ ایرانی چائے پینے کے لئے چلا جاتا تھا۔ وہ مجھ سے مل کر بہت خوش ہوتا تھا۔ میری ترقی پر وہ بہت خوش تھا۔ ایرانی چائے پینے کے بعد میں اپنی صبح کی کلاس کے لئے کالج چلا جاتا تھا۔ وہ بھی خوب دن تھے، اب یاد کرتا ہوں تو بہت لطف آتا ہے۔
ان دنوں میرے پاس زیادہ پیسے نہیں ہوتے تھے، اس لئے میں کم سے کم خرچ کرتا تھا اور کالج جانے کے لئے بھی سب سے سستا ٹکٹ خریدا کرتا تھا۔ بعض اوقات تو میں پیسے نہ ہونے کی وجہ سے اپنے اسٹاپ سے پہلے ہی اتر کر پیدل کالج چلا جاتا تھا۔
اس وقت ہماری جیب صرف ایرانی کیفے میں کھانے پینے کی ہی اجازت دیتی تھی۔ آج کے نوجوان فائیو اسٹار ہوٹلوں میں جاکر لطف اٹھاتے ہیں مگر ان دنوں ایرانی کیفے ہی ہمارے لئے کھانے پینے اور گپ شپ کرنے کی بہترین جگہ تھی۔ مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوتی تھی کہ ویٹر ایک کے اوپر ایک بارہ چائے کی پیالیاں رکھ کر کیسے گاہکوں کو تقسیم کرتا تھا۔ ایسا تو کوئی سرکس کا جوکر ہی کرسکتا ہے۔ اس کا یہ تماشا بار بار دیکھنے کے لئے بار بار اس سے چائے منگواتا تھا حالانکہ بجٹ اجازت نہیں دیتا تھا۔ ایرانی ہوٹل اس زمانے میں مجھ ایسے جدوجہد کرنے والے خالی جیب لوگوں کے لئے بہت بڑا سہارا ہوتے تھے۔ میں سوچتا ہوں کہ اگربمبئی میں ایرانی ہوٹل نہ ہوتے تو میرے جیسے ہزاروں لاکھوں لوگ تو مر ہی جاتے۔
میں پچاس سال کے بعد اپنا آبائی گاؤں دیکھنے گیا جو کہ اب پاکستان میں ہے۔ مجھے یاد ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف نے مجھے مدعو کیا تھا۔ میں نے ان سے درخواست کی کہ میں اپنا آبائی گاؤں دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ بہت مہربان اور شفیق ہیں۔ انہوں نے میرے لئے تمام انتظامات کرا دیے۔ میرے گاؤں کا نام خورد ہے ۔ یہ جہلم شہر سے چودہ میل کے فاصلے پر ہے۔ میرا گاؤں دریائے جہلم کے کنارے پر ہے اور یہ بہت خوبصورت جگہ ہے۔ گاؤں سے نکلتے ہی جہلم کے پانی کا بہتا ہوا نظارہ قابل دید ہے۔
میرے گاؤں میں بہت جوش و خروش اور محبت ملی۔ وہ سب لڑکے جو میرے ساتھ پڑھا کرتے تھے مجھ سے ملنے کے لئے آئے اور ہم نے پرانی یادیں تازہ کیں۔ میں ان عورتوں سے بھی ملا جنہیں میں نے دس بارہ سال کی بچیاں دیکھا تھا مگر اب وہ ساٹھ پینسٹھ سال کی بوڑھی عورتیں ہوچکی تھیں۔ اب میرے ساتھ کھیلنے والی بچیاں نانی دادی بن چکی تھیں۔ انہوں نے بھی بچپن کے بہت سے دلچسپ واقعات اور شرارتوں کی یادیں تازہ کیں۔
پاکستان سے جانے کے بعد میں کبھی لاہور نہیں آیا۔ کراچی تو آنا ہوا تھا۔ کراچی میں مجھے بے نظیر بھٹو کی شادی میں مدعو کیا گیا تھا۔ میری بیوی نرگس میرا گاؤں دیکھنا چاہتی تھیں۔ میں بھی اپنا گاؤں دیکھنا چاہتا تھا۔ پرانے دوستوں سے مل کر پرانی یادیں تازہ کرنا چاہتا تھا۔ وہ جاننا چاہتی تھیں کہ میں کون سے اسکول میں پڑھتا تھا اور اسکول کس طرح جایا کرتا تھا۔
میں ڈی اے وی اسکول میں پڑھتا تھا، اور چھٹی جماعت تک گھوڑے پر بیٹھ کر اسکول جاتا تھا، میرا اسکول اٹھ میل دور تھا۔ اسکول جانے کے لئے کوئی دوسرا ذریعہ نہ تھا۔ میرے پتا جی زمیندار تھے۔ ہمارے گھر میں بہت سے گھوڑے تھے۔ مجھے اسکول لے جانے والا گھوڑا سب سے الگ رکھا جاتا تھا۔
علی سفیان آفاقی مزید لکھتے ہیں: سنیل دت نے اپنی تعلیم کا سلسلہ بھی محنت مزدوری اور جدو جہد کے زمانے میں جاری رکھا تھا جو ایک دانش مندانہ فیصلہ تھا۔ بی اے کرنے کے بعد انہوں نے بہت سے چھوٹے موٹے کام کیے، فٹ پاتھوں پر سوئے لیکن ہمت نہیں ہاری۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک زمانے میں "ریڈیو سیلون” سے فلمی گانوں کا ایک پروگرام ہر روز پیش کیا جاتا تھا، جسے پاکستان اور ہندوستان میں موسیقی کے شوقین باقاعدگی سے سنا کرتے تھے۔ سیلون کا نام بعد میں سری لنکا ہوگیا۔ یہ دراصل ایک جزیرہ ہے جنوبی ہندوستان میں تامل ناڈو کے ساحل سے صرف 25 میل کے فاصلے پر۔ انگریزوں کی حکومت کے زمانے میں سارا ہندوستان ایک تھا اور سلطنت برطانیہ کے زمانے میں سیلون کو ہندوستان ہی کا حصہ سمجھا جاتا تھا، اب یہ سری لنکا ہوگیا۔
ریڈیو سیلون کو اپنا پروگرام پیش کرنے کے لئے ایک موزوں شخص کی ضرورت تھی جو بہترین نغمات پروڈدیوسرز سے حاصل بھی کرسکے۔ سنیل دت نے بھی اس کے لئے درخواست دے دی۔ صورت شکل اچھی تھی اور پنجابی ہونے کے باوجود ان کا اردو تلفظ و لب و لہجہ بہت اچھا تھا۔ اس طرح انہیں منتخب کر لیا گیا اور کافی عرصہ تک وہ ریڈیو سیلون سے گیتوں کی مالا پیش کرتے رہے۔ یہ فلم سازوں کے لئے سستی پبلسٹی تھی، اس لئے بھارتی فلم سازوں نے اس سے بہت فائدہ اٹھایا اور کشمیر سے راس کماری تک ان کے فلمی نغمات گونجنے لگے۔ جب نخشب صاحب پاکستان آئے اور انہوں نے فلم میخانہ بنائی تو اس فلم کے گانے ریڈیو سیلون سے پیش کیے گئے جس کی وجہ سے سننے والے بے چینی سے فلم کی نمائش کا انتظار کرتے رہے لیکن جب فلم ریلیز ہوئی تو بری طرح فلاپ ہوگئی حالانہ ناشاد صاحب نے اس فلم کے نغموں کی بہت اچھی دھنیں بنائی تھیں۔
(ماخوذ از ماہنامہ ‘سرگزشت’پاکستان)
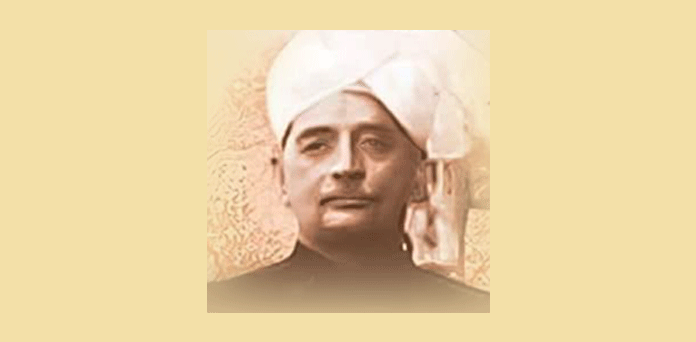
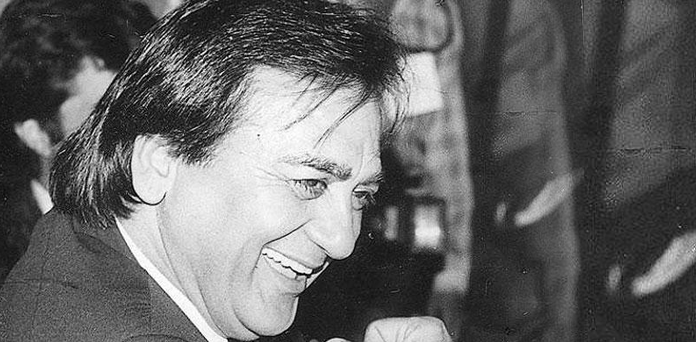
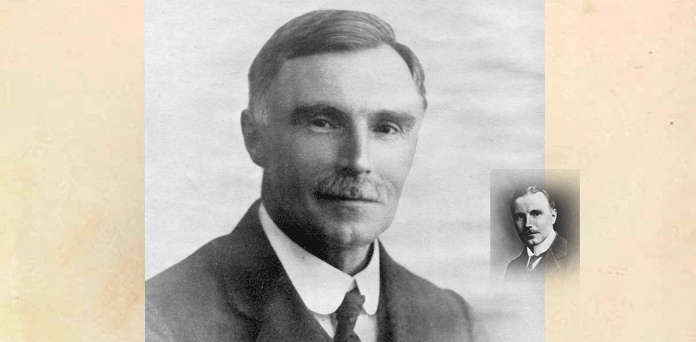
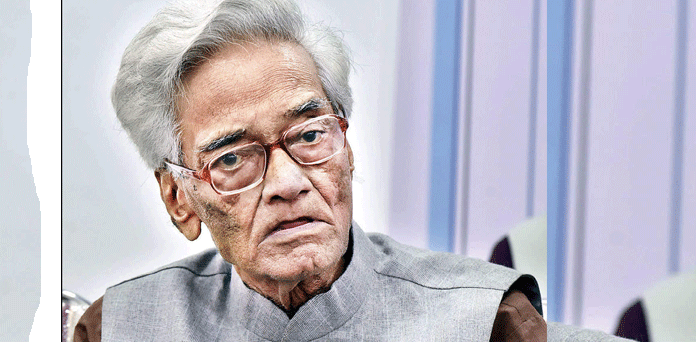
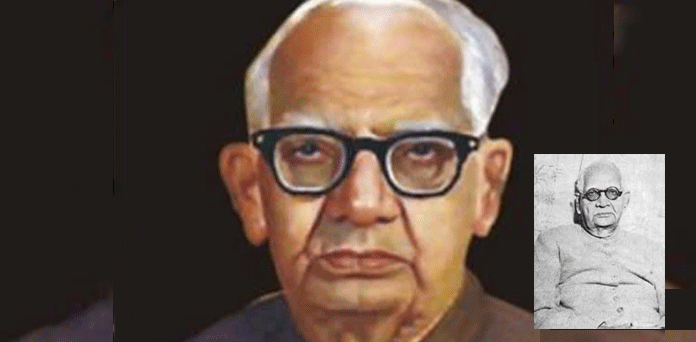
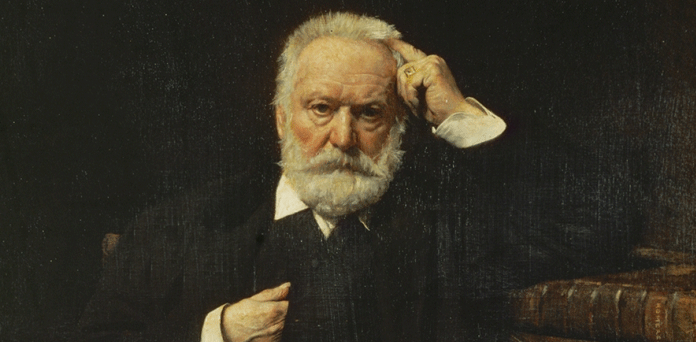

 کو ’’بابائے سندھ‘‘ کہا جاتا ہے۔ انھیں ہر طبقۂ عوام میں یکساں احترام اور پسندیدگی حاصل تھی اور انھیں عوام نے یہ لقب دیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حیدر بخش جتوئی کی زندگی غریب عوام کے حقوق کے لیے جدوجہد میں گزری جس نے انھیں ہر دل عزیز شخصیت بنا دیا تھا۔ آج ہلالِ امتیاز پانے والے کامریڈ حیدر بخش جتوئی کی برسی ہے۔
کو ’’بابائے سندھ‘‘ کہا جاتا ہے۔ انھیں ہر طبقۂ عوام میں یکساں احترام اور پسندیدگی حاصل تھی اور انھیں عوام نے یہ لقب دیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حیدر بخش جتوئی کی زندگی غریب عوام کے حقوق کے لیے جدوجہد میں گزری جس نے انھیں ہر دل عزیز شخصیت بنا دیا تھا۔ آج ہلالِ امتیاز پانے والے کامریڈ حیدر بخش جتوئی کی برسی ہے۔