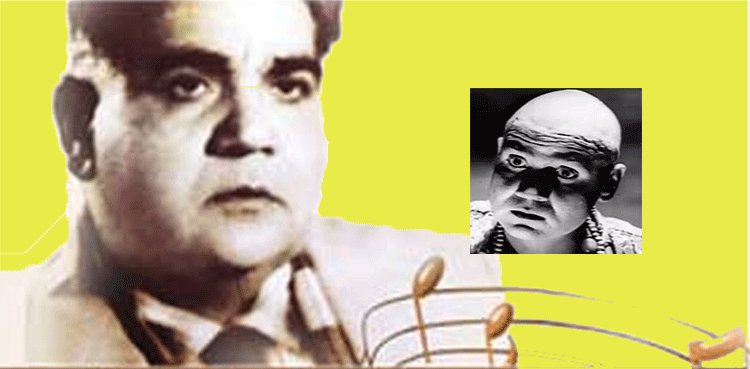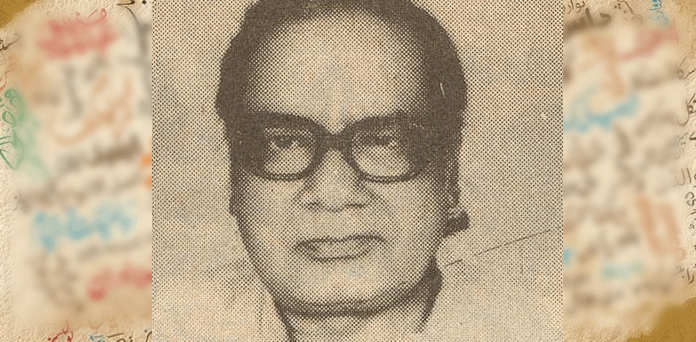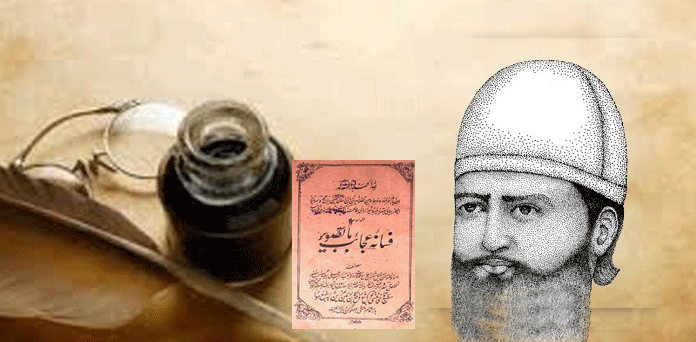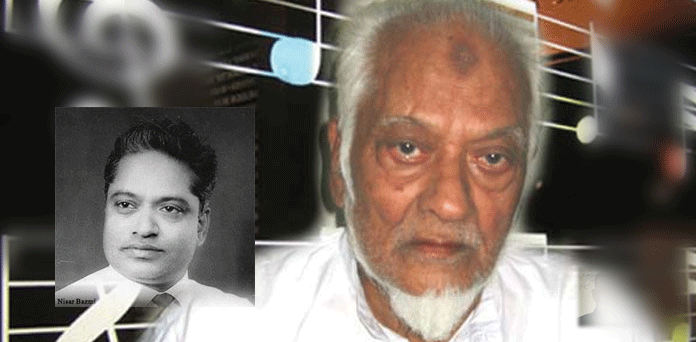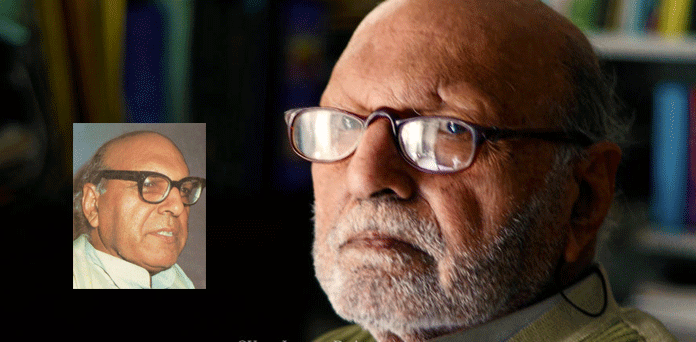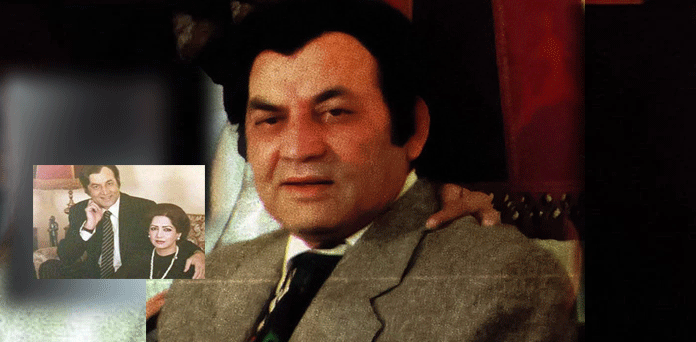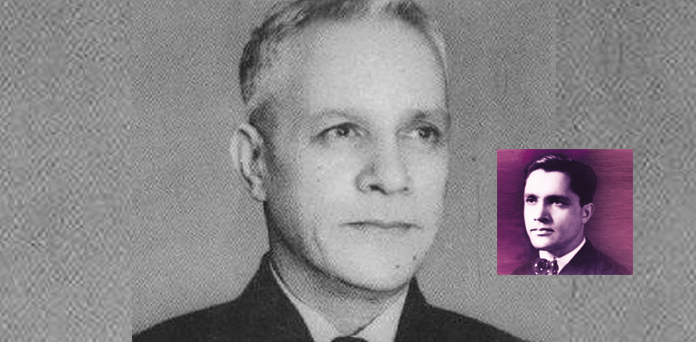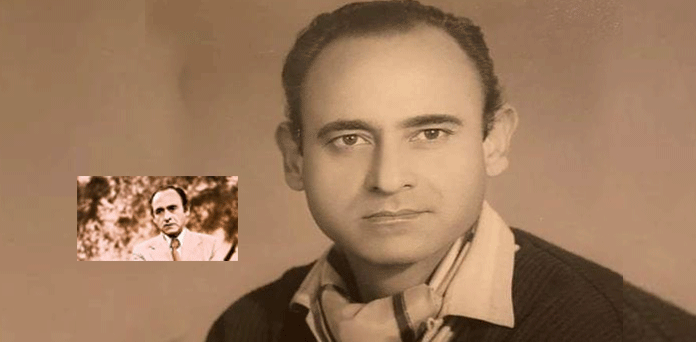پاکستان کی پہلی پنجابی فلم ’’پھیرے‘‘ تھی جو نذیر صاحب نے بنائی تھی۔ یہ فلم آج ہی کے روز 1949ء میں ریلیز ہوئی تھی۔ اس فلم کی کہانی، مکالمے اور گانے بابا عالم سیاہ پوش نے لکھے تھے اور یہ وہ نام ہے جس سے نئی نسل نامانوس بھی ہوگی اور یہ ان کے لیے ایک قسم کی پُراسراریت بھی رکھتا ہے۔ بابا عالم سیاہ پوش اور ان جیسے کئی فن کار، فلم ساز اور دوسرے آرٹسٹ ہی تھے جنھوں نے اس زمانہ میں فلمی صنعت کی بنیاد مضبوط کی اور اپنے کام کی بدولت پہچان بنائی۔
28 جولائی کو ریلیز ہونے والی فلم پھیرے کو زبردست کام یابی ملی تھی اور اس کے بعد فلم سازوں نے مزید پنجابی فلمیں بنائیں اور خوب بزنس کیا۔ یہ فلم صرف دو ماہ کے دورانیہ میں مکمل کی گئی تھی جس کے نغمات بے حد مقبول ہوئے تھے۔ پھیرے میں فلم ساز نذیر اور ان کی بیوی سورن لتا کے ساتھ بابا عالم سیاہ پوش نے بھی اداکاری کی تھی۔
بابا عالم سیاہ پوش کے فلمی گیتوں اور مکالموں میں بڑا زور تھا۔ ان کی فلمی کاوشیں پنجاب کی زرخیز مٹی کی مہک میں بسی اور اس کی ثقافت میں رنگی ہوتی تھیں جس کو پنجاب میں فلم بینوں نے بے حد پسند کیا اور فلم سازوں نے مزید پنجابی فلمیں بنائیں۔
بابا عالم سیاہ پوش 1916ء میں پیدا ہوئے۔ دستیاب معلومات کے مطابق وہ گورداسپور کے تھے۔ ان کا نام محمد حسین تھا۔ لیکن انھیں سب جوانی ہی میں "بابا” کہنے لگے تھے اور "سیاہ پوش” اس لیے کہا جانے لگا کہ ایک ناکام عشق کے بعد انھوں نے دنیا داری ترک کردی تھی۔ وہ زیادہ تر سیاہ لباس میں رہتے تھے جو غم اور سوگ کی علامت تھا۔ لیکن بعد میں ساتھیوں کے سمجھانے پر کافی حد تک بدل گئے تھے۔ وہ پنجاب یونیورسٹی کے فارغ التحصیل تھے اور پنجابی زبان پر عبور رکھتے تھے۔
سیاہ پوش تقسیم سے قبل فلم بھنور (1947) کے گیت نگار اور مکالمہ نویس کے طور پر سامنے آئے تھے۔ پاکستان میں ان کی پہلی فلم پھیرے تھی جو پہلی سپر ہٹ سلور جوبلی فلم ثابت ہوئی۔اس میں ان کا لکھا ہوا گیت عنایت حسین بھٹی نے گایا جس کے بول تھے، "جے نئیں سی پیار نبھانا، سانوں دس جا کوئی ٹھکانا۔” یہ پنجابی گیت بڑا مقبول ہوا تھا۔ پاکستان میں اپنی اوّلین کام یابی کے بعد انھوں نے بے شمار پنجابی فلموں کے لیے گیت اور مکالمے لکھے۔ یہ وہ دور تھا جب فلمی صنعت میں ان کے نام کا ڈنکا بجتا تھا۔ اس وقت کئی دوسرے پنجابی نغمہ نگار اور مکالمہ نویس بھی میدان میں اتر چکے تھے مگر بابا عالم سیاہ پوش کا انداز سب سے جدا تھا۔ ان کے تحریر کردہ پنجابی نغمات میں کئی فلمیں سپر ہٹ ثابت ہوئیں۔ ان فلموں میں چوڑیاں، دلدار، لارا لپّا، تیس مار خان، جانی دشمن، بدلہ، میرا ویر کے علاوہ کئی اور فلمیں شامل ہیں۔
بابا عالم سیاہ پوش پنجابی فلموں کے گیت نگار ہی نہیں تھے بلکہ انھوں نے اس زبان میں معیاری شاعری بھی کی اور ان کی نظمیں اس وقت کے اخبارات میں شائع ہوئیں۔سیاہ پوش کی نظموں میں سماج اور حکومت پر طنز بھی ملتا ہے۔ ان کی نظم ’’آٹا‘‘ جس زمانہ میں اخبار میں شائع ہوئی تو ممتاز دولتانہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے۔ اس نظم پر ان کے حکم سے اخبار کو نوٹس بھیجا گیا تھا۔ طنز کی شدّت سے بھرپور اس نظم کو عوام کی طرف سے بہت پذیرائی ملی تھی۔ بابا سیاہ پوش نے شہرت اور مقبولیت تو بہت حاصل کی مگر تمام عمر تنگ دست رہے۔ دراصل بابا عالم سیاہ پوش بھی فلم سازوں کی روایتی چیرہ دستیوں کا شکار رہے تھے اور رائلٹی یا معاوضہ کے معاملے میں ان کو مشکلات کا سامنا ہی رہا۔ کہتے ہیں کہ مالی تنگی کے باوجود وہ زندہ دل اور خوش اخلاق و ملنسار تھے۔ وہ ان لوگوں میں سے تھے جنھیں مایوسیوں کے اندھیروں میں بھی اُمید کی روشنی دکھائی دیتی تھی۔ دو مارچ 1970ء کو بابا عالم سیاہ پوش زندگی کی تمام پریشانیوں اور دکھوں سے نجات پا گئے تھے۔