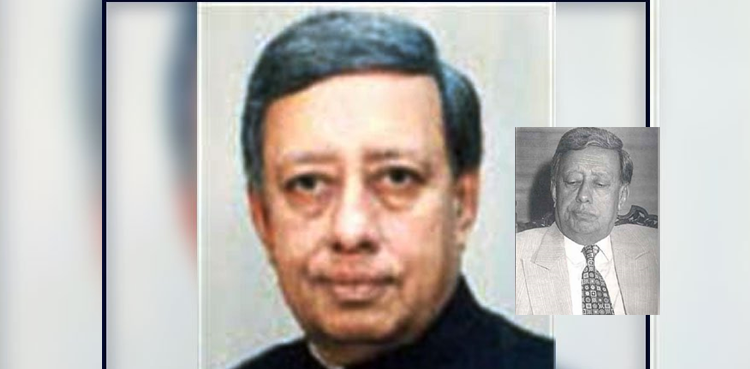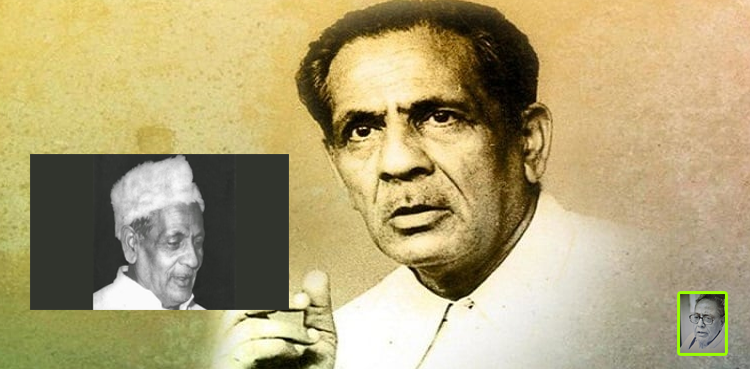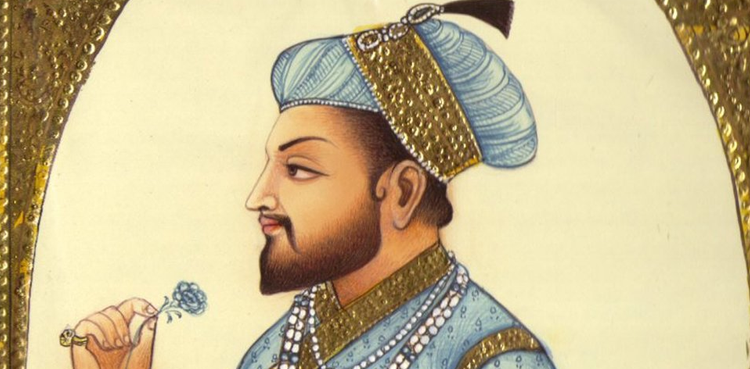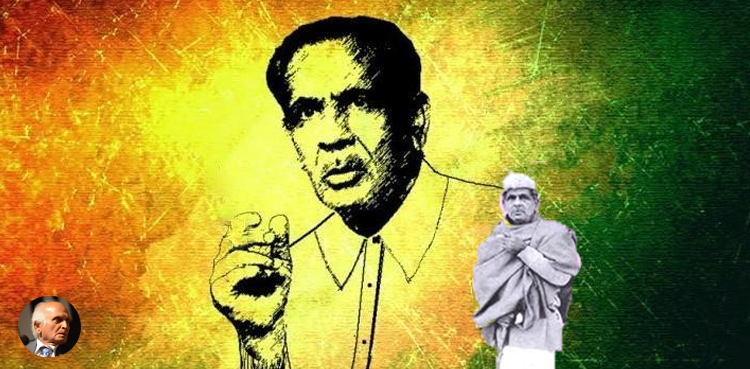جو شخص کل جوش کے گزرنے پر پھوٹ کر رو رہا تھا، وہ آج گزر گیا اور اب وہی بات جو اس نے جوش کے اٹھ جانے پر کہی تھی اس کے بارے میں درست ٹھہری ہے۔
اک ستون اور گرا ایک چراغ اور بجھا
آگے پیچھے اردو شاعری کے دو ستون گرے، دو چراغ بجھے۔
ویسے تو جوش اور فراق دونوں ہی اپنی اپنی جگہ اپنے عہد کے چراغ تھے مگر دونوں کی روشنی میں بہت فرق تھا۔ جوش پر ایک روایت ختم ہو رہی تھی، فراق سے ایک عہد شروع ہو رہا تھا۔ پابند نظم میں جتنا کچھ اظہار ہونا تھا ہو لیا۔ اب وہ آگے نہیں چل سکتی تھی کہ نئی نظم شروع ہو چکی تھی۔ جوش کے ساتھ اس نظم کا سفر تمام ہوا۔ مگر فراق صاحب جہاں سے شروع ہوئے وہاں سے غزل کا نیا سفر شروع ہوا۔ فراق صاحب کو نئی غزل کا باپ کہنا چاہیے۔
اس صدی کی تیسری دہائی میں ہماری شاعری میں نئی نظم نے اپنا ڈنکا بجایا۔ اس وقت یوں لگتا تھا کہ تخلیقی اظہار کی ساری ذمہ داری نئی نظم نے سنبھال لی ہے، غزل بس مشاعرے کی ضرورتیں پوری کیا کرے گی مگر اسی دہائی میں غزل کے ساتھ ایک واقعہ گزر گیا۔ فراق صاحب غزل گوئی تو پچھلی دہائی سے کرتے چلے آ رہے تھے۔ مگر اس دہائی میں آ کر ان کی غزل نے ایک عجیب سی کروٹ بدلی۔ اس کروٹ کا اچھے خاصے عرصے تک کسی کو پتہ ہی نہ چلا۔ مشاعرے جگر صاحب لوٹ رہے تھے۔ اس نقار خانے میں فراق کی دھیمی آواز کہاں سنی جا سکتی تھی ادھر ادبی رسالوں میں بھی بہت شور تھا۔ نظمِ آزاد کا شور انقلابی شاعری کا شور، فراق کی دھیمی آواز یہاں بھی دبی دبی تھی۔ نئی نظم والے اس وقت بہت زور دکھا رہے تھے انہیں یہ احساس ہی نہیں ہوا کہ یہ دھیمی آواز ان کی نئی شاعری کے لیے موقع کی منتظر تھی۔ ادب میں نئے رجحان کے طاقت بننے کا عمل بھی عجب ہوتا ہے۔ اکثر یوں ہوا ہے کہ کوئی نیا رجحان ابھرا اور ایک عرصہ تک اکیلی آواز طاقت پکڑ کر عہد کا رجحان بن گئی۔ فراق صاحب کی غزل میری دہائی میں اور ہمسر دہائی سے نکل کر 1947ء تک مشاعروں اور نئی نظم کے ہنگاموں کے بیچ اکیلی آواز تھی۔ بس 47ء میں جب تقسیم کا واقعہ نما ہوا تو اچانک اس اکیلی آواز کے ہمنوا پیدا ہو گئے۔ ہمنواؤں نے اس آواز کو عہد کی آواز بنا دیا۔
یہ بھی عجب ہوا کہ فراق صاحب ہندستان میں رہے اور ہمنوا پاکستان میں پیدا ہوئے۔ پاکستان کے ابھرنے کے ساتھ ناصر کاظمی کی غزل ایک نئی آواز بن کر ابھری۔ اردگرد اور آوازیں ابھریں اور اب غزل نے پھر سے اپنے عہد کے ساتھ پیوست ہو کر تخلیقی اظہار کی ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ لیکن اگر فراق صاحب نے اتنے عرصے تک اس میں اپنی جان کو نہ کھپایا ہوتا تو اس میں یہ توانائی کیسے پیدا ہوتی۔
اس ایک چراغ سے کتنے چراغ جل اٹھے
اور پھر عسکری صاحب نے اعلان کیا کہ ’’اب جو غزلیں لکھی جا رہی ہیں ان میں فراق کا دیا ہوا طرزِ احساس گونجتا ہے۔ فراق کے محاورے سنائی دیتے ہیں، فراق کی آواز لرزتی ہے۔ بالکل اس طرح جیسے غزل گو شعراء کے یہاں میر اور غالب کا احساس اور محاورہ جا بجا لپک اٹھتا ہے۔ پچھلے تین چار سال میں جو غزل کا احیاء ہوا ہے وہ 75 فیصد فراق کا مرہون منت ہے۔ فراق کی شاعری نے اردو میں ایک ادارے کی حیثیت اختیار کر لی ہے۔‘‘
فراق صاحب کی غزل کی وہ کروٹ جسے ہم نئی غزل سے عبارت کرتے ہیں عسکری صاحب کی دانست میں 28ء سے شروع ہوتی ہے۔ مگر فراق صاحب تو دوسری دہائی کے آغاز کے ساتھ شروع ہوئے تھے اس عرصہ کو ہم کس کھاتے میں ڈالیں اور اس کی توجیہ کیسے کریں۔
بات یہ ہے کہ بڑا شاعر پیدا ہوتے ہی بڑا شاعر نہیں بن جاتا یا اگر کسی شاعر کو کسی نئے رجحان کا نقیب بنتا ہے تو شروع ہی سے اسے یہ حیثیت حاصل نہیں ہو جاتی۔ ابتدائی مراحل میں تو بس کچھ پر چھائیاں نظر آتی ہیں۔ اپنے اصل مقام تک پہنچنے کے لیے اسے ریاضت کے ایک پورے عمل سے گزرنا پڑتا ہے۔ فراق صاحب کا 38ء تک کا زمانہ شاعری کی ریاضت کا زمانہ ہے۔ یہ ریاضت کس نوعیت کی تھی۔ اس کا اندازہ فراق صاحب کی اکیلی اردو غزل کی روایت سے استفادے پر قانع نہیں تھے۔ مختلف ادبی روایتوں اور مختلف تہذیبی سر چشموں سے اپنے آپ کو سیراب کر رہے تھے ان کا یہ بیان دیکھیے۔
’’میری شاعرانہ شخصیت و وجدان کی تخلیق و نشو و نما میں بہت سے اثرات شامل تھے۔ پہلا اثر سنسکرت ادب اور قدیم ہندو تہذیب کے وہ آدرش تھے جن میں مادی کائنات اور مجازی زندگی پر ایک ایسا معصوم اور روشن خیال ایمان ہمیں ملتا ہے جو مذہبی عقائد سے بے نیاز ہو کر اور بے نیاز کر کے شعور میں انتہائی گہرائی پیدا کر دیتا ہے۔
اس ضمن میں فراق صاحب کا یہ موقف بھی سنتے چلئے کہ اردو شاعری نے عربی اور فارسی سے تو بہت فیض اٹھایا ہے مگر اسے دوسری زبانوں کے ادب اور تہذیبوں میں جو آفاقی عناصر ہیں انہیں بھی اپنے اندر سمو نا چاہیے بالخصوص کالی داس، بھر تری ہری اور تلسی داس سے شناسا ہونا چاہیے۔ خیر اب ان کا دوسرا بیان دیکھیے۔
’’میری جستجو یہی رہی کہ شروع سے لے کر اب تک کی اردو غزل میں ان اشعار کو اپنی روحانی اور نفسیاتی غذا بناؤں جن میں روشن خیالی اور شرافت کوٹ کوٹ کر بھری ہو۔ قدیم یونانی تہذیب اور دوسری قدیم تہذیبوں میں جو اعلیٰ ترین فکریات مجھے مل سکیں، انہیں بھی میرے شعور اور لہجے نے اپنایا پھر جدید مغربی ادب کے جواہر پاروں نے میری زندگی اور شاعری کو مالا مال کیا۔ ‘‘
دیکھیے کہ کس طرح ایک شاعر مختلف ادبی روایتوں سے مختلف تہذیبوں سے اپنی تخلیقی روح کے لیے غذا حاصل کر رہا ہے اور اپنے فکر و احساس میں وسعت پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ عمل چھوٹا عمل تو نہیں ہے اس میں وقت تو لگتا ہی تھا اور اتفاق یا اردو شاعری کی روح کا انتظام دیکھیے کہ یہ عمل ٹھیک اس برس جا کر تکمیل کو پہنچتا ہے جب علامہ اقبال اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔
علامہ اقبال کا حوالہ میں نے یہ سوچ کر دیا کہ اس بیسوی صدی میں ہماری شعری روایت میں بلکہ ہماری ادبی روایت میں وہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے کچھ اس طور شاعری میں قدم رکھا کہ مغرب کے فکر و فلسفہ سے بھی پوری طرح سیراب تھے اور مشرق کی بالخصوص اسلام کی فکری روایت میں بھی رچے بسے تھے۔ اس طور پر انہوں نے اردو شاعری کی فکری بنیادوں کو پختہ کیا۔ وہ دنیا سے رخصت ہونے لگتے ہیں کہ ایک دوسرا شاعر اسی طور مشرق و مغرب کی عملی، ادبی اور تہذیبی روایات سے فیض پا کر غزل سراہوتا ہے یعنی اقبال کے بعد فراق دوسرے شاعر ہیں جو ایک بڑے دماغ کے ساتھ ایک علمی کمک کے ساتھ اور ایک وسیع قلب و نظر کے ساتھ اردو شاعری کی دنیا میں داخل ہوئے اسی لیے اگر ڈاکٹر گوپی چند نارنگ نے اپنے تعزیتی بیان میں فراق صاحب کو اردو ادب کا ہمالیہ پہاڑ کہا ہے تو اس میں ایسا مبالغہ نہیں ہے اور میں نے تو یہاں صرف فراق کی غزل کا ذکر کیا ہے۔ دوسری اصناف میں فراق نے کیا کہا ہے اور اردو تنقید کو اس شخص نے کیا دیا ہے، اس کا تو ذکر آیا ہی نہیں مگر یہ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جس شخص نے گھاٹ گھاٹ علم کا اور ادب کا پانی پیا ہو وہ جب تنقید لکھنے بیٹھا ہو گا تو اس نے کیا کچھ دیا ہو گا۔
اس پس منظر میں دیکھیے پھر سمجھ میں آتا ہے کہ فراق صاحب کی موت اردو ادب کے لیے کتنا بڑا سانحہ ہے سچ مچ جیسے ہمالیہ پہاڑ گر پڑا۔
ایک روشن دماغ تھا نہ رہا
شہر میں اک چراغ تھا نہ رہا
(اردو کے ممتاز فکشن رائٹر، صاحبِ طرز ادیب انتظار حسین کی ایک تحریر)