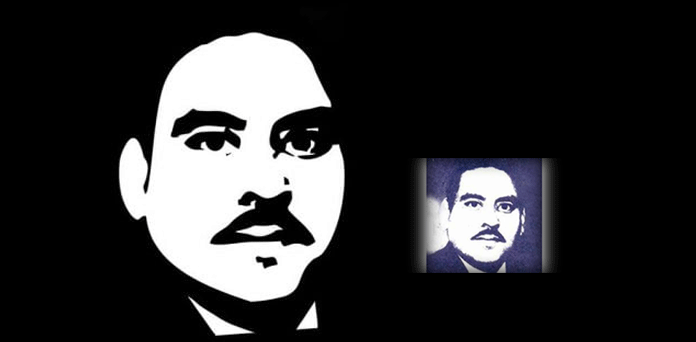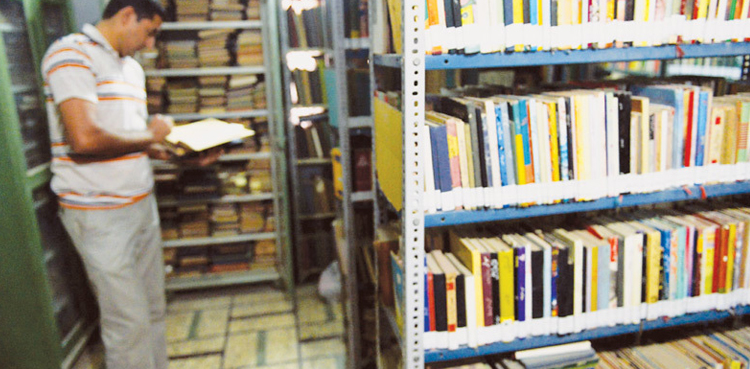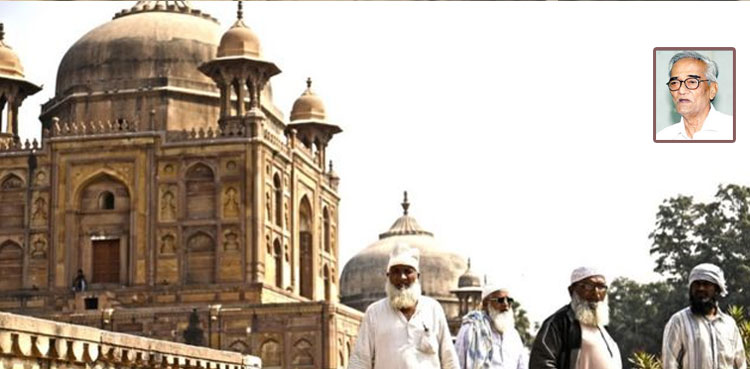راجیندر منچندا بانی کو اردو ادب میں جدید لب و لہجے والے ایسے شاعر کے طور پر یاد کیا جاتا ہے جس نے غزل کو توانا فکر سے مالا مال کیا۔
ان کا نام راجیندر منچندا تھا اور بانی تخلّص۔ وہ 1932ء کو ملتان میں پیدا ہوئے۔ بانیؔ کا خاندان تقسیمِ ہند کے بعد بھارت ہجرت کر گیا۔ وہیں 1981 میں بانی کی زندگی کا سفر تمام ہوا۔ ان کے تین شعری مجموعے منظرِ عام پر آئے جن کے نام حرفِ معتبر، حسابِ رنگ اور شفقِ شجر ہیں۔ یہاں ہم بانی سے متعلق اردو کے معروف مزاح نگار مجتبیٰ حسین کے شخصی خاکے سے چند اقتباسات پیش کررہے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں:
بانی کو میں نے جس طرح اور جس حد تک دیکھا، پایا اور سنا ہے وہ سب کچھ اس خاکے میں ہے۔ ایک بانی وہ جو بانی ہے، دوسرا بانی وہ جو منچندا ہے۔
نومبر 1972 میں جب میں دہلی آیا تو اس وقت تک میں نے ڈرتے ڈرتے بانی کا تھوڑا بہت کلام پڑھ لیا تھا۔ اور آج سربزم اس راز کا افشا کرتا چلوں کہ مجھے ان کا کلام بے حد پسند آیا تھا۔ دل میں اندیشہ تھا۔ کہ بانی سے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی موڑ پر ضرور ملاقات ہوگی۔ لہٰذا سوچا کہ ان کا مزید کلام پڑھ لینا چاہیے۔ اگر وہ اپنی شاعری کے بارے میں کبھی کوئی سوال پوچھ بیٹھیں، اور میں معقول سا جواب نہ دے سکوں تو سبکی ہوگی یوں بھی دور اندیش آدمی خطرہ کو پہلے ہی بھانپ لیتا ہے، میں بانی کے کچھ شعر یاد کر کے اور ان کے کلام کے بارے میں اپنی رائے پر مبنی چند جملے تراش کر دلّی میں بلا خوف و خطر گھومتا رہا کہ بانی اب جہاں چاہیں ملیں وہ مجھے یوں غفلت میں نہ پائیں گے۔ مگر ایک دن کسی نے بتایا کہ بانی ان دنوں موت اور زیست کی کشمکش میں مبتلا ہیں اور اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ پھر بہت عرصہ بعد ماولنکر ہال میں ریڈیو کے ایک مشاعرہ میں انہیں جناب ’’دم گفتگو صد سخن معتبر راز‘‘ نے میرا تعارف بانی سے کرایا۔ بانی انہی دنوں اسپتال سے چھوٹ کر آئے تھے۔ نقاہت کے باوجود بڑی گرم جوشی سے ملے پھر شکایت کی ’’بھئی ہم ہسپتال میں مہینوں تک موت سے لڑتے رہے مگر تم نے خبر تک نہ لی حالانکہ تمہیں دلّی آئے ہوئے تو کئی مہینے بیت گئے۔‘‘
بانی شکایت کرتے رہے اور میں نظر جھکائے بانی کے کلام کے بارے میں ان جملوں کو یاد کرنے کی ناکام کوشش کرتا رہا جو میں نے کبھی حفظ کر رکھے تھے۔ خدا دشمن کو بھی کمزور حافظہ نہ دے۔ پھر بانی سے کافی ہاؤس، ادبی جلسوں اور مخصوص بیٹھکوں میں ملاقاتیں ہونے لگیں۔ بانی کو میں نے ہر دم ایک سیدھے سادے اور معصوم آدمی مگر ایک سرکش اور چوکس شاعر کے روپ میں پایا۔ ایسا شاعر جس کے سامنے ہر دم اس کی شاعری رہتی ہے۔ بانی کی شاعری مال عرب ہے جو ہمیشہ پیش عرب رہتا ہے۔
مجھے یاد ہے کہ ایک دن میں اپنے ایک حیدر آبادی دوست کے ہمراہ کافی ہاؤس گیا تو دیکھا کہ بانی دوستوں میں گھرے بیٹھے ہیں۔ مسئلہ کچھ یوں زیر بحث تھا کہ بانی فلاں مشاعرہ میں کیوں نہیں گئے۔ بحث پہلے سے جاری تھی اور جب ہم ٹیبل پر پہنچے تو بانی دوستوں سے یوں مخاطب تھے۔ ’’بھئی بانی صاحب کو تم جانتے ہی ہو۔ وہ کیوں اس طرح کے مشاعروں میں جانے لگیں۔ بانی صاحب کو لوگوں نے سمجھ کیا رکھا ہے۔ بانی صاحب کا اپنا ایک الگ مقام ہے۔ بانی صاحب بہرحال بانی صاحب ہیں۔‘‘ غرض وہ بڑی دیر تک بانی صاحب ہی کی باتیں کرتے رہے۔ پھر وہ ٹیبل سے اٹھ کر چلے گئے۔ جب وہ چلے گئے تو میرے حیدرآبادی دوست نے کہا ’’یار بانی تو دہلی میں ہی رہتے ہیں۔ ان سے ملنے کی بڑی تمنا ہے۔ بڑا اشتیاق ہے۔ پھر ابھی جو صاحب اٹھ کر گئے ہیں۔ انھوں نے تو اس آتش شوق کو اور بھی بھڑکا دیا ہے۔ یار ہماری ان سے ملاقات تو کرا دو۔‘‘ محفل میں زور دار قہقہے بلند ہوئے اور میں نے اپنے دوست کو بتلایا۔ ’’میاں یہ جو صاحب ابھی تمہاری آتش شوق کو بھڑکا رہے تھے وہ اصل میں بانی صاحب ہی تھے۔ بانی صاحب کے راستہ میں خود بانی صاحب حائل ہیں۔ اب یہ تمہاری بدقسمتی ہے کہ ان سے ملاقات نہ ہو سکی۔‘‘
اور میرا دوست حیران اور پھٹی پھٹی نگاہوں سے ہمارے قہقہوں کو دیکھتا رہ گیا۔ میں یہ بات مذاق میں نہیں بلکہ بڑی سنجیدگی کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ احتشام حسین مرحوم سے لے کر باقر مہدی اور شمس الّرحمن فاروقی تک سب ناقد بانی کے سچے قدردان ہیں۔ موخرالذکر دوناقدوں کی قدردانی کا میں چشم دید گواہ بھی ہوں۔
ڈاکٹر نارنگؔ کے گھر پر ایک محفل میں جب بانی سے کلام سنانے کی فرمائش کی گئی تو شمس الّرحمن فاروقی نے کہا تھا۔ یہ کیسے ہوسکتا ہے، بانی اپنے رتبہ کے اعتبار سے آخر میں کلام سنائیں گے۔ پہلے میں سنائے دیتا ہوں۔‘‘