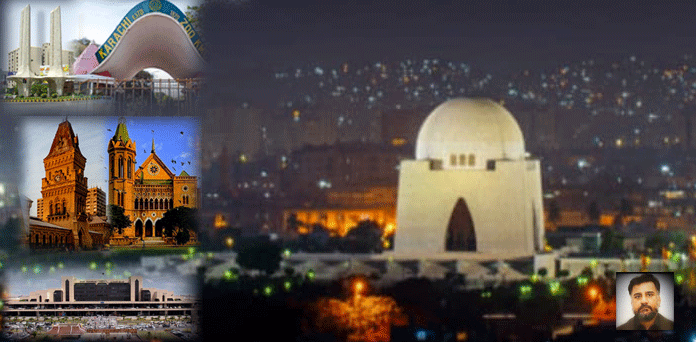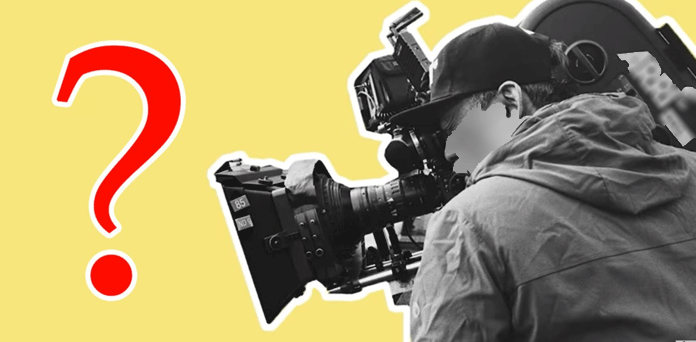تحریر: محمد عثمان جامعی
سہیل احمد صدیقی سے میرا تعلق سولہ سترہ سال پر محیط ہے، اس دوران میں نے جب بھی ان کو دیکھا تو یہ خیال آیا اے کمال افسوس ہے، تجھ پر کمال افسوس ہے۔ اردو، انگریزی، سندھی پر مکمل دسترس، فرنچ سے گہری شناسائی، فارسی اور عربی کے لسانی رموز سے واقف۔ تخلیق سے تحقیق تک علم وادب کے ہر میدان میں گام زن، تحریر ہی نہیں تقریر کے فن میں بھی طاق، مگر ان ساری صلاحیتوں اور اہلیتوں کے باوجود کبھی روزگار کے مسائل سے جھوجھتے، کبھی معاشی تنگی سے پریشان۔ لیکن زندگی کے جھمیلے ہوں، شکستوں کی تکان ہو، دل شکن بے قدری ہو یا پھن اٹھائے اور ڈنک مارتے رویے، کوئی رکاوٹ علم کے سفر میں ان کے آڑے نہ آسکی، مشکلات کی کوئی آندھی ان کی ہمت کا پرچم سرنگوں نہ کرسکی اور برف زاروں کی خنکی سمیٹی سرد مہری اور بے اعتنائی کا چلن ان کے سینے میں دہکتی لگن کی اگن بجھانے میں ناکام رہا۔
دراصل یہ ان کا عشق ہے جو انھیں حالات کی زہرناکیوں سے بچائے اور اپنے رستے پر لگائے رکھتا ہے، ان کا عشق انھیں صحرا کی ریت میں گُم ہونے دیتا ہے نہ تیشہ دے کر کسی کوہسار کی طرف بھیجتا ہے، وہ تو ان سے اور بھی بڑی مشقت لے رہا ہے، طبیعتوں اور مزاجوں کی ریگ میں زبان کے پھول کھلانے اور پتھریلے دماغوں میں برگِ گُل سے بھی نازک لفظوں سے زبان کی آبیاری کی کَڑی مشقت، جو انھیں تھکاتی ہے نہ اکتاہٹ کا شکار کرتی ہے۔ یہ اردو کا عشق ہے، جس نے انھیں مار رکھا ہے، اور ”زباں فہمی“ کا سلسلہ اس عشق کا اظہار بھی ہے، مظہر بھی اور داستان بھی۔

’زباں فہمی“ کے زیرعنوان شایع ہونے والی تحریریں اردو کی بے وقعتی، بے قدری، اس سے تعصب کا ایک ایسا تقاضا تھیں جسے سہیل احمد صدیقی جیسا کوئی ذی علم اور زبان کے ہر رنگ اور سارے تیوروں سے واقف قلم کار ہی نبھا سکتا تھا، جنھوں نے صحافتی مضمون نگاری سے ادبی نثرپاروں تک اور ٹیلی ویژن اور ریڈیو کے اسکرپٹ لکھنے سے اشتہار نویسی تک زبان کے پھیکے، تیکھے، میٹھے، مرچیلے اور نکمین سارے ذائقے چکھے بھی ہیں اور چکھائے بھی ہیں۔

یوں کہہ لیں کہ انھوں نے اردو نگری کے گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہے۔ پیا ہی نہیں، مشکیزوں میں بھر بھر کر ساتھ لائے بھی ہیں اور اب اس پانی سے لفظوں کے آلودہ چہرے دھو کر ان کا اصل رنگ روپ سامنے لانے میں مصروف ہیں۔ ہمیں گمان نہیں یقین ہے کہ انھوں نے گھاٹ گھاٹ پھرتے ہوئے پنگھٹوں پر بھی اوک سے پانی پیا ہوگا، اس کے بغیر زباں دانی اور شاعری کا سفر کہاں مکمل ہوتا ہے، اور یہ ان دونوں راہوں کے مسافر ہیں۔ زبان کی ہر ادا سے شناسائی کے ساتھ اردو کے آب رواں میں اپنے اپنے رنگ گھول کر اسے رنگا رنگ کرنے والی زبانوں میں سے کسی پر عبور اور کسی سے اچھی خاصی یاد اللہ کے باعث سہیل احمد صدیقی کسی ماہر کھوجی کی طرح لفظوں کے نقش پا پر اُلٹے قدموں چلتے ہوئے اس کا ٹھور ٹھکانا ڈھونڈ نکالتے ہیں اور تجربہ کار صرّاف کے مانند محاوروں اور شعروں میں اصل اور کھوٹ کی کھوج لگا لیتے ہیں۔
یہ تحقیقی کاوشیں اپنی جگہ اہم ہیں، مگر ”زباں فہمی“ کے خالق کی اصل خدمت اردو میں بگاڑ کی یلغار کا مقابلہ اور اسے انگریزی کی مسلسل پیش قدمی سے بچانے کے لیے جدوجہد ہے۔ یہ کام جتنا ناگزیر ہے، اتنا ہی کٹھن بھی، ایسا دشوار کہ اچھے اچھوں نے یہ بھاری صرف پتھر چوم کر چھوڑ دیا، کوئی اسے کارِ عبث سمجھتا ہے تو کوئی دیوار سے سر ٹکرانا قرار دیتا ہے۔ مگر سہیل احمد صدیقی اس جنگ کے باہمّت سالاروں شکیل عادل زادہ، احفاظ الرحمٰن اور اطہر ہاشمی کی روش اپنائے ہوئے مسلسل برسرِ پیکار ہیں۔ ذرا تصور تو کیجیے ان کی ہمّت اور حوصلے کا، یہ ایک ایسے معاشرے میں زبان کے خد و خال بگڑنے سے بچانے اور مسخ ہوجانے والے نقوش کی بحالی کے لیے دن رات ایک کیے ہوئے ہیں، جس معاشرے میں غلط اردو بولنا قابلِ فخر ہے، جہاں والدین بڑی شان سے بتاتے ہیں کہ ان کے بچے کی اردو خراب ہے، جہاں شادی کے دعوت نامے سے گھر کی دیوار پر لگی نام کی تختی تک ہر جگہ اردو میں عبارت لکھنا باعثِ شرم سمجھا جاتا ہے، اس بدقسمت زبان کے الفاظ قبروں کے کتبوں ہی پر نظر آتے اور یہ بتاتے ہیں کہ یہ قوم، یہ سماج اب اردو کو گورستان میں دیکھنے کا متمنی ہے۔
سہیل احمد صدیقی ایک ایسی قوم میں زبان کی اصلاح کا بِیڑا اٹھائے ہوئے ہیں، زبان کا بیڑا غرق ہونا جس کے لیے ذرا برابر اہمیت نہیں رکھتا، وہ ایک ایسے ملک میں حرف و معنی کے احترام کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں جس کے ٹی وی چینل، اخبارات اور ویب سائٹس روز کسی لفظ کسی محاورے کی عزت پامال کردیتے ہیں، وہ ایسے سماج میں صحیح اردو بولنے اور لکھنے کے لیے سرگرم ہیں جس کا ایک شاعر اور زبان کا مجتہد جون ایلیا اپنے بیٹے کے لیے فکرمند ہوکر کہتا ہے نجانے تم کتنی کم غلط اردو لکھی ہوگی۔ میرے ممدوح اس دیس میں اشعار میں سہواً تبدیلیوں اور شعروں کی غلط نسبت کو درست کرنے کے لیے جگر سوزی کر رہے ہیں، جس دیس کے ایک نہایت اعلی منصب دار، اتنے اعلٰی کے باقی اہل جاہ و منصب بس ان کے آلۂ کار، ایک تقریر میں فتنوں کا سر کچلنے کی دھن میں کسی اور کے شعر علامہ اقبال کے سر منڈھ دیتے ہیں، جس پر اقبال نے اپنی لحد میں تڑپ کر کہا ہوگا، ”تقریر جو ایسی ہو تو تقریر بھی فتنہ۔“ وہ اس زبان کی محبت کا فرض چکا رہے ہیں جس کے طفیل شہرت اور دولت کمانے والے کچھ اہلِ قلم کے دل بھی اس کی نفرت سے یوں بھرے ہیں کہ بغض کی یہ غلاظت جب ہونٹوں سے بہتی ہے تو یہ غلیظ ”بہاﺅ“ دیکھ کر ان کی شخصیت کا سارا تاثر ”راکھ“ ہوجاتا ہے۔ ایسے ماحول اور حالات میں یہ زبان کا فہم بانٹنے کے لیے کمربستہ ہیں تو یہ ان کے عشق ہی کی کارستانی ہے۔
زباں فہمی کا سلسلہ زبان کی اصلاح اور اردو شناسی کا ذریعہ تو ہے ہی یہ سہیل احمد صدیقی کی پوری کی پوری شخصیت کا منی ایچرز پر مشتمل تصویر خانہ بھی ہے۔ اس میں ان کی شخصیت کے پہلو، افکار، ان کی نجی اور پیشہ ورانہ زندگی کے اتار چڑھاﺅ، ان کے علمی سروکار اور معلومات کی وسعت کی جھلکیاں جا بہ جا جلوے دکھاتی ہیں۔ جب یہ کسی لفظ کی اصل کا سراغ لانے نکلتے ہیں تو ان کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے ہم مذہب، تاریخ، ثقافت جغرافیے کے کتنے ہی حقائق سے گزرتے ہیں۔ کبھی لفظوں کا یہ تعاقب قاری کو نباتات کی دنیا میں لے جاتا ہے، کبھی رنگوں کی نیرنگی اس کے سامنے ہوتی ہے، کہیں تاریخ کا کوئی ورق کھل جاتا ہے، کہیں کسی مذہبی کتاب کا صفحہ الٹ جاتا ہے، پھل، سبزیاں، پکوان، شہر، شخصیات، صحافت کون سا موضوع ہے جس کے بارے میں مضامین کسی انکشاف کا دریچہ نہیں کھولتے۔ اپنے مطالعے اور معلومات سے ہمیں حیران کرتے سہیل احمد صدیقی کے بارے میں جب پتا چلتا ہے کہ زندگی کی آزمائشوں میں پڑنے سے پہلے وہ ذہنی آزمائش کے مقابلوں کے فاتح رہے ہیں، تو ساتھ ہی یہ عقدہ بھی کھل جاتا ہے کہ کیریئر اور دولت کے پیچھے بھاگتے نوجوانوں کے بیچ دھیرج سے علم کی راہوں پر چلتے لڑکے کو یہ چسکا کیسے پڑا۔
زباں فہمی کا مطالعہ کرتے ہوئے ہم اردو کے بھید بھاﺅ اور اس کے دیگر زبانوں سے رشتے ناتوں پر صاحبِ کتاب کی گہری نظر سے فیض یاب ہونے کے ساتھ ان کے اسلوب کی رنگارنگی سے بھی لطف اٹھاتے ہیں، جو کبھی محققانہ بردباری اور بھاری پن لیے ہوتا ہے تو کہیں صحافتی ڈھنگ اختیار کرلیتا ہے، کہیں ان کے قلم سے نکلی سطور مؤرخ کے ڈھب پر بال کی کھال اتارنے پر تل جاتی ہیں تو کہیں ہمیں ایک مزاح نگار کی سی شگفتگی اور ہلکے پھلکے انداز سے واسطہ پڑتا ہے۔ اور جب جب وہ اپنی جیون کہانی کا کوئی ٹکڑا تحریر میں جماتے ہیں تو لفظوں میں کسی قصہ گو کی فن کاری بول اٹھتی ہے۔ یہ سارے بدلاﺅ اور سبھاﺅ موضوعات کے تابع اور ان کے تقاضوں کے مطابق ہوتے ہیں، جس سے پتا چلتا ہے کہ بہ طور قلم کار وہ اکہری شخصیت کے مالک نہیں بلکہ موضوع کے مطابق زبان کو برتنے کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں۔
سہیل احمد صدیقی اور ان کے قدردانوں اور ان سے پیار کرنے والوں کو زباں فہمی (نقش اوّل) کی اشاعت پر مبارک باد دیتے ہوئے میں آرزومند اور دعا گو ہوں کہ سہیل صاحب زباں فہمی کی یہ قلمی اور علمی تحریک جاری رکھیں اور کتابوں کی صورت ان کی تحریریں نقش در نقش اردو کے علمی و ادبی ورثے کا حصہ بنتے رہیں۔