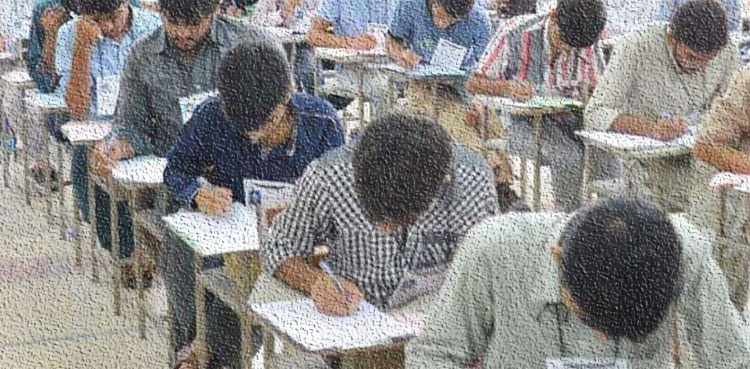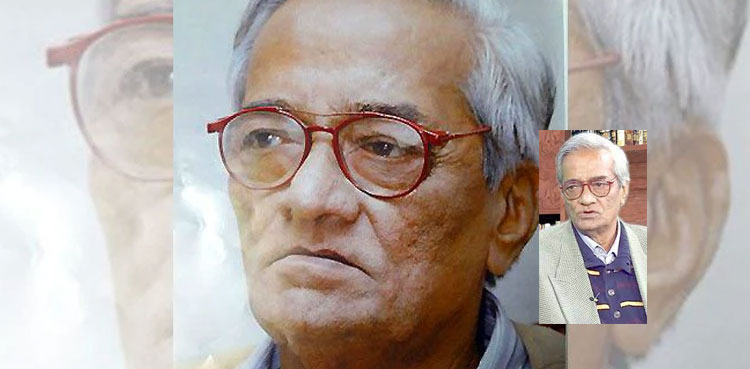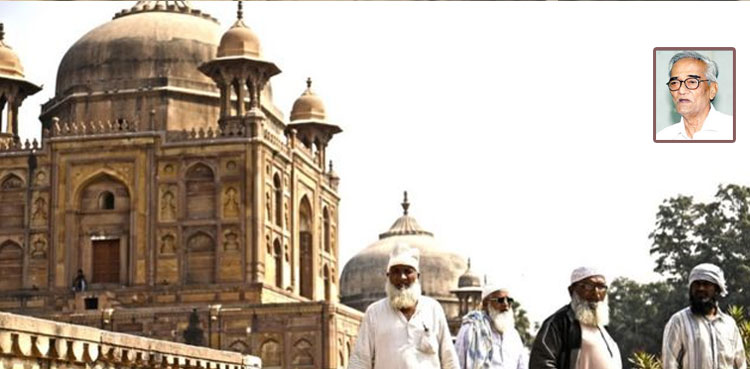چراغ حسن حسرتؔ کی نثر کے بارے میں شورش کاشمیری لکھتے ہیں، ’’وہ نثر کی ہر صنف پر قادر تھے، سیرت بھی لکھی، افسانے بھی تحریر کیے، تاریخ پر بھی قلم اٹھایا۔ بچّوں کا نصاب بھی لکھا۔‘‘
26 جون 1955 کو مولانا چراغ حسن حسرت لاہور میں انتقال کر گئے تھے۔ آج اس ممتاز ادیب و شاعر اور جیّد صحافی کی برسی منائی جارہی ہے۔ مزاحیہ مضامین اور فکاہیہ کالم ان کی خاص وجہِ شہرت ہیں۔
چراغ حسن حسرت 1904 میں کشمیر میں پیدا ہوئے تھے۔ اسکول کے زمانے میں شاعری کی طرف راغب ہوئے، فارسی پر عبور اور عربی جاننے کے ساتھ اردو زبان و بیان پر قدرت رکھتے تھے اور پاکستان ہجرت کرنے کے بعد یہاں اردو اور فارسی کی تدریس سے منسلک ہوگئے۔ اسی زمانے میں عملی صحافت کا سلسلہ شروع ہوگیا اور متعدد اخبارات میں کام کرنے کے ساتھ ادبی جرائد کے لیے لکھنے لگے اور ادارت بھی کی جن میں ’’انسان، زمیندار، شیراز اور شہباز‘‘ شامل ہیں۔ انھیں شملہ اور کلکتہ میں بھی تدریس اور صحافت کے شعبے میں اپنے تجربے اور علم و قابلیت کا مظاہرہ کرنے کا موقع ملا۔
حسرت نے مختلف قلمی ناموں سے لکھا جن میں ’’کولمبس، کوچہ گرد، اور سند باد جہازی‘‘ مشہور ہیں۔ ان ناموں سے حسرت کی تحریریں ہر خاص و عام میں مقبول ہوئیں اور ان کا طرزِ نگارش اور دل چسپ و شگفتہ انداز ان کی شہرت میں اضافہ کرتا چلا گیا۔
مولانا چراغ حسن حسرت کی تصانیف اردو ادب کا گراں قدر سرمایہ ہیں۔ ان کی کتابوں میں کیلے کا چھلکا، پربت کی بیٹی، مردم دیدہ، دو ڈاکٹر اور پنجاب کا جغرافیہ و دیگر شامل ہیں۔
چراغ حسن حسرتؔ کی نثر مختلف النّوع موضوعات پر مشتمل ہے۔ وہ سنجیدہ، خالص ادبی اور رومانوی مضامین کے ساتھ طنز و مزاح لکھتے تھے۔ اس کے علاوہ خاکہ نویسی، تراجم، تبصرے اور تحقیقی مضامین بھی ان کے زورِ قلم کا نتیجہ ہیں۔ حسرت کو ان کے فکاہیہ مضامین اور ظرافت آمیز کالموں سے خوب شہرت ملی۔ چراغ حسن حسرتؔ نے لاہور کے روزناموں سے مزاحیہ کالموں کا سلسلہ کم و بیش چودہ پندرہ برس جاری رکھا۔
انھوں نے زیادہ تر اپنے ماحول اور اردگرد بکھرے ہوئے موضوعات کو اپنے کالموں میں پیش کیا ہے۔ وہ اپنی تحریروں میں زور اور اثر پیدا کرنے کے لیے محاورہ، تشبیہ، استعارہ اور ضربُ الامثال سے خوب کام لیتے تھے۔
ایک ادیب، ایک صحافی، انشا پرداز اور ایک تاریخ نگار کی حیثیت سے جہاں انھوں نے قارئین کی بڑی تعداد کو اپنا گرویدہ بنا لیا تھا، وہیں وہ علم و ادب کی دنیا اور اپنے قریبی احباب میں اپنی بادہ نوشی اور بعض عادات کی وجہ سے مطعون بھی کیے جاتے تھے۔
اردو کے نام وَر افسانہ نگار سعادت حسن منٹو بھی چراغ حسن حسرت کے بے تکلّف دوستوں میں شامل تھے، اور ان کا ایک خاکہ لکھا تھا جس سے چند پارے ہم یہاں نقل کررہے ہیں۔
"مولانا چراغ حسن حسرت جنہیں اپنی اختصار پسندی کی وجہ سے حسرت صاحب کہتا ہوں۔ عجیب و غریب شخصیت کے مالک ہیں۔ آپ پنجابی محاورے کے مطابق دودھ دیتے ہیں مگر مینگنیاں ڈال کر۔ ویسے یہ دودھ پلانے والے جانوروں کی قبیل سے نہیں ہیں حالانکہ کافی بڑے کان رکھتے ہیں۔
آپ سے میری پہلی ملاقات عرب ہوٹل میں ہوئی۔ جسے اگر فرانس کا ’’لیٹن کوارٹر‘‘ کہا جائے تو بالکل درست ہوگا۔ ان دنوں میں نے نیا نیا لکھنا شروع کیا تھا اور خود کو بزعمِ خویش بہت بڑا ادیب سمجھنے لگا تھا۔ عرب ہوٹل میں تعارف مظفر حسین شمیم نے اُن سے کرایا۔ یہ بھی حسرت صاحب کے مقابلے میں کم عجیب و غریب شخصیت نہیں رکھتے۔ میں بیمار تھا۔ شمیم صاحب کی وساطت سے مجھے ہفتہ وار’’پارس‘‘ میں جس کے مالک کرم چند تھے، ملازمت مل گئی۔ تنخواہ چالیس روپے ماہوار مقرر ہوئی مگر ایک مہینے میں بمشکل دس پندرہ روپے ملتے تھے۔ شمیم صاحب اور میں ان دنوں دوپہر کا کھانا عرب ہوٹل میں کھاتے تھے۔
ایک دن میں نے اس ہوٹل کے باہر تھڑے پر وہ ٹوکرا دیکھا جس میں بچا کھچا کھانا ڈال دیا جاتا تھا۔ اس کے پاس ایک کتا کھڑا تھا۔ ہڈیوں اور تڑی مڑی روٹیوں کو سونگھتا، مگر کھاتا نہیں تھا۔ مجھے تعجب ہوا کہ یہ سلسلہ کیا ہے۔
شمیم صاحب نے جب حسرت صاحب سے میرا تعارف کرایا اور ادھر ادھر کی چند باتیں ہوئیں، تو میرے استفسار پر بتایا کہ اس کتّے کی محبت ایک سانڈ سے ہے۔ مجھے بہت حیرت ہوئی لیکن میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ان دو حیوانوں میں دوستی تھی۔ سانڈ ساڑھے بارہ بجے دوپہر کو خراماں خراماں آتا، کتّا دُم ہِلا ہلا کر اس کا استقبال کرتا اور وہ ٹوکرا جس کا میں ذکر کر چکا ہوں، اس کے حوالے کردیتا۔ جب وہ اپنا پیٹ بھر لیتا جو کچھ باقی بچ جاتا اس پر قناعت کرتا۔
اس دن سے اب تک میری اور حسرت صاحب کی دوستی، اس سانڈ اور کتّے کی دوستی ہے۔ معلوم نہیں حسرت صاحب سانڈ ہیں یا میں کتّا۔ مگر ایک بات ہے کہ ہم میں سے کوئی نہ کوئی سانڈ اور کتا ضرور ہے لیکن ہم میں اکثر لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں جو ان دو حیوانوں میں شاید نہ ہوتی ہوں۔
حسرت صاحب بڑی پیاری شخصیت کے مالک ہیں۔ میں ان سے عمر میں کافی چھوٹا ہوں لیکن میں انہیں بڑی بڑی مونچھوں والا بچّہ سمجھتا ہوں۔ یہ مونچھیں صلاح الدین احمد صاحب کی مونچھوں سے بہت ملتی جلتی ہیں۔
حسرت صاحب کہنے کو تو کشمیری ہیں مگر اپنے رنگ اور خدوخال کے اعتبار سے معلوم نہیں کس نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ فربہ اندام اور خاصے کالے ہیں۔ معلوم نہیں کس اعتبار سے کشمیری ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں؟
ویسے مجھے اتنا معلوم ہے کہ آپ آغا حشر کاشمیری کے ہم جلیس تھے۔ علامہ اقبال سے بھی شرفِ ملاقات حاصل تھا جو کشمیری تھے۔ خاکسار بھی ہیں جس سے ان کی’’سانڈ اور کتے‘‘ کی دوستی ہے لیکن اس کے باوجود اگر یہ ثابت کرنا چاہیں کہ خالص کشمیری ہیں تو کوئی کشمیری نہیں مانے گا۔ حالانکہ انہوں نے کشمیر پر ایک کتاب بھی لکھی ہے۔
یہ کتاب میں نے پڑھی ہے۔ میں عام طور پر بڑا برخود غلط انسان متصور کیا جاتا ہوں لیکن مجھے ماننا پڑتا ہے اور آپ سب کے سامنے حسرت صاحب بڑی دلفریب اندازِ تحریر کے مختار اور مالک ہیں۔ بڑی سہلِ ممتنع قسم کے فقرے اور جملے لکھتے ہیں۔ پر ان کی ان پیاری تحریروں میں مجھے ایک بات کھٹکتی ہے کہ وہ ہمیشہ استادوں کا طریقۂ تعلیم استعمال کرتے ہیں۔ ان کے بے شمار شاگرد موجود ہیں جو شاید ان کے علم میں نہ ہوں مگر ان کی خواہش ہے کہ وہ ہر بچّے، نوجوان اور بوڑھے پر رعب جمائیں اور اس کا کاندھا تھپکا کر اسے یہ محسوس کرنے پر مجبور کریں کہ وہ ان کا برخوردار ہے۔ مجھے ان کی طبیعت کا یہ رخ سخت ناپسند ہے، اسی وجہ سے میری اور ان کی لڑائی ہوتی رہی ہے۔
اردو کے صفِ اوّل کے طنز نگار چراغ حسن حسرت لاہور کے میانی صاحب کے قبرستان میں آسودۂ خاک ہیں۔