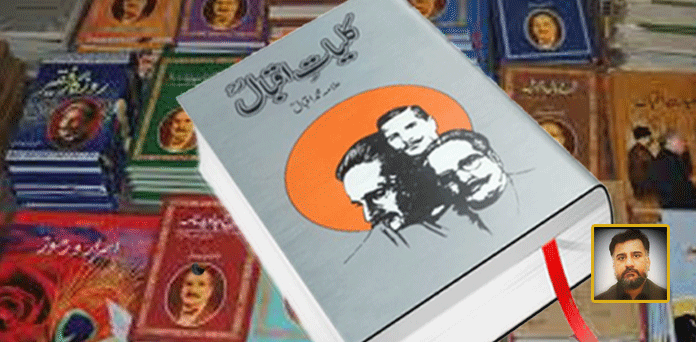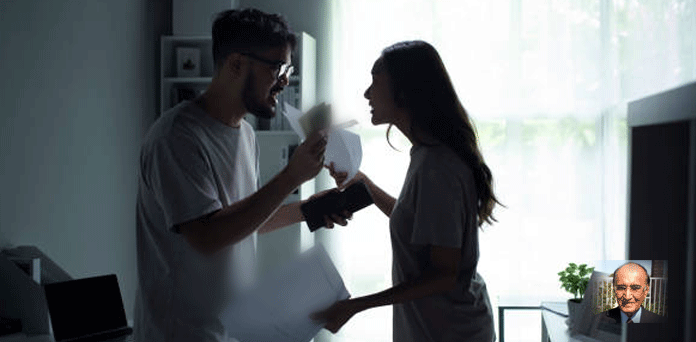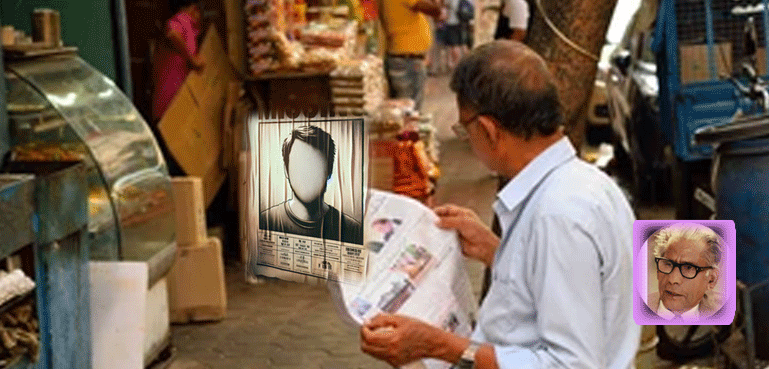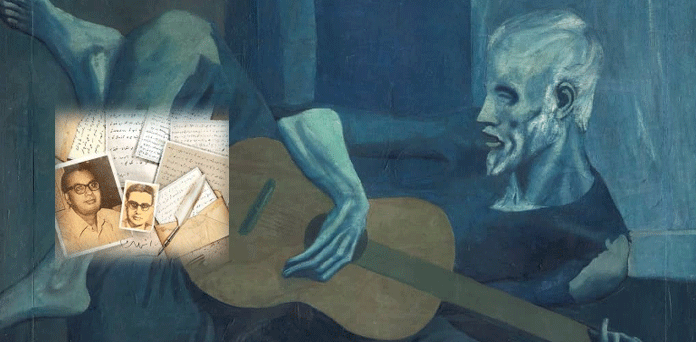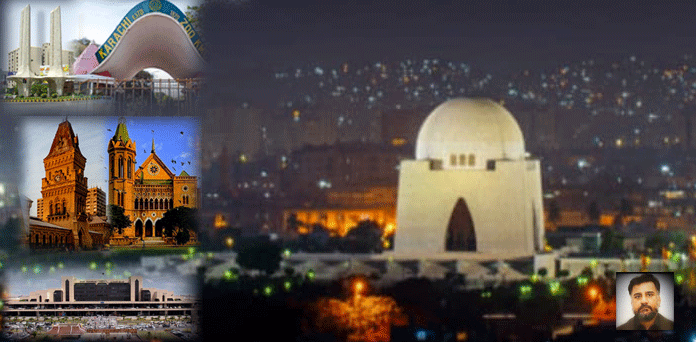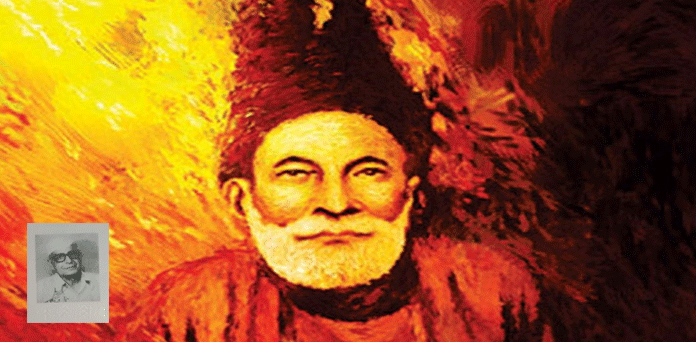آپ یقین مانیے کہ اگر مذہبی قیود، سماجی ذمہ داریاں اور ذاتی وقعت کا خیال لوگوں کے دلوں سے نکال دیا جائے تو آپ کو یہ جتنے شریف صورت انسان نظر آ رہے ہیں، ان کے کارناموں سے شیطان بھی پناہ مانگے اور یہ لوگ وہ حشر بپا کر دیں کہ دنیا دوزخ کا نمونہ بن جائے۔
یہ تو شاید آپ بھی مانتے ہوں گے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے اور یہ خطاب اس کو محض اس کی دماغی قوتوں کی وجہ سے ملا ہے۔ چونکہ شیطان اور اس کی ذریات یقیناً اشرف المخلوقات کے زمرے سے خارج ہیں، اس لئے ماننا پڑے گا کہ ان کے سروں میں دماغ نہیں ہے اور جب دماغ ہی نہیں ہے تو وہ کسی طرح بھی سوچ سوچ کر وہ بد معاشیاں نہیں کر سکتے جو انسان کر سکتا ہے اور جو جو باتیں دماغ سے اتار کر یہ کر جاتا ہے وہ فرشتہ تو کیا حضرت عزرائیل کے حاشیۂ خیال میں بھی نہیں آ سکتیں۔
اس کے بعد دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر واقعات کسی شخص کو نیک سے بد اور اچھے سے برا کر سکتے ہیں تو کیا واقعات کسی بدمعاش کو نیک معاش بھی بنا سکتے ہیں۔ اس بارے میں میری اور دنیا کی بعض قابل احترام ہستیوں کی رائے میں اختلاف ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ چیز ممکن ہے وہ کہتے ہیں کہ برائی کا مادّہ پختہ ہو کر کوئی بیرونی اثر قبول نہیں کر سکتا۔ یہ وہ بحث ہے جس کے سلسلے میں اپنی زندگی کے بعض حالت لکھ کر میں آپ کی رائے کا طالب ہوں۔ مگر خدا کے لیے رائے ظاہر کرتے وقت آپ صرف واقعات کو دیکھیے اور اس کا خیال نہ کیجیے کہ ایک طرف تو ایک ایسے شخص کی رائے ہے جس کی تمام عمر بدمعاشیاں کرتے گزری ہے اور دوسری طرف ان لوگوں رائے ہے جن کی عزت دنیا میں ہر شخص کے دل میں ہے اور جن کے قول آپ حدیث اور آیت کے ہم پلہ سمجھتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ بھی بتائیے کہ کیا طریقے ہو سکتے ہیں جو پختہ کار بدمعاشوں کو راہِ راست پر لا سکیں اور ان کی اصلاح حال کر سکیں۔
اس سے غرض نہیں کہ میں کہاں پیدا ہوا اور کب پیدا ہوا۔ اس سے مطلب نہیں کہ میں کس خاندان میں پیدا ہوا۔ میرا نام کیا رکھا گیا اور میں نے اس ایک نام کے رفتہ رفتہ کتنے نام کر لیے۔ ہمارے گرد و پیش کے واقعات سمجھنے کے لیے بس اتنا جاننا کافی ہے کہ ہم پیدا ہوئے اور ایسے والدین کے ہاں پیدا ہوئے کہ جناب والد صاحب قبلہ سخت شرابی اور بے فکرے تھے اور ہماری اماں بالکل اپاہج۔ گھر میں پہلے کچھ جمع پونجی ہو تو ہو لیکن جب سے ہوش سنبھالا، ہم نے تو یہاں خاک ہی اڑتے دیکھی۔ ہم کو اب تک یہ معلوم نہیں کہ آخر گھر کا خرچ چلتا تھا تو کیوں کر چلتا تھا۔ آٹھ نو برس تک ہماری عمر لونڈوں میں گیڑیاں اور گلی ڈنڈا کھیلنے، بدمعاشیاں کرنے اور شہر بھر کے گلی کوچوں کی خاک چھاننے میں گزری۔
کوئی ہم دس برس کے ہوں گے کہ والدہ صاحبہ نے گھر کا خرچ چلانے کا آلہ ہم کو بنایا۔ یعنی چوری کرنے کی ترغیب دی اور اس طرح ہم نے چوری کی۔ بسم اللہ سامنے کے گھر والے مولوی صاحب کے مرغے سے کی لیکن وہ مرغا بھی آخر مولوی صاحب کا مرغا تھا۔ ادھر ہم نے اس پر ہاتھ ڈالا اور ادھر اس نے غل مچا کر سارے محلّے کو جمع کر لیا۔ مولوی صاحب بھی باہر نکل آئے۔ مرغے کو ہماری بغل سے رہائی دلائی۔ ہمارے دو تین چپت رسید کیے۔ خوب ڈانٹا۔ ہماری اماں سے شکایت کی اور ڈرامے کا یہ سین ختم ہو گیا۔ ہماری عمر کا لحاظ کرتے ہوئے کسی کو یہ خیال بھی نہیں گزرا کہ ہم نے چوری کی نیّت سے یہ مرغا پکڑا تھا۔ یہ سمجھے کہ جس طرح بچّے جانوروں کو ستاتے ہیں، اسی طرح اس نے بھی کیا ہوگا۔ چلیے گئی گزری بات ہوئی۔
ہم روتے ہوئے اماں کے پاس آئے۔ انہوں نے ہم کو ایک ایسی ترکیب بتا دی کہ اب کہو تو سارے شہر کی مرغیاں پکڑ لاؤں اور کیا مجال ہے کہ ایک بھی ذرا چوں کر جائے۔ خیر وہ ترکیب بھی سن لیجیے۔ مگر للہ اس پر عمل نہ کیجیے، ورنہ یاد رکھیے کہ چوری کا جو مادّہ فطرت نے آپ کو ودیعت کیا ہے اس میں ہیجان پیدا ہو جائے گا اور ممکن ہے آپ بھی مرغے چور ہو جائیں۔
یہ تو آپ جانتے ہوں گے کہ مرغی پر اگر پانی کی ایک بوند بھی پڑ جائے تو وہ سکڑ کر وہیں بیٹھ جاتی ہے اور چاہے مار بھی ڈالو تو آواز نہیں نکالتی اور اسی سے ’’بھیگی مرغی‘‘ کا محاورہ نکلا ہے۔ فطرت کے مطالعے نے چوروں کو سکھا دیا ہے کہ مرغیوں کے چرانے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ ان کو کسی طرح گیلا کر دیا جائے۔ وہ کیا کرتے ہیں کہ جہاں کسی مرغی کو اپنے موقع پر دیکھا اور چپکے سے گیلا کپڑا اس پر ڈال دیا۔ ادھر گیلا کپڑا پڑا اور ادھر وہ دبکی۔ انہوں نے اٹھا کر بغل میں دبایا اور چلتے بنے۔ اب مرغی ہے کہ آنکھیں بند کیے سکڑی سکڑائی بغل میں دبی چلی جا رہی ہے۔ نہ کڑ کڑاتی ہے اور نہ منہ سے آواز نکالتی ہے۔ بہر حال یہ طریقہ سیکھ ہم نے سب سے پہلے مولوی صاحب کے مرغے پر ہی ہاتھ صاف کیا۔ اس روز بہت دنوں کے بعد ہمارے ہاں مرغ کا سالن پکا اور سب نے بڑے مزے سے اڑایا۔ مرغ کے بال و پر سب گڑھا کھود کر گھر ہی میں دفن کر دیے۔
بات یہ ہے کہ بچّے کو جو چیز سکھائی جاتی ہے وہ جلد سیکھ جاتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ اپنے ہاتھ کی چالاکی دکھا کر لوگوں کو بتائے کہ ہم کسی کارروائی میں بڑوں سے دب کر رہنے والے نہیں ہیں۔ چنانچہ ہم نے بھی مرغیاں پکڑنے کا تانتا باندھ دیا۔ شاید ہی کوئی منحوس دن ہوتا ہوگا جو ہم مرغیاں پکڑ کر نہ لاتے ہوں۔ کچھ دنوں تو یہ مرغیاں صرف ہمارے کھانے میں آتی رہیں۔ اس کے بعد ان کی تجارت شروع کی۔ یہاں کی مرغی پکڑی وہاں بیچ دی۔ وہاں کی مرغی لائے یہاں فروخت کر دی۔ غرض ہمارے بل پر گھر کا خرچ چلنے لگا۔ گھر کے خرچ سے جو کچھ بچتا وہ والد صاحب قبلہ مار پیٹ کر لے جاتے اور مفت کی شراب اڑاتے۔
اسی آوارہ گردی میں ہماری ملاقات ایسے لوگوں سے ہو گئی جو چوری میں مشاق تھے۔ ان میں بعضے ایسے تھے جو قید خانے کی ڈگریاں بھی حاصل کر چکے تھے۔ رفتہ رفتہ ان کی صحبت میں ہم کو مزہ آنے لگا۔ ہم اپنے کارنامے بیان کرتے وہ اپنے قصے سناتے۔ ہمارا شوق بڑھتا اور جی چاہتا کہ کچھ ایسا کام کرو جو یہ بھی کہیں کہ ’’واہ میاں صاحب زادے تم نے تو کمال کر دیا۔‘‘ غرض’’بدنام اگر ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا۔‘‘ کے خیال نے ہم کو مرغی چور سے پکا چور کر دیا۔ پہلے جیب کترنے کی مشق کی۔ گندہ بروزہ مل مل کر انگلیوں کی کگریں ایسی سخت کر لیں کہ مضبوط سے مضبوط اور موٹے سے موٹے کپڑے کو چٹکی میں لیا، ذرا مسلا اور جیب ہاتھ میں آ گئی۔ ہوتے ہوتے انگلیاں ایسا کام کرنے لگیں کہ قینچی بھی کیا کرے گی۔ جب اس میں کمال حاصل ہوگیا تو پھر قفل شکنی کی مشق بہم پہنچائی۔
قفل دو طرح سے کھولے جاتے ہیں۔ یا کنجیوں سے یا تار سے۔ اب یہ چور کا کمال ہے کہ قفل کو دیکھتے ہی اپنے لچھے میں سے کنجی ایسی نکالے جو قفل میں ٹھیک بیٹھ جائے، اور تار کو اس طرح موڑ کر ڈالے کہ پہلے ہی چکر میں سب پتلیاں ہٹ کر کھٹ سے قفل کھل جائے۔ کچھ خدا کی دین تھی کہ مجھے اس کام میں یدِ طولٰی حاصل ہو گیا۔ معمولی قفل تو درکنار، چپ کے کارخانے کا قفل بھی میں ایک منٹ میں کھول دیتا تھا اور یہی وجہ تھی کہ شہر کے بڑے بڑے چور بھی میری خوشامد کرتے۔ سب سے بڑا حصہ دیتے۔ اور ہاتھ جوڑ جوڑ کر مجھے ساتھ لے جاتے مگر میں سوائے قفل کھول دینے کے چوری سے کچھ غرض نہ رکھتا تھا۔ قفل کھولا اور چلا آیا۔ یار لوگوں نے چوری کا مال فروخت کیا اور میرا حصہ چپکے سے میرے پاس بھیج دیا۔ میرے ساتھی اکثر گرفتار ہوئے جیل گئے لیکن میرا نام کبھی عدالت کے سامنے نہیں آیا اورمیں باوجود سیکڑوں وارداتوں میں حصہ لینے کے بچا رہا۔
ہوتے ہوتے میرے ہاتھ کی صفائی نے وہ نام پیدا کیا کہ مجھے شہر بھر کے چوروں نے اپنا سردار بنا لیا۔ کوئی بڑی واردات نہ ہوتی تھی جس میں مجھ سے مشورہ نہ کیا جاتا ہو۔ کوئی بڑی چوری نہ ہوتی تھی جس کا میں نقشہ نہ ڈالتا ہوں اور کوئی مقدمہ نہ ہوتا تھا جس میں میری ذہانت سے مدد لے کر ملز مین رہا نہ ہوتے ہوں۔ بڑے بڑے گھاگ جیب کترے میرا لوہا مانتے تھے اور بڑے بڑے دیہاڑی چور میرے مشورے بغیر کسی کام میں ہاتھ نہ ڈالتے تھے۔
میری عمر کوئی اٹھارہ انیس سال کی ہو گی کہ اخبار ’’حفاظت‘‘ میں ایک اشتہار میری نظر سے گزرا۔ ہمارے ملک کے ایک بہت بڑے ادیب مسٹر مسعود نے لکھا تھا کہ ’’میں ایک ناول لکھنا اور چوری کے متعلق معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اگر اس فن کا کوئی ماہر میری مدد کرے تو میں اس کو مناسب معاوضہ دینے پر بھی تیار ہوں۔‘‘ آپ جانتے ہیں کہ ہر شخص اپنے کارناموں پر فخر کرتا اور ان کو مشتہر کرنا چاہتا ہے۔ یہ ایک انسانی کمزوری ہے اور اس سے کوئی فرد بشر خالی نہیں ہے۔ خیر انعام و اکرام کا تو مجھے فکر نہ تھا۔ ہاں میرے دل نے کہا کہ ذرا ان صاحب سے چل کر مل لو اور دیکھو کہ ہیں یہ کتنے پانی میں۔ چوروں کے قصے لکھ لکھ کر یہ اتنے مشہور ہو گئے ہیں لیکن یہ جانتے بھی ہیں کہ چور کیسے ہوتے ہیں اور چوری کس طرح کرتے ہیں۔
خطرہ ضرور تھا مگر میرے شوق نے مجھے اس قدر گھیرا کہ میں آخر شریفوں کی سی شکل بنا ان کے پاس پہنچ ہی گیا۔
کیا دیکھتا ہوں کہ ایک خوبصورت نوجوان سا شخص سامنے کھڑا مسکرا رہا ہے۔ آنکھوں میں ذہانت اور چہرہ پر متانت کے ساتھ شوخی اور لباس میں سادگی کے ساتھ صفائی ہے۔ آتے ہی ہاتھ بڑھایا اور کہا، ’’معاف کیجیے گا میں نے آپ کو نہیں پہچانا۔‘‘ میں نے کہا، ’’میں آپ ہی کی طلبی پر حاضر ہوا ہوں۔ آپ ہم لوگوں کے متعلق کچھ معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ممکن ہے کہ میں آپ کی اس خواہش کو پورا کر سکوں۔‘‘
کہنے لگے ’’اوہو۔ آپ میرے اشتہار کے جواب میں تشریف لائے ہیں۔ ذرا ٹھہریے۔ میں ابھی اپنی موٹر لاتا ہوں۔ ایسی باتیں کرنے کے لئے یہ جگہ مناسب نہیں ہے۔ کہیں سوفتے میں بیٹھ کر گفتگو کریں گے۔ مجھے آپ سے بہت کچھ پوچھنا ہے۔ ممکن ہے کہ ہماری یہ گفتگو دونوں کے لئے فائدہ بخش ہو۔‘‘
وہ تو یہ کہہ کر چلے گئے اور مجھے خیال ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ حضرت مجھے گرفتار کرا دیں۔ پھر سوچا کہ مجھ پر الزام ہی کیا ہے جو میں ڈروں۔ اور ان کو میرے حالات ہی کیا معلوم ہیں جو مجھے کچھ اندیشہ ہو۔ اگر گڑبڑ ہوئی بھی تو خود انہی کو شرمندہ ہونا پڑے گا۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ وہ موٹر لے آئے اور میں ’’ہر چہ باد باد ما کشتی در آب انداختیم‘‘ کہتا ہوا ان کے ساتھ سوار ہو گیا۔
موٹر فراٹے بھرتی شہر سے گزر آبادی کو پیچھے چھوڑ، جنگل میں سے ہوتی ہوئی ایک ندی پر پہنچی۔ مسٹر مسعود نے موٹر روکی۔ ہم دونوں اترے۔ چائے کا سامان نکالا گیا اور ندی کے کنارے دستر خوان بچھا کر ہم دونوں بیٹھے۔ اب کھاتے جاتے ہیں اور باتیں ہوتی جاتی ہیں۔
مسٹر مسعود نے کہا کہ ’’معاف کیجیے میں آپ کا نام نہیں جانتا اس لئے آپ کو گفتگو میں صرف ’’مسٹر‘‘ کہوں گا۔ کیونکہ میں جانتا ہوں کہ آپ کے حالات شاید اس کی اجازت نہ دیں کہ آپ اپنا نام کسی اجنبی شخص پر ظاہر کریں۔ اور اگر آپ نے ظاہر کیا بھی تو وہ یقیناً آپ کا اصلی نام نہ ہوگا۔ اس لئے بہتر یہی ہے کہ صرف لفط ’’مسٹر‘‘ سے ان تمام دقتوں کو رفع کیا جائے۔
اس سے تو آپ مطمئن ہو گئے ہوں گے کہ میں آپ کو ایسی جگہ لایا ہوں جہاں کوئی شخص چھپ چھپا کر ہماری باتیں نہیں سن سکتا۔ اور میں نے یہ صرف اس لیے کیا ہے کہ آپ کو یہ اندیشہ نہ ہو کہ میں آپ کے واقعات سننے میں کسی دوسرے کو شریک کر کے گواہ بنانا چاہتا ہوں۔ اب ہم نہایت اطمینان سے گفتگو کر سکتے ہیں۔ آپ کا جو جی چاہے مجھ سے پوچھیے اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں ہر چیز صاف دلی سے بیان کروں گا اور مجھے امید ہے کہ آپ بھی میرے سوالوں کے جواب میں سچائی کا پہلو اختیار کریں گے اور اس طرح ممکن ہے کہ یہ صحبت ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کا دوست اور پکا دوست بنا دے۔
مسٹر مسعود کی آواز میں کچھ ایسا لوچ، الفاظ میں کچھ ایسی شیرینی، نگاہ میں کچھ ایسی محبت اور گفتگو میں کچھ ایسی دل چسپی تھی کہ تھوڑی ہی دیر میں وہ تمام اندیشے ہوا ہو گئے جو مجھ جیسے شخص کے دل میں پیدا ہوئے تھے۔ اور پیدا ہونے لازمی تھے اور یہ پہلا موقع تھا کہ میرے دل میں کسی شخص کی وقعت قائم ہوئی۔ اور خود اپنے متعلق بھی سمجھا کہ میں بھی آدمی ہوں اور ایک شریف آدمی بن سکتا ہوں۔ باتوں باتوں میں یہ بھی معلوم ہوا کہ مسٹر مسعود کو ابتدا ہی سے مجھ جیسے لوگوں سے ملنے کا شوق ہے اور وہ کوئی کتاب نہیں لکھتے جب تک اس کی بنا واقعات پر نہ ہو۔ ان کو بہت سے بدمعاشوں نے دھوکے بھی دیے اور دوستی کی آڑ میں ان کو خوب لوٹا۔ یہاں تک کہ کئی دفعہ تو خود ان کے گھر میں چوری کی اور مزہ یہ ہے کہ خود اس چوری کا حال ان سے بیان بھی کر دیا مگر اس اللہ کے بندے نے نہ کبھی کسی کے خلاف کوئی کارروائی کی اور نہ کبھی کوئی شکوہ و شکایت زبان پر لایا۔
مجھے یہ معلوم کر کے بڑی حیرت ہوئی کہ وہ اور تو اور، خود میرے حالات سے پوری طرح واقف ہیں۔ انہوں نے اپنا جال کچھ اس طرح پھیلایا تھا کہ کوئی واردات نہ ہوتی ہوگی جس کا رتی رتی حال ان کو نہ معلوم ہو جاتا ہو۔ اور کوئی مشہور چور یا ڈاکو ایسا نہ تھا جس کو وہ ذاتی طور پر نہ جانتے ہوں، اور ضرورت کے وقت اس کی مدد نہ کرتے ہوں۔ وہ اس بات کے قائل تھے کہ ضرورت اکثر لوگوں کو چوری کا پیشہ اختیار کرنے پر مجبور کرتی ہے لیکن رفتہ رفتہ گرد و پیش کے واقعات جال بن کر ان کو اس طرح پھنسا لیتے ہیں کہ وہ جتنا نکلنا چاہتے ہیں اتنی ہی جال کی رسیاں ان کو کستی چلی جاتی ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یا تو وہ کسی جیل خانے میں مر کر رہ جاتے ہیں یا ضمیر کی ملامت کسی مرض میں مبتلا کر کےان کا خاتمہ کر دیتی ہے۔
مسٹر مسعود جیسے شخص کے ساتھ دل کھول کر گفتگو نہ کرنا واقعی ظلم تھا۔ میں نے بھی اپنے اگلے پچھلے واقعات سب بیان کر دیے۔ چوری کرنے کی ترکیبیں بتائیں۔ قفل کھولنے کے طریقے بتائے۔ اپنے ساتھیوں کے قصے بیان کیے۔ غرض کوئی تین چار گھنٹے اسی قسم کی گفتگو میں گزر گئے۔ شام ہو گئی تھی اس لیے ہم دونوں اٹھے۔ شہر کے کنارے پر انہوں نے مجھے موٹر سے اتار دیا۔ دوسرے دن ملنے کا وعدہ لیا اور اس طرح ہم دونوں کی گفتگو کا سلسلہ کوئی مہینہ بھر چلتا رہا۔ انہوں نے مجھے معقول معاضہ دینا بھی چاہا لیکن میں نے لینے سے انکار کر دیا۔ ایک دن مجھ سے کہنے لگے، ’’مسٹر اب معلوم نہیں آئندہ ہمارا ملنا ہو یا نہ ہو لیکن میں سچ کہتا ہوں کہ آپ کی صحبت میں جو مزہ مجھے آیا ہے، وہ شاید ہی کسی کی صحبت میں آیا ہو۔ میرا ارادہ ہے کل یہاں سے چلا جاؤں گا۔ اس لئے یہ سمجھنا چاہیے کہ آج میری اور آپ کی آخری ملاقات ہے۔
ایک دن میں نے اخبار میں پڑھا کہ قفلوں کے ایک بڑے کارخانے میں ایک کاریگر کی ضرورت ہے۔ اسّی روپے تنخواہ ملے گی مگر انہی لوگوں کو درخواست دینی چاہیے جو قفلوں کی پتلیوں کو سمجھتے ہوں اور ان میں ایجاد کرنے کا مشورہ دے سکتے ہوں۔ مجھ کو آتا ہی کیا تھا، اگر کچھ آتا تھا تو انہی پتلیوں کا الٹ پھیر۔ دل میں آیا کہ چلو یہاں قسمت آزمائی کریں۔ جیب جو ٹٹولی تو کرایہ تک پاس نہ تھا۔ اللہ کا نام لے کر پیدل چل کھڑا ہوا۔
سو میل کا فاصلہ چار دن میں طے کیا۔ کارخانے میں پہنچا۔ میری زدہ حالت دیکھ کر کسی نے منہ نہ لگایا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ وہ جگہ بھر چکی ہے۔ کارخانے کی سیڑھیوں پر سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر نہ ہوئی تھی کہ خدا کی قدرت سے کارخانے کے مالک وہاں سے گزرے۔ مجھے سر پکڑے بیٹھا دیکھ کر وہیں ٹھہر گئے۔ مجھ سے پوچھا کہ ’’آپ کون ہیں اور یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟‘‘
میں نے اپنے پیدل آنے کا قصہ بیان کیا۔ ان پر اس کا کچھ ایسا اثر ہوا کہ مجھے لے کر کارخانے میں گئے۔ ایک بڑی تجوری رکھی تھی۔ کہنے لگے، ’’ذرا بتاؤ تو سہی کہ اس میں کتنی پتلیاں ہیں۔ ہمارے کار خانے کا دعویٰ ہے کہ اسے کوئی نہیں کھول سکتا۔‘‘ میں نے ان سے ایک موٹا تار مانگا۔ قفل کے سوراخ میں ڈال کر گھمایا اور کہا کہ’’اس میں گیارہ پتلیاں ہیں اور اس کے کھولنے کے لیے دو کنجیاں چاہییں۔ لیکن اگر آپ کہیں تو اسی تار سے میں اس کو کھول دوں۔‘‘
میں نے تار کو ذرا موڑ کر دو چکر دیے۔ قفل کھٹ سے کھل گیا۔ یہ دیکھ کر تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ کہنے لگے، ’’کیا تم بتا سکتے ہو کہ اس میں اور کیا ترمیم کی ضرورت ہے جو قفل بغیر کسی کنجی کے نہ کھل سکے۔‘‘ میں نے اپنے تجربے کے لحاظ سے ان کو پتلیوں کی ترتیب بتائی۔ یہ سن کر تو وہ ایسے خوش ہوئے کہ وہیں کھڑے کھڑے اسّی روپے پر مجھے نوکر رکھ لیا۔ اس کے بعد میں نے اتنی محنت سے کام کیا اور قفلوں میں وہ ایجادیں کیں کہ تھوڑے ہی دنوں میں وہ کارخانہ کہیں سے کہیں پہنچ گیا۔ میری تنخواہ بڑھ کر تین سو روپے ہو گئی۔ دوسرے کارخانے والوں نے مجھے توڑنا بھی چاہا لیکن میں نے صاف انکار کر دیا۔ بھلا یہ کیسے ممکن تھا کہ جس شخص نے مصیبت میں میری مدد کی تھی اس کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ غرض یہ کہ تمام ملک میں ہمارے کارخانے کی دھاک بیٹھ گئی۔ جب اس طرح اطمینان ہو گیا، تو میں نے گھر بسانے کا ارادہ کیا۔ شادی بھی ٹھہر گئی لیکن عین وقت پر از غیبی گولہ پڑا۔
ہوا یہ کہ ہمارے شہر میں’’چور اور چوری‘‘ پر ایک لیکچر کا اشتہار دیا گیا۔ میں نے سوچا کہ چلو دیکھیں کہ یہ لیکچرار صاحب اس پیشے کے متعلق کیا جانتے ہیں اور کیا کہتے ہیں۔ وقت مقررہ پر جو میں جلسہ میں پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ہزاروں آدمیوں کا مجمع ہے۔ سیکڑوں اخباروں کے نمائندے فوٹو کے کیمرے لیے موجود ہیں۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ آخر ان بھلے آدمیوں کو چوروں سے کچھ ایسی دلچسپی ہے جو اپنا سارا کاروبار چھوڑ کر یہاں جمع ہوئے ہیں۔ بہرحال چار بجے کے قریب مقرر صاحب تشریف لائے۔ ان کے خیر مقدم میں تالیوں کا وہ شور اور ہرے ہرے کا وہ غل ہوا کہ زمین آسمان ہل گئے۔ وہ بھی نہایت شان سے چبوترہ پر آئے۔ اب جو دیکھتا ہوں تو یہ تو میرے پرانے دوست مسٹر مسعود ہیں۔ میں نے کہا، ’’لو بھئی اچھا ہوا، اب ان کو بتاؤں گا کہ حضرت مجھے دیکھ کر آپ اندازہ کیجیے کہ میں صحیح کہتا تھا یا آپ صحیح کہتے تھے۔ میں پہلے کیا تھا اور اب کیا ہوں۔ آخر میری اصلاح حال ہوئی یا نہیں۔‘‘
خیر لیکچر شروع ہوا۔ مسٹر مسعود نے چوروں کی ٹولیوں کے، ان کے رہنے سہنے کے، ان کے چوری کرنے کے، ان کے خیالات کے غرض ان کی زندگی کے ہر پہلو کا نقشہ اس خوبی سے کھینچا کہ دل خوش ہو گیا۔ اور اس وقت معلوم ہواکہ واقعی مطالعۂ زندگی اس طرح کیا جاتا ہے اور تجربات کو اس طرح بیان کرتے ہیں۔ اپنے لیکچر کے آخر میں انہوں نے وہی پرانی بحث چھیڑی کہ ’’جس شخص کو چوری کا مرض پڑ گیا ہو کیا اس کی اصلاح حال کی جا سکتی ہے؟‘‘ اور اپنی وہی پرانی رائے ظاہر کی کہ ’’یہ مرض پختہ ہو کر عادت ثانی ہو جاتا ہے۔ اور عادت ثانی کا چھڑانا ناممکن ہے۔‘‘ لیکچر ختم ہونے کے بعد مجھ سے نہ رہا گیا اور میں سیدھا لیکچرار صاحب کے چبوترے پر پہنچا۔ انہوں نے مجھ کو ذرا غور سے دیکھا لیکن یہ نہ سمجھ سکے کہ یہ کون شخص ہے۔
مجھ کو لیکچر وکچر دینا تو آتا نہیں۔ ہاں میں نے سیدھی سیدھی زبان میں کہا، ’’معزز حاضرین! ہمارے کرم فرما مسٹر مسعود نے آخر میں جو کچھ کہا ہے وہ بالکل غلط ہے۔ ممکن ہے کہ ان کی دریافت میں کوئی ایسا چور نہ ملا ہو جو راہ راست پر آیا ہو۔ لیکن میرا تجربہ اس کے بالکل خلاف ہے۔ میں عرض کرتا ہوں کہ بد سے بد تر شخص کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ خواہ اس کو مسٹر مسعود مانیں یا نہ مانیں۔‘‘ میں یہیں تک کہنے پایا تھا کہ جلسہ میں غل مچ گیا۔ کوئی کہتا، ’’حضرت آپ کے دماغ کا علاج کرائیے۔‘‘ کوئی کہتا، ’’آپ کی فصد لیجیے۔‘‘ غرض کیسا سننا اور کیسا سمجھنا۔ ایک طوفان بے تمیزی برپا ہو گیا۔ مسٹر مسعود تو سوار ہو کر چل دیے اور مجھے اخبار کے نمائندوں نے گھیر لیا۔ بیسیوں فوٹو لیے گئے۔ہزاروں سوالات کیے گئے۔
میں نے پوچھا، ’’بھائیو یہ کیا معاملہ ہے۔ آخر میں نے ایسی کون سی عجیب بات کہی ہے جو مجھے یوں دیوانہ بنا لیا ہے۔‘‘ آخر بڑی مشکل سے ایک صاحب نے کہا، ’’حضرت معلوم بھی ہے کہ آپ نے کس شخص کی تردید کی ہے۔ مسٹر مسعود وہ شخص ہیں کہ جرائم پیشہ لوگوں کی واقفیت کے متعلق تمام دنیا ان کا لوہا مانتی ہے۔ آپ کے سوا اس شہر میں تو کیا ساری دنیا میں کوئی نہ ہوگا کہ مسٹر مسعود ان لوگوں کے بارے میں کچھ فرمائیں اور وہ آمنّا اور صدقنا نہ کہے۔ خیر اور کچھ نہیں تو یہ ضرور ہوگا کہ ساری دنیا میں شہرت ہو جائے گی کہ آج بھرے جلسے میں ایک صاحب نے مسٹر مسعود پراعتراض ٹھونک دیا۔‘‘ میں پریشان تھا کہ یا میرے اللہ یہ عجیب بات ہے کہ یہ دنیا والے جب کسی کو اچھا سمجھنے لگتے ہیں تو پھر اس کے خلا ف کچھ سننا ہی نہیں چاہتے اور اس کی صحیح اور غلط ہر بات پر سر تسلیم جھکا دیتے ہیں۔
چار روز بھی نہیں گزرتے تھے کہ ملک کے سارے اخباروں میں اس جلسے کی کیفیت اور میری تقریر چھپ گئی۔ ہر اخبارمیں میری تصویر تھی اور اس کے نیچے لکھا تھا کہ ’’آپ فلاں شہر میں لوہار ہیں۔ اور چوروں کے اصلاح حال کے بارے میں مسٹر مسعود کی رائے سے اختلاف رکھتے ہیں۔‘‘ غرض کوئی پرچہ نہ تھا جس میں مجھے خوب نہ بنایا گیا ہو، اور میرا مذاق نہ اڑایا گیا ہو۔ جو پرچہ چھپتا اس کی ایک کاپی میرے پاس بھی آتی۔ میں دیکھتا اور ہنس کر خاموش ہو جاتا۔ لوگوں کی اس بے ہودگی کی تو مجھے پروا نہ تھی لیکن غضب یہ ہوا کہ یہ اخبار میرے قدیم ہم پیشہ لوگوں کے ہاتھوں میں بھی پڑے۔ وہ پہلے سے میری تلاش میں تھے، اور پیشہ چھوڑنے کی وجہ سے مجھ سے بدلہ لینا چاہتے تھے۔ انہوں نے یہ کیا کہ میرے سابقہ حالات اخباروں میں چھپوا دیے۔ اور دنیا کو بتا دیا کہ جن صاحب نے مسٹر مسعود کی مخالفت کی ہے وہ خود بڑے دیہاڑی چور ہیں۔ اور اس لیے ان کی رائے کسی طرح بھی مسٹر مسعود کی رائے سے کم وقعت نہیں رکھتی۔
ان حالات کا چھپنا تھا کہ سارے ملک میں اودھم مچ گیا ور جو عزت میں نے اپنی محنت، کار گزاری اور دیانت سے حاصل کی تھی وہ سب خاک میں مل گئی۔
(اردو کے مقبول مزاح نگار مرزا فرحت اللہ بیگ کی ایک شگفتہ تحریر سے اقتباسات)