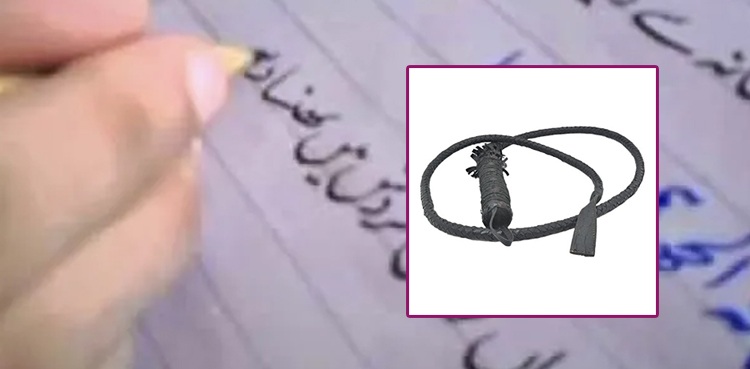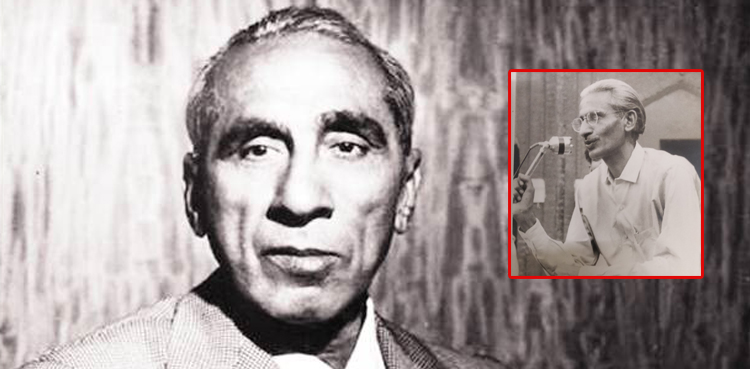رضیہ ہماری توقع سے بھی زیادہ حسین نکلی اور حسین ہی نہیں کیا فتنہ گرِ قد و گیسو تھی۔ پہلی نگاہ پر ہی محسوس ہوا کہ initiative ہمارے ہاتھ سے نکل کر فریقِ مخالف کے پاس چلا گیا ہے۔
یہی وجہ تھی کہ پہلا سوال بھی ادھر سے ہی آیا: "تو آپ ہیں ہمارے نئے نویلے ٹیوٹر؟” اب اس شوخ سوال کا جواب تو یہ تھا کہ "تو آپ ہیں ہماری نئی نویلی شاگرد؟” لیکن سچّی بات یہ ہے کہ حسن کی سرکار میں ہماری شوخی ایک لمحے کے لیے ماند پڑ گئی اور ہمارے منہ سے ایک بے جان سا جواب نکلا:
” جی ہاں، نیا تو ہوں، ٹیوٹر نہیں ہوں۔ مولوی صاحب کی جگہ آیا ہوں۔”
"اس سے آپ کی ٹیوٹری میں کیا فرق پڑتا ہے؟”
"یہی کہ عارضی ہوں۔”
"تو عارضی ٹیوٹر صاحب۔ ہمیں ذرا اس مصیبت سے نجات دلا دیں۔” رضیہ کا اشارہ دیوانِ غالب کی طرف تھا۔ میں نے قدرے متعجب ہو کر پوچھا: "آپ دیوانِ غالب کو مصیبت کہتی ہیں؟”
"جی ہاں! اور خود غالب کو بھی۔”
"میں پوچھ سکتا ہوں کہ غالب پر یہ عتاب کیوں؟”
"آپ ذرا آسان اردو بولیے۔ عتاب کسے کہتے ہیں؟”
"عتاب غصّے کو کہتے ہیں۔”
"غصّہ؟ ہاں غصّہ اس لیے کہ غالب صاحب کا لکھا تو شاید وہ خود بھی نہیں سمجھ سکتے۔ پھر خدا جانے پورا دیوان کیوں لکھ مارا؟”
"اس لیے کہ لوگ پڑھ کر لذّت اور سرور حاصل کریں۔”
"نہیں جناب۔ اس لیے کہ ہر سال سیکڑوں لڑکیاں اردو میں فیل ہوں۔”
"محترمہ۔ میری دل چسپی فقط ایک لڑکی میں ہے، فرمائیے آپ کا سبق کس غزل پر ہے؟” جواب میں رضیہ نے ایک غزل کے پہلے مصرع پر انگلی رکھ دی، لیکن منہ سے کچھ نہ بولی۔ میں نے دیکھا تو غالب کی مشہور غزل تھی۔
یہ نہ تھی ہماری قسمت کہ وصالِ یار ہوتا
میں نے کہا، "یہ تو بڑی لاجواب غزل ہے، ذرا پڑھیے تو۔”
"میرا خیال ہے آپ ہی پڑھیں۔ میرے پڑھنے سے اس کی لاجوابی پر کوئی ناگوار اثر نہ پڑے۔” مجھے محسوس ہوا کہ ولایت کی پڑھی ہوئی رضیہ صاحبہ باتونی بھی ہیں اور ذہین بھی لیکن اردو پڑھنے میں غالباً اناڑی ہی ہیں۔
میں نے کہا، "میرے پڑھنے سے آپ کا بھلا نہ ہوگا۔ آپ ہی پڑھیں کہ تلفظ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔”
رضیہ نے پڑھنا شروع کیا اور سچ مچ جیسے پہلی جماعت کا بچّہ پڑھتا ہے۔
” یہ نہ تھی ہماری قس مت کہ وصل۔۔۔۔” میں نے ٹوک کر کہا۔
"یہ وصل نہیں وصال ہے، وصل تو سیٹی کو کہتے ہیں۔”
رضیہ نے ہمیں سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ ہم ذرا مسکرائے اور ہمارا اعتماد بحال ہونے لگا۔
رضیہ بولی: "اچھا۔ وصال سہی۔ وصال کے معنی کیا ہوتے ہیں؟”
"وصال کے معنی ہوتے ہیں ملاقات، محبوب سے ملاقات۔ آپ پھر مصرع پڑھیں۔” رضیہ نے دوبارہ مصرع پڑھا۔ پہلے سے ذرا بہتر تھا لیکن وصال اور یار کو اضافت کے بغیر الگ الگ پڑھا۔ اس پر ہم نے ٹوکا۔
"وصال یار نہیں وصالِ یار ہے۔ درمیان میں اضافت ہے۔”
"اضافت کیا ہوتی ہے؟ کہاں ہوتی ہے؟”
"یہ جو چھوٹی سی زیر نظر آرہی ہے نا آپ کو، اسی کو اضافت کہتے ہیں۔”
"تو سیدھا سادہ وصالے یار کیوں نہیں لکھ دیتے؟”
"اس لیے کہ وہ علما کے نزدیک غلط ہے۔” یہ ہم نے کسی قدر رعب سے کہا۔
علما کا وصال سے کیا تعلق ہے؟”
"علما کا تعلق وصال سے نہیں زیر سے ہے۔”
"اچھا جانے دیں علما کو۔ مطلب کیا ہوا؟”
"شاعر کہتا ہے کہ یہ میری قسمت ہی میں نہ تھا کہ یار سے وصال ہوتا۔”
"قسمت کو تو غالب صاحب درمیان میں یونہی گھسیٹ لائے، مطلب یہ کہ بے چارے کو وصال نصیب نہ ہوا۔”
"جی ہاں کچھ ایسی ہی بات تھی۔”
"کیا وجہ؟”
"میں کیا کہہ سکتا ہوں؟”
"کیوں نہیں کہہ سکتے۔ آپ ٹیوٹر جو ہیں۔”
"شاعر خود خاموش ہے۔”
"تو شاعر نے وجہ نہیں بتائی مگر یہ خوش خبری سنادی کہ وصال میں فیل ہوگئے؟”
” جی ہاں فی الحال تو یہی ہے۔ آگے پڑھیں۔” رضیہ نے اگلا مصرع پڑھا۔ ذرا اٹک اٹک کر مگر ٹھیک پڑھا:
اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا
میں نے رضیہ کی دل جوئی کے لیے ذرا سرپرستانہ انداز میں کہا، "شاباش، آپ نے بہت اچھا پڑھا ہے۔”
"اس شاباش کو تو میں ذرا بعد میں فریم کراؤں گی۔ اس وقت ذرا شعر کے پورے معنیٰ بتا دیں۔” ہم نے رضیہ کا طنز برداشت کرتے ہوئے کہا۔
"مطلب صاف ہے، غالب کہتا ہے قسمت میں محبوبہ سے وصال لکھا ہی نہ تھا۔ چنانچہ اب موت قریب ہے مگر جیتا بھی رہتا تو وصال کے انتظار میں عمر کٹ جاتی۔”
” توبہ اللہ، اتنا Lack of confidence، یہ غالب اتنے ہی گئے گزرے تھےِ؟”
گئے گزرے؟ نہیں تو۔۔۔غالب ایک عظیم شاعر تھے۔”
"شاعر تو جیسے تھے، سو تھے لیکن محبت کے معاملے میں گھسیارے ہی نکلے”
(ممتاز مزاح نگار کرنل محمد خان کے قلم سے)