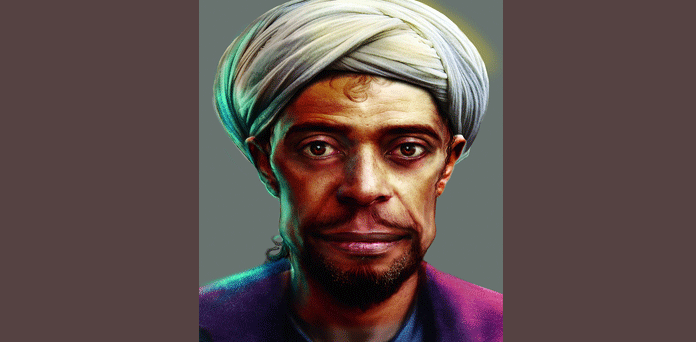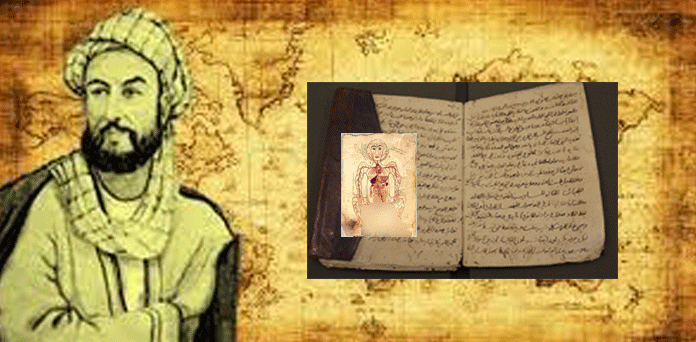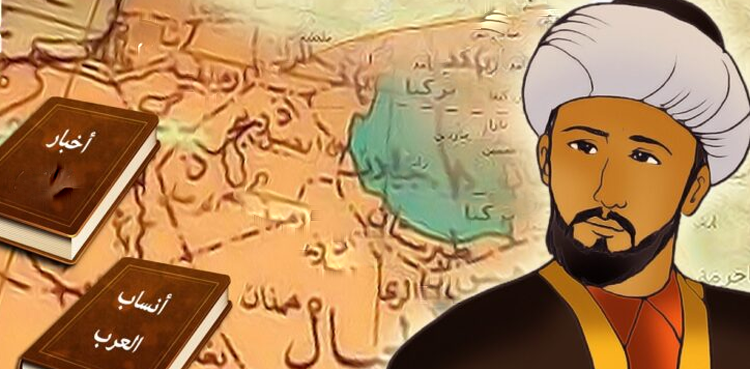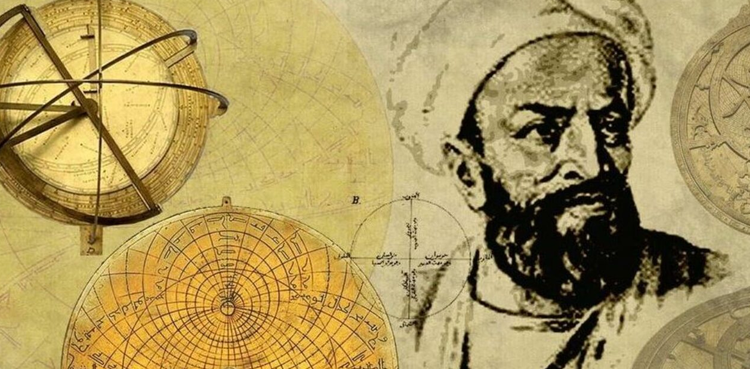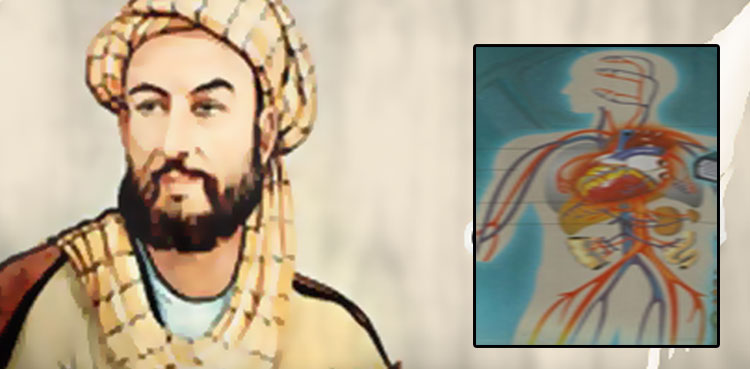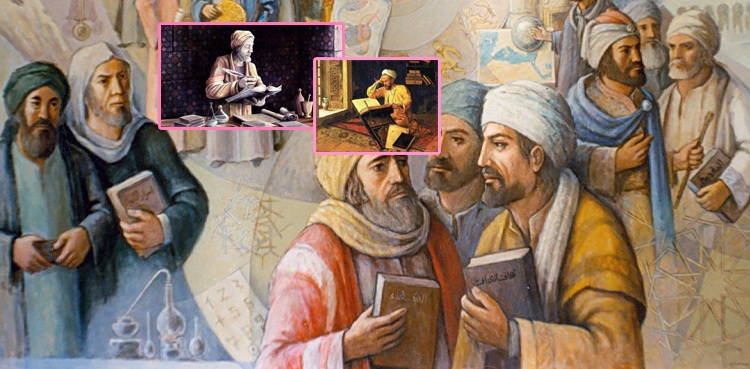یہ عرب دنیا کے ایک فلسفی، مصنّف، محقق اور ماہرِ حیاتیات جاحظ کا تذکرہ ہے۔ محققین لکھتے ہیں کہ جاحظ ہی وہ مسلمان مفکر تھے جنھوں نے ڈارون سے ہزار برس قبل نظریۂ ارتقا پیش کیا۔ مطالعہ کا شوق اور علمی و تحقیقی کاموں کی لگن رکھنے والے جاحظ کی ناگہانی موت بھی کتابیں ہی بنی تھیں۔
جاحظ کا پورا نام ابو عثمان عمرو بحرالکنانی البصری تھا۔ محققین کے مطابق وہ 776 عیسوی میں بصرہ میں پیدا ہوئے۔ غریب خاندان کے جاحظ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بدہیئت تھے۔ ان کے دیدے بڑے اور آنکھیں باہر کی جانب گویا ابلی ہوئی تھیں۔ بچّے اور اکثر بڑے بھی ان کو دیکھ کر مذاق اڑاتے تھے۔ اسی نسبت سے وہ جاحظ مشہور ہوئے جس کا عربی میں ایک معنی عجیب الخلقت ہے یا ایسا شخص جس کی آنکھیں باہر کو ابلی ہوئی معلوم ہوں۔ جاحظ کو بچپن میں دریا سے مچھلیاں پکڑ کر بیچنے کا کام کرنا پڑا اور انھوں نے گزر بسر میں مشکلات کا سامنا کیا۔
جاحظ نے اپنی شکل و صورت اور غربت کو اپنے علمی ذوق و شوق کے سامنے ڈھیر ہونے پر مجبور کر دیا۔ چارلس ڈارون نے اپنے مشاہدات اور گہرے غور و فکر کے بعد نظریۂ ارتقا کو ٹھوس عقلی اور استدلالی بنیاد فراہم کی تھی جس پر آج تک تحقیق کا سلسلہ جاری ہے اور اس نظریۂ ارتقا کو بنیاد بنا کر سائنس داں زندگی کے بارے میں بہت کچھ جان رہے ہیں۔ لیکن جاحظ کئی صدیوں پہلے یہ تصور پیش کر چکے تھے۔
جاحظ نے اس دور کے رواج کے مطابق تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ فارغ اوقات میں مختلف علمی اور ادبی مجالس میں شرکت کرتے اور وہاں علماء اور اپنے وقت کی فاضل شخصیات کی تقاریر اور مباحثے سنا کرتے تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا، جب عباسی عہد میں معتزلہ فرقہ جڑ پکڑ رہا تھا اور ہر طرف مذہب ہر مباحث، فلسفہ اور سائنس کے موضوعات پر دھواں دھار تقریریں ہوا کرتی تھیں۔ جاحظ نے اسی دور میں اپنے اندر علمی ذوق و شوق کو پنپتا ہوا پایا اور وہ کتب خانوں میں وقت گزارنے لگے جس سے انھیں اپنے نظریات کو وضع کرنے میں مدد ملی۔ عباسی سلطنت کے اس عروج کے دور میں خلیفہ ہارون الرشید اور مامون الرشید کے بنوائے ہوئے کتب خانوں، اور علم و فنون کے لیے سازگار ماحول میں جاحظ نے بھی خود کو منوایا۔ نوجوان جاحظ نے مختلف و متنوع موضوعات پر ایک کے بعد ایک تصنیف پیش کی اور جلد ہی ان کی شہرت دور تک پھیل گئی۔ یہاں تک کہ عباسی خلیفہ مامون الرشید بھی ان کے قدردانوں میں شامل ہو گئے۔ بعد میں خلیفہ المتوکل نے انھیں اپنے بچوں کا استاد مقرر کیا۔
جاحظ نے سائنس، جغرافیہ، فلسفہ، صرف و نحو اور علم البیان جیسے کئی موضوعات پر قلم اٹھایا۔ ان کی کتابوں کی تعداد دو سو کے قریب بتائی گئی ہے، تاہم یہ سبھی تصانیف محفوظ نہیں رہ سکیں۔ ہم تک ان کی چند ہی کتابیں پہنچی ہیں اور ان میں ایک ‘کتاب البخلاء’ (بخیلوں کی کتاب) بھی ہے جو نویں صدی کے عرب معاشرے کا زندہ مرقع ہے جس میں انھوں نے متعدد لوگوں کی جیتی جاگتی تصویریں پیش کی ہیں۔
اگر جاحظ کی سب سے مشہور تصنیف کی بات کی جائے تو یہ زمین پر ارتقا کے سلسلے میں ‘کتاب الحیوان’ ہے۔ یہ ایک قسم کا انسائیکلوپیڈیا ہے جس میں جاحظ نے ساڑھے تین سو جانوروں کا احوال بیان کیا ہے۔ اسی کتاب میں جاحظ نے چند ایسے تصورات پیش کیے جو حیرت انگیز طور پر ڈارون کے نظریۂ ارتقا سے مشابہ ہیں۔
شاعر مشرق علامہ اقبال نے بھی جاحظ کا ذکر کیا ہے۔ اپنے خطبات کے مجموعے ‘ری کنسٹرکشن آف ریلیجیئس تھاٹ ان اسلام’ (اسلامی مذہبی فکر کی تشکیلِ نو) میں وہ لکھتے ہیں کہ ‘یہ جاحظ تھا جس نے نقلِ مکانی اور ماحول کی وجہ سے جانوروں کی زندگی میں آنے والی تبدیلیوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔’
اس مسلمان مفکر کی موت کا سبب بھی یہی علمی شغف بنا۔ کہا جاتا ہے کہ سن رسیدہ جاحظ ایک روز کتابوں کی الماری سے کسی موضوع پر کوئی کتاب نکال رہے تھے کہ بھاری بھرکم الماری ان پر آ پڑی۔ بوڑھے جاحظ اس الماری کے نیچے دب کر ہلاک ہوگئے تھے۔