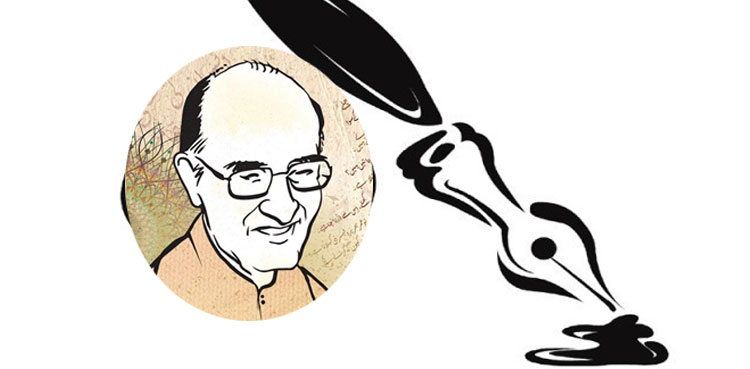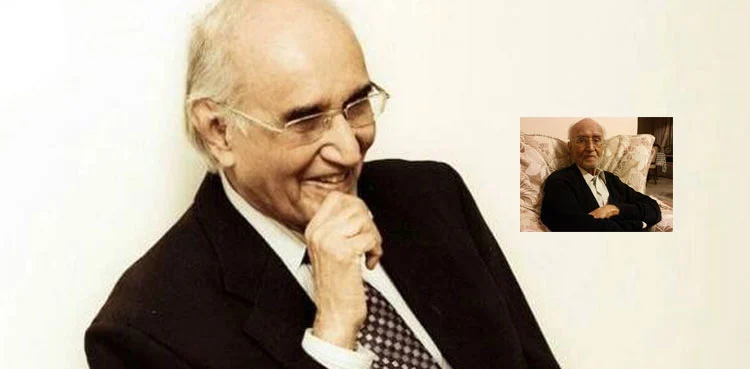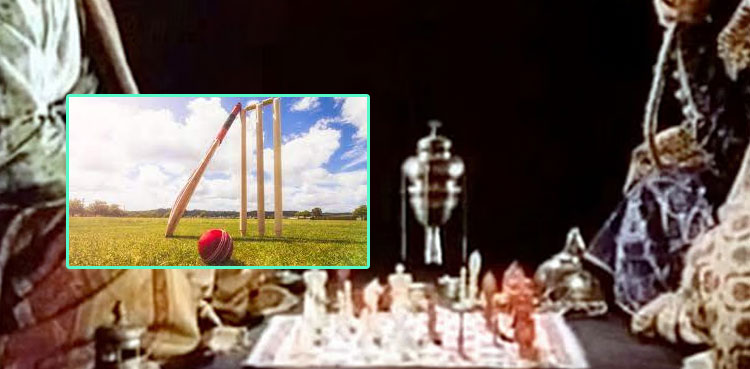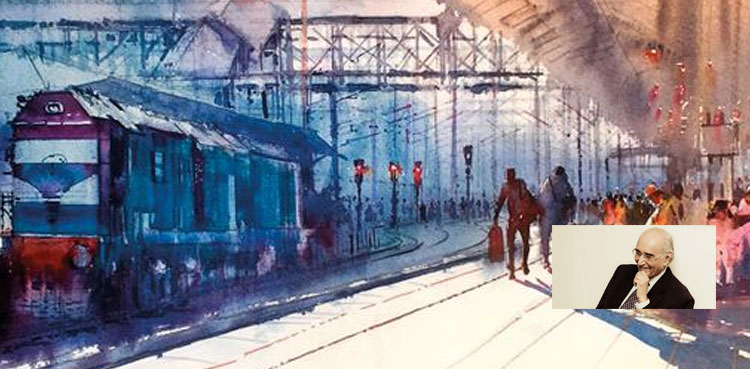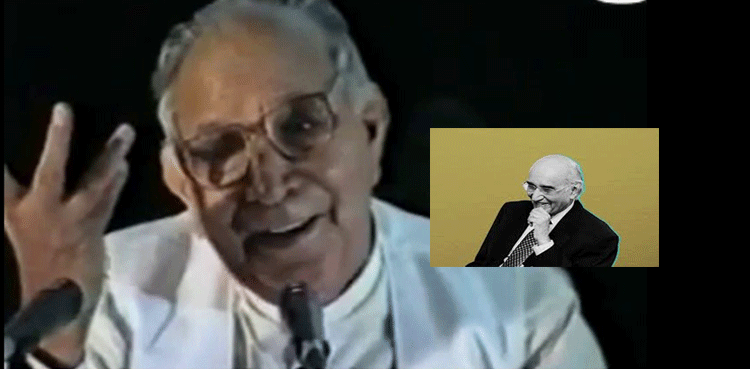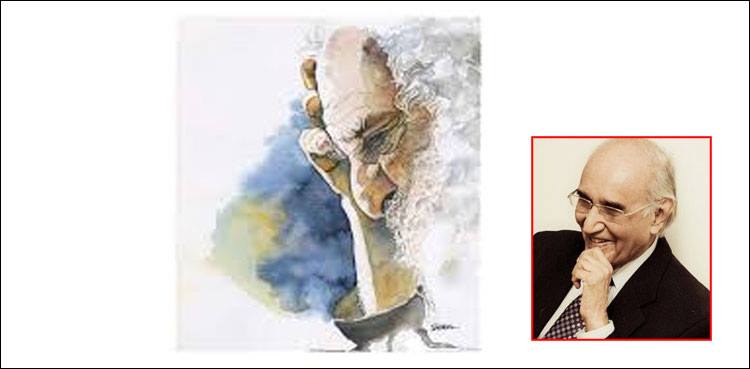انسان کو حیوانِ ظریف کہا گیا ہے۔ لیکن یہ حیوانوں کے ساتھ بڑی زیادتی ہے۔
اس لیے کہ دیکھا جائے تو انسان صرف واحد حیوان ہے جو مصیبت پڑنے سے پہلے مایوس ہوجاتا ہے۔ انسان واحد جاندار ہے، جسے خلّاقِ عالم نے اپنے حال پر رونے کے لیے غدودِ گریہ بخشے ہیں۔ کثرتِ استعمال سے یہ بڑھ جائیں تو حساس طنز نگار دنیا سے یوں خفا ہو جاتے ہیں جیسے اگلے وقتوں میں آقا نمک حرام لونڈیوں سے روٹھ جایا کرتے تھے۔ لغزشِ غیر پر انہیں ہنسی کے بجائے طیش آجاتا ہے۔ ذہین لوگوں کی ایک قسم وہ بھی ہے جو احمقوں کا وجود سرے سے برداشت ہی نہیں کر سکتی۔ لیکن، جیسا کہ مارکوئس دی سید نے کہا تھا، وہ بھول جاتے ہیں کہ سبھی انسان احمق ہوتے ہیں۔ موصوف نے تو یہ مشورہ بھی دیا ہے کہ اگر تم واقعی کسی احمق کی صورت نہیں دیکھنا چاہتے تو خود کو اپنے کمرے میں مقفّل کر لو اور آئینہ توڑ کر پھینک دو۔
لیکن مزاح نگار کے لیے نصیحت، فصیحت اور فہمائش حرام ہیں۔ وہ اپنے اور تلخ حقائق کے درمیان ایک قد آدم دیوارِ قہقہ کھڑی کر لیتا ہے۔ وہ اپنا روئے خنداں، سورج مکھی پھول کی مانند، ہمیشہ سرچشمۂ نور کی جانب رکھتا ہے اور جب اس کا سورج ڈوب جاتا ہے تو اپنا رخ اس سمت کر لیتا ہے، جدھر سے وہ پھر طلوع ہوگا؛
ہمہ آفتاب بینم، ہمہ آفتاب گویم
نہ شبنم، نہ شب پر ستم کہ حدیث خواب گویم
حسّ مزاح ہی اصل انسان کی چھٹی حس ہے۔ یہ ہو تو انسان ہر مقام سے آسان گزر جاتا ہے۔ یوں تو مزاح، مذہب اور الکحل ہر چیز میں با آسانی حل ہو جاتے ہیں، بالخصوص اردو ادب میں۔ لیکن مزاح کے اپنے تقاضے، اپنے ادب آداب ہیں۔ شرطِ اوّل یہ کہ برہمی، بیزاری اور کدورت دل میں راہ پائے۔ ورنہ بومرنگ پلٹ کر خود شکاری کا کام تمام کردیتا ہے۔ مزا تو جب ہے کہ آگ بھی لگے اور کوئی انگلی نہ اٹھا سکے کہ’’یہ دھوآں سا کہاں سے اٹھتا ہے؟‘‘ مزاح نگار اس وقت تک تبسم زیرِ لب کا سزاوار نہیں، جب تک اس نے دنیا اور اہلِ دنیا سے رج کے پیار نہ کیا ہو۔ ان سے، ان کی بے مہری و کم نگاہی سے۔ ان کی سَر خوشی و ہوشیاری سے۔ ان کی تر دامنی اور تقدس سے۔ ایک پیمبر کے دامن پر پڑنے والا ہاتھ گستاخ ضرور ہے، مگر مشتاق و آرزو مند بھی ہے۔ یہ زلیخا کا ہاتھ ہے۔ خواب کو چھو کردیکھنے والا ہاتھ۔
صبا کے ہاتھ میں نرمی ہے ان کے ہاتھوں کی
ایک صاحبِ طرز ادیب نے، جو سخن فہم ہونے کے علاوہ ہمارے طرف دار بھی ہیں (تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ سود خوار ہوتا…. کی حد تک) ایک رسالے میں دبی زبان سے شکوہ کیا کہ ہماری شوخیٔ تحریر مسائل حاضرہ کے عکس اور سیاسی سوز و گداز سے عاری ہے۔ اپنی صفائی میں ہم مختصرًا اتنا ہی عرض کریں گے کہ طعن و تشنیع سے اگر دوسروں کی اصلاح ہوجاتی تو بارود ایجاد کرنے کی ضرورت پیش نہ آتی۔
لوگ کیوں، کب اور کیسے ہنستے ہیں، جس دن ان سوالوں کا صحیح صحیح جواب معلوم ہوجائے گا، انسان ہنسنا چھوڑ دے گا۔ رہا یہ سوال کہ کس پر ہنستے ہیں؟ تو اس کا انحصار حکومت کی تاب و رواداری پر ہے۔ انگریز صرف ان چیزوں پر ہنستے ہیں، جو ان کی سمجھ میں نہیں آتیں۔۔۔ پنچ کے لطیفے، موسم، عورت، تجریدی آرٹ۔ اس کے برعکس، ہم لوگ ان چیزوں پر ہنستے ہیں، جو اب ہماری سمجھ میں آگئی ہیں۔ مثلاً انگریز، عشقیہ شاعری، روپیہ کمانے کی ترکیبیں، بنیادی جمہوریت۔
(اردو کے ممتاز مزاح نگار مشتاق یوسفی کے قلم سے)