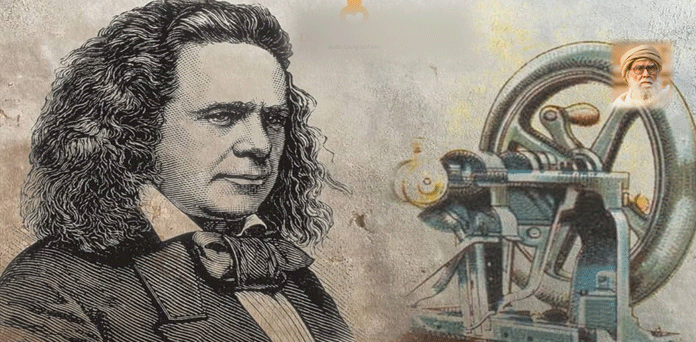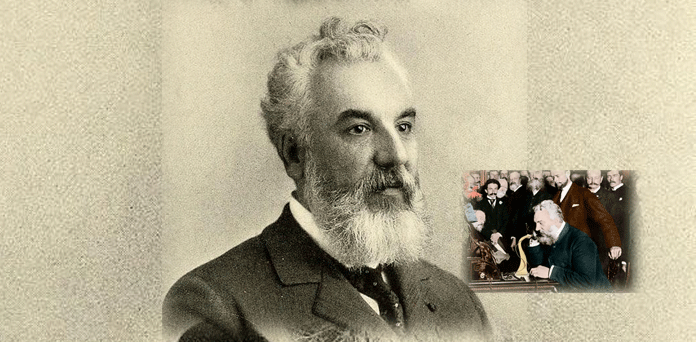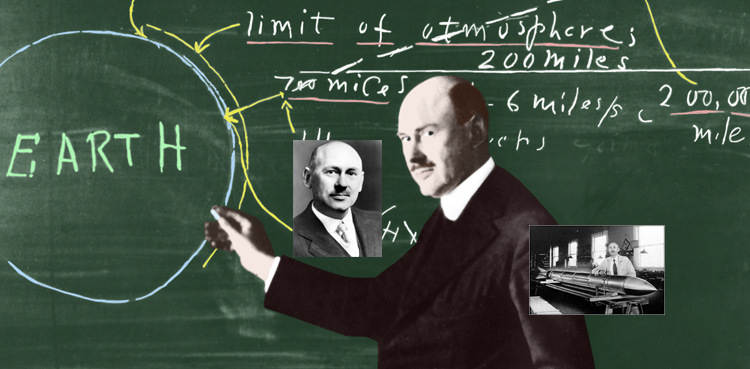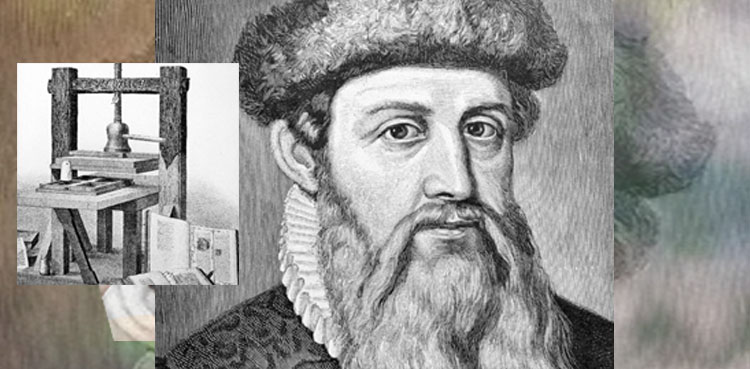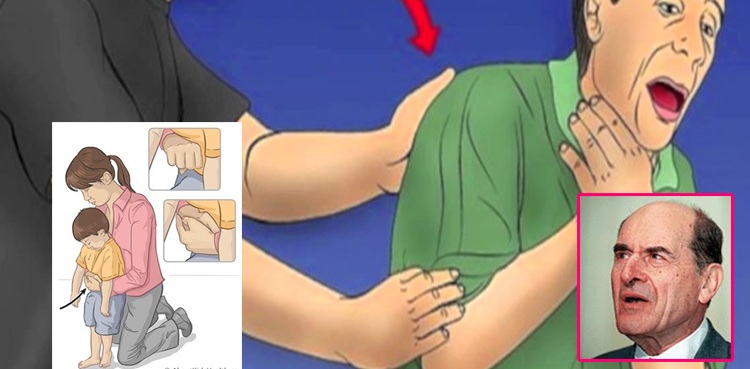کلیم الدّین احمد اردو زبان و ادب کی ایک مشہور مگر مشاہیر اور ہم عصروں میں متنازع بھی تھے جنھوں نے تنقید لکھی، شاعری کی اور مختلف موضوعات اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے مضامین سپردِ قلم کیے۔
ان کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا تھا کہ وہ اردو کی ہر چیز کو انگریزی کے مخصوص چشمے سے دیکھتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ انھیں اردو ادب میں کوئی چیز کام کی نظر نہیں آتی۔ کبھی وہ غزل جیسی مقبول اور ہر دور میں لائقِ ستائش اور معتبر صنف کو نیم وحشی کہہ کر مسترد کرتے ہیں تو کبھی لکھتے ہیں کہ اردو میں تنقید کا وجود محض فرضی ہے۔ الغرض کلیم الدّین احمد اپنے خیالات اور نظریات کی وجہ سے ہمیشہ متنازع رہے۔ انھوں نے فنونِ لطیفہ، ثقافت اور اصنافِ ادب کو جس طرح دیکھا اور سمجھا، اسے رقم کر دیا اور اپنی مخالفت کی پروا نہ کی۔
کلیم الدّین احمد 1908ء میں پیدا ہوئے تھے اور اسّی کی دہائی کے آغاز تک بقیدِ حیات رہے۔ انھوں نے وہ دور دیکھا جب ہندوستان میں ریڈیو تیزی سے مقبول ہوا اور معلومات کی فراہمی اور تفریح کا سب سے بڑا ذریعہ سمجھا گیا۔ آج کے دور میں ریڈیو سیٹ تو گھروں میں رہا ہی نہیں اور ٹیلی ویژن کی اہمیت بھی موبائل فون اور سوشل میڈیا کی وجہ سے ہر دن گھٹ رہی ہے، لیکن دہائیوں پہلے لوگ ریڈیو کو کیسی جادوئی اور نہایت اثرانگیز ایجاد تصور کرتے تھے اور ہندوستان میں اس کی کیا اہمیت تھی، یہ بتانے کے لیے کلیم الدّین احمد کے مضمون سے چند پارے حاضرِ خدمت ہیں۔ ملاحظہ کیجیے۔
"ریڈیو بھی سائنس کا ایک کرشمہ ہے اور دوسری سائنٹفک ایجادوں کی طرح ہم اس کا بھی خیر مقدم کرتے ہیں اور غیرناقدانہ طور پر اس کی تعریف میں رطبُ اللّسان ہوتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ سائنس چیزوں کی ایجاد کرتا ہے، لیکن ان چیزوں سے کام لینا ہمارا کام ہے۔”
"سائنس نے بہت سی چیزیں ایجاد کی ہیں۔ جن چیزوں کا ہمیں کبھی وہم و گمان بھی نہ تھا وہ واقعہ بنی ہوئی ہیں۔ جو باتیں ہم خیالی داستانوں میں پڑھا یا سنا کرتے تھے وہ اب خیالی نہیں رہیں، زندہ حقیقت کی طرح چلتی پھرتی نظرآتی ہیں۔”
"داستانوں میں ہم جادو کے گھوڑے پر بیٹھ کر ہوا میں اڑتے پھرتے تھے، آج نئے نئے قسم کے ہوائی جہازوں میں بیٹھ کر ہم دور دراز کا سفر قلیل مدت میں طے کر سکتے ہیں۔ زمین اور سمندر میں سفر کر سکتے ہیں۔ دور کی خبریں سن سکتے ہیں۔ دور کی چیزیں دیکھ سکتے ہیں۔ غرض بہت سے ایسے کام کر سکتے ہیں جن کے تصور سے پہلے ہمارے دل کی تسکین ہوتی تھی۔ یہ چیزیں اچھی بھی ہیں اور بری بھی۔ اور ان کی اچھائی اور برائی استعمال پر منحصر ہے۔”
"ہوائی جہاز کو لیجیے۔ اس سے کتنی آسانیاں پیدا ہو گئی ہیں۔ خط کتابت اور سفر کی آسانی ہے۔ اسی سے مسٹر چرچل کی بیماری میں ضروری دوائیں جلد سے جلد پہنچائی جا سکتی ہیں، لیکن آج یہی ایک ایسے وسیع پیمانہ پر، جس کے تصور سے دل دھڑکنے لگتا ہے، قتل و خون، تباہی و بربادی، انسان کی خوف ناک مصیبتوں کا آلہ بنا ہوا ہے۔ سائنس نے ہوائی جہاز تو ایجاد کر دیا لیکن اس سے اچھا یا برا کام لینا تو انسان پر منحصر ہے۔ سائنس ہمیں یہ نہیں بتاتا اور نہ بتاسکتا ہے کہ ہم اس ایجاد سے کیا مصرف لیں۔ سائنس کو انسانی قدروں سے کوئی خاص سروکار نہیں۔ اس کی ایجادوں کی مدد سے انسانیت ترقی کر سکتی ہے اور انہی سے انسانیت تباہ و برباد بھی ہو سکتی ہے۔”
"آج کے خونیں مناظر کے تصور سے دل بے اختیار ہو کر کہہ اٹھتا ہے کاش سائنس نے یہ ترقیاں نہ کی ہوتیں۔ پھر انسانیت کو اس خون کے غسل سے سابقہ نہ پڑتا۔ سائنس کی ترقی کا ایک نتیجہ یہ بھی ہوا کہ پہلے سالہا سال کی جنگ میں جتنی جانیں تلف ہوتی تھیں اس قدر آج ایک روز میں ضائع ہو سکتی ہیں۔ توپیں، بم کے گولے، ٹینک، آبدوز کشتیاں، زہریلی گیس، مہلک امراض کے جراثیم، غرض ایک لامتناہی سلسلہ ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انسانیت خودکشی پر آمادہ ہے اور اس جرم میں سائنس اس کا معین و مددگار ہے۔”
"ظاہر ہے کہ کسی چیز کی صرف اس لیے کہ وہ سائنس کی حیرت انگیز ایجاد ہے، ہم بے سوچے سمجھے تعریف نہیں کر سکتے۔ اس قسم کی تعریف ہماری بے صبری کی دلیل ہے اور یہ بھی صحیح ہے کہ سائنس کی کسی ایجاد سے ناجائز مصرف لینے کا ذمہ دار انسان ہے سائنس نہیں۔ کہہ سکتے ہیں کہ سائنس تو ہمیں قتل و غارت کی تلقین نہیں کرتا، انسان کو خود کشی پر نہیں ابھارتا، اس لیے سائنس موردِ الزام نہیں۔ یہ بات ایک حد تک صحیح ہے لیکن ہمیں یہ نہ بھولنا چاہیے کہ سائنس پر سماجی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ یہ انسانی بہبود کے لیے عالمِ وجود میں آیا اور اسے مقصد کو کبھی نہ بھولنا چاہیے۔ سائنس تباہی و بربادی کے سامان مہیا کر کے علیحدگی اختیار نہیں کرسکتا اور یہ کہہ کر الزام سے بری نہیں ہو سکتا کہ چیزیں تو ایجاد ہو گئیں، اب ان سے کام لینا میرا کام نہیں۔ سائنس اور سائنس داں کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنی ایجاد کی ہوئی چیزوں کو انسانیت کی تباہی کا ذریعہ نہ بننے دیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ سائنس کو اپنے مقام سے واقف ہونا چاہیے۔ اگر یہ اپنے حد سے نہ بڑھے، اپنی خامیوں اور حدود سے واقف ہو اور خدائی کا دعویٰ نہ کرے تو بہت سے الزام جو اس پر عائد ہوتے ہیں ان سے محفوظ رہے گا۔”
"غرض ریڈیو یا سائنس کی کوئی دوسری ایجاد اپنی جگہ پر اچھی بھی ہو سکتی ہے اور بری بھی۔ اس ریڈیو سے بہت سے اچھے کام لیے جا سکتے ہیں۔ جلد ضروری خبریں بھیجی جاسکتی ہیں۔ ضرورت کے وقت مدد طلب کی جا سکتی ہے۔ ایسی جگہوں میں جو ایک دوسرے سے کافی فاصلہ پر واقع ہوئی ہیں، براہ راست ربط قائم رکھا جا سکتا ہے۔ دوری کا مسئلہ ریڈیو اور ہوائی جہاز کی وجہ سے حل ہو گیا ہے، دنیا مختصر اور سمٹی ہوئی ہو گئی ہے۔ سماجی اور بین الاقوامی تعلقات میں آسانیاں ہیں اور مختلف کلچر ایک دوسرے سے الگ نہیں بلکہ سب آپس میں مل رہے ہیں اور مل کر ایک اعلیٰ انسانیت کا نمونہ قائم کر سکتے ہیں۔ یہ سب سہی لیکن اسی ریڈیو سے ناجائز مصرف لیا جا سکتا ہے۔ غلط خبریں نشر کی جا سکتی ہیں۔ جنگ میں اس سے اسی قدر مہلک کام لیا جا سکتا ہے جتنا بری و بحری اور ہوائی فوجوں سے۔ اسی سے انسان کے ذہن کوغلام بنایا جا سکتا ہے، اس کی روح کو جراثیم کا شکار بنایا جا سکتا ہے۔ لیکن ہم ان باتوں پر زیادہ غور و فکر نہیں کرتے اور جو چیز رائج ہو جاتی ہے اسے قبول کر لیتے ہیں۔”
"ریڈیو کا رواج مغربی ملکوں میں عام ہے اور اب ہندوستان میں بھی عام ہو چکا ہے۔ مختلف ریڈیو اسٹیشن قائم ہوئے ہیں اور صبح سے رات تک پروگرام جاری رہتا ہے جیسے سنیما کا رواج عام ہے اور اسے عموماً زندگی کی ضروریات میں شمار کیا جاتا ہے۔ بہت کم لوگ ہیں جو سنیما کی اچھائی برائی کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں۔ اسے تفریح کا ایک اچھا ذریعہ خیال کیا جاتا ہے۔ سنیما اور کلچر میں کیا تعلق ہے، اس مسئلہ پر ہم سوچنے کی زحمت گوارا نہیں کرتے۔ اسی طرح اخباروں کا مسئلہ ہے۔ اخباری اشتہاروں کا مسئلہ ہے۔ بازاری رسالوں، افسانوں اور ناولوں کا مسئلہ ہے۔ غرض ایسے کتنے مسائل ہیں جن پر غور و فکر کی ضرورت ہے کہ یہ چیزیں انسانیت کی ذہنی خودکشی کا ذریعہ نہ بن جائیں۔ ہم ہیں کہ کچھ سمجھتے ہی نہیں۔”
"ہاں تو ریڈیو کا مسئلہ کوئی الگ مسئلہ نہیں لیکن اتنی فرصت نہیں کہ ان سب مسئلوں پر ایک نظر ڈالی جائے اور شاید اس کی ضرورت بھی نہیں کیونکہ ریڈیو نے اخباروں، اشتہاروں، تصویروں، بازاری رسالوں اور افسانوں کو گویا اپنی وسیع آغوش میں لے لیا ہے۔ اس لیے جو کچھ ریڈیو کے بارے میں کہا جائے وہ اور چیزوں پر بھی منطبق ہوگا۔”