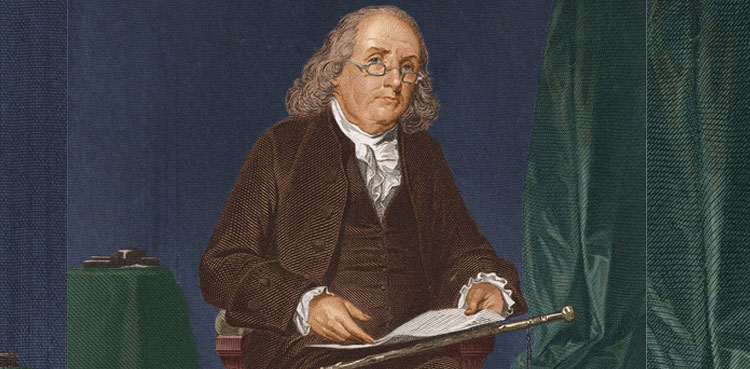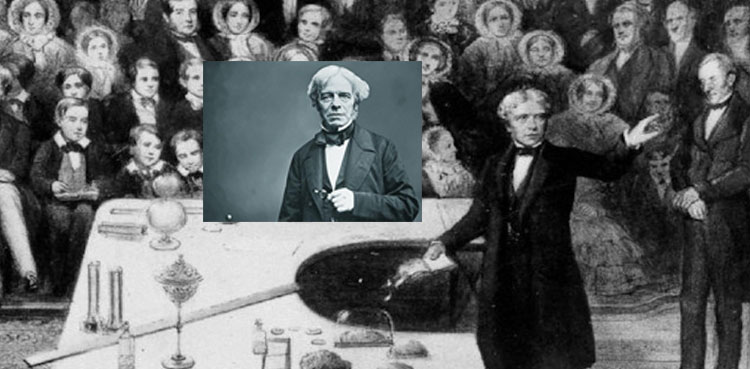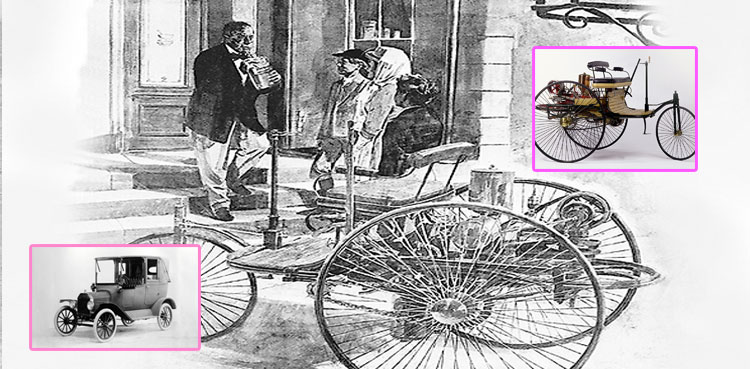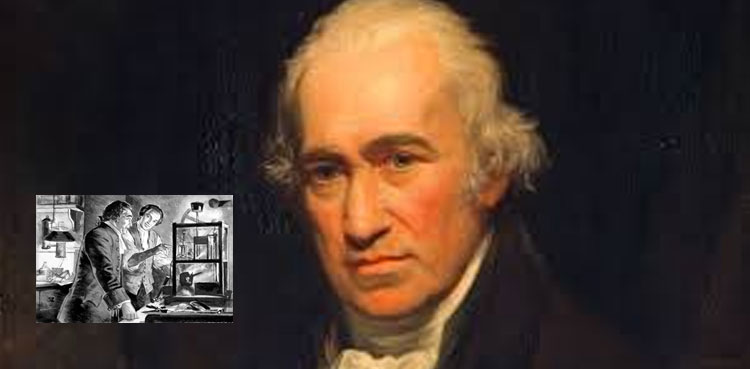علم و فنون کی دنیا میں اپنی قابلیت اور کسی شعبے میں اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر نام و مقام پانے والوں میں جون برنولی وہ ریاضی دان ہے جس کا پورا گھرانہ ہی علمی کارناموں کے سبب پہچانا گیا۔ برنولی خاندان میں کئی فن کار اور سائنس داں گزرے ہیں جنھیں شہرت حاصل ہوئی۔
برنولی خاندان بیلجیئم سے سوئٹزر لینڈ کے شہر بازیل آکر آباد ہوا تھا۔ جون برنولی اسی شہر میں پیدا ہوا اور سوئس ریاضی داں کی حیثیت سے شہرت حاصل کی۔ اس نے 27 جولائی 1667ء کو بازیل میں آنکھ کھولی تھی۔ وہ اپنے وقت کے مشہور ریاضی داں لیونہارڈ اویلر کا استاد بھی رہا۔ جون برنولی نے یکم جنوری 1748ء کو وفات پائی۔
جون کے والد نکولس برنولی تھے جن کی خواہش تھی کہ بیٹا کاروبار سے متعلق تعلیم حاصل کرے اور مسالوں کی تجارت کا وہ کام سنبھال سکے جسے انھوں نے بڑی محنت سے ترقی دی تھی۔ لیکن جون برنولی اس میں دل چسپی نہیں لے رہا تھا اور اس نے اپنے باپ کو اس بات پر قائل کرلیا کہ وہ طب کی تعلیم حاصل کرے گا۔ تاہم اسے یہ مضمون بھی پسند نہیں آیا اور اس نے ریاضی میں دل چسپی لینی شروع کر دی۔ جون برنولی نے بازیل شہر کی ایک جامعہ میں داخلہ لیا اور تعلیم کا سلسلہ شروع کردیا، لیکن وہ اپنے بڑے بھائی جیکب برنولی سے خاص طور پر ریاضی کے مسائل پر بحث کرتا اور اس کے ساتھ مل کر ریاضی کے مضمون کی گتھیاں سلجھاتا رہتا۔ اسی زمانے میں جون نے اپنے سب بھائیوں کے ساتھ مل کر کیلکولس پڑھنا شروع کیا اور اس پر کافی وقت لگایا۔ وہ پہلا ریاضی داں تھا جس نے کیلکولس کو بہت سمجھا اور اس کی مدد سے کئی مسائل حل کرنے کی کوشش کی۔ یونیورسٹی سے فارغ ہونے کے بعد جون نے باقاعدہ کیلکولس پڑھانا شروع کر دی۔ 1694ء میں اس کی شادی ہوگئی اور وہ ہالینڈ میں یونیورسٹی میں ریاضی کا پروفیسر بن گیا۔ 1705ء میں وہ بازیل واپس آیا جہاں اپنے بھائی اور استاد جیکب برنولی کی وفات کے بعد جامعہ بازیل میں اس کی جگہ تدریس شروع کی۔
یہ جان کر آپ کو حیرت بھی ہوگی اور برنولی خاندان کی شخصیات میں دل چسپی بھی محسوس ہوگی کہ بالخصوص ریاضی کے مضمون میں وہ جیسے جیسے ترقی کررہے تھے اور ان کا شہرہ ہورہا تھا، اسی طرح ان میں حسد جیسا جذبہ بھی پروان چڑھ رہا تھا۔ یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہونے سے پہلے جون اور اس کا بھائی جیکب ایک ساتھ کام کرتے تھے مگر بعد میں وہ آپس میں مقابلے بازی کرنے لگے۔ ایک دوسرے پر برتری جتانے اور اپنے کام کو زیادہ اہم بتاتے ہوئے دوسرے کے علمی کام کو کم درجہ کا یا غلط ثابت کرنے کی کوشش کی۔ جیکب برنولی کا تو انتقال ہو گیا، لیکن اس کی وفات کے بعد جون برنولی اپنے ہی بیٹے اور مشہور ریاضی داں ڈینیل برنولی دوم سے حسد محسوس کرنے لگا۔ یہ 1738ء کی بات ہے جب ان دونوں نے الگ الگ سيالی حرکيات (fluid dynamics) پر مقالہ لکھا، لیکن افسوس کی بات ہے کہ جون برنولی نے اپنے ہی بیٹے پر برتری حاصل کرنے کی غرض سے اور دنیا کے سامنے اپنی کاوش کی اہمیت منوانے کے لیے اپنے مقالے کو دو سال پرانا بتایا تھا۔ اس کے لیے جون برنولی نے اپنے مقالے پر دو سال پہلے کی ایک تاریخ ڈال دی تھی۔