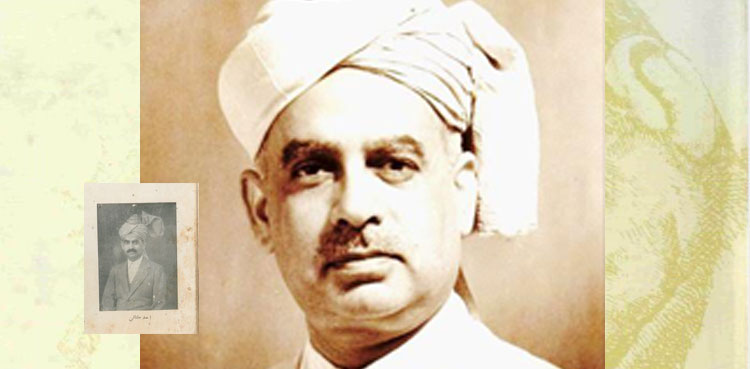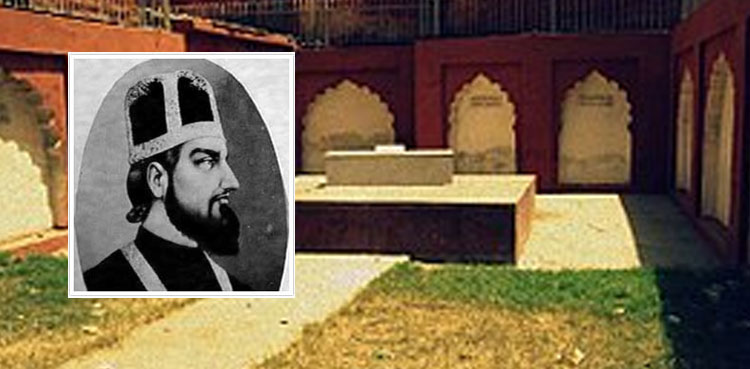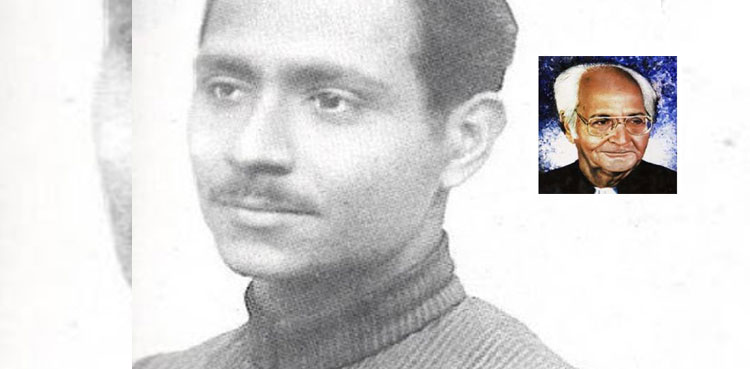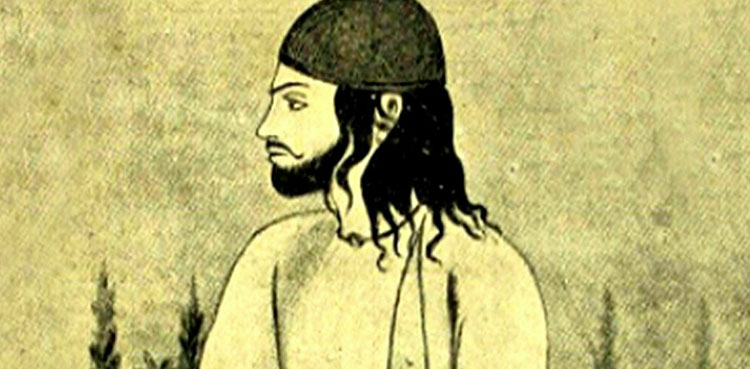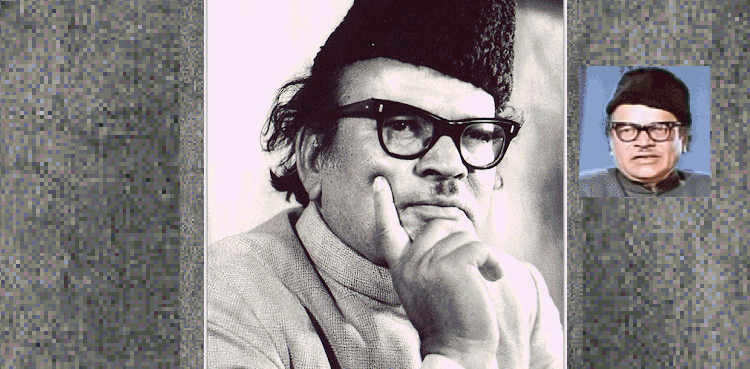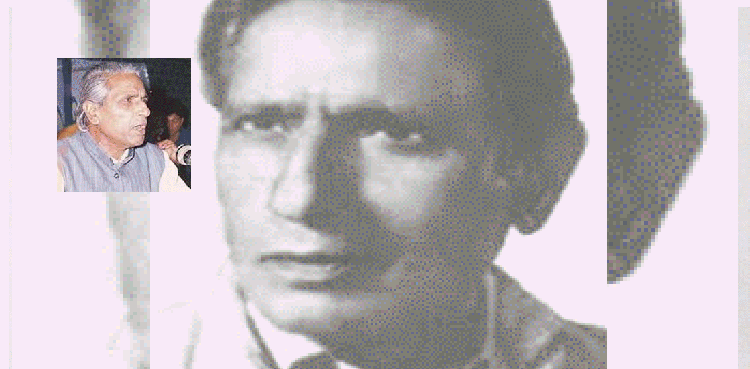سلام مچھلی شہری اپنے زمانے کے ایک مقبول شاعر تھے۔ رومانوی شاعری میں منفرد راہ نکالنے والے اس شاعر نے غزل اور نظم دونوں اصنافِ سخن میں طبع آزمائی کی۔
اس دور میں سلام نے ایک بالکل نئے طرز کی رومانی شاعری کی اور خاص طور پر نوجوانوں میں مقبول ہوئے۔ سلام مچھلی شہری نے اپنی ریڈیو کی ملازمت کے زمانے میں کئی منظوم ڈرامے اور اوپیرا بھی لکھے۔ وہ نثر نگار بھی تھے اور ’بازو بند کھل کھل جائے‘ کے نام سے ان کا ایک ناول بھی شایع ہوا۔
یکم جولائی 1921ء کو انھوں نے مچھلی شہر جونپور کے ایک گھرانے میں آنکھ کھولی۔ تعلیم کا سلسلہ صرف ہائی اسکول تک محدود رہا اور کسی طرح الٰہ آباد یونیورسٹی کے کتب خانے میں ملازمت مل گئی۔ یہاں انھوں نے علم و مطالعہ کا شوق خوب پورا کیا۔ انھیں لائبریری کی ملازمت کے دوران کئی موضوعات پر کتب اور مختلف زبانوں کے ادب کو پڑھنے کا موقع ملا جس نے انھیں ادبی فکر و تخلیق میں مدد دی۔ 1943ء میں سلام مچھلی شہری لکھنؤ ریڈیو اسٹیشن پر مسوّدہ نویسی پر مامور ہوئے۔ اور بعد میں اسسٹنٹ پروڈیوسر کی حیثیت سے سری نگر ریڈیو اسٹیشن پر تبادلہ ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد دہلی میں ریڈیو اسٹیشن پر پروڈیوسر کے طور پر ان کا تقرر ہوگیا۔ اس عرصے میں ان کا شعری سفر جاری رہا اور وہ ایک رومانی شاعر کے طور پر پہچانے گئے۔ انھیں بھارتی حکومت نے ’پدم شری‘ سے بھی نوازا۔
سلام مچھلی شہری کے تین شعری مجموعے ’ میرے نغمے‘ ،’وسعتیں‘، اور’ پائل‘ شایع ہوئے۔ انھوں نے 19 نومبر 1973ء کو دہلی میں وفات پائی۔ سلام مچھلی شہری کی یہ مشہور نظم ملاحظہ کیجیے۔
بہت دنوں کی بات ہے
فضا کو یاد بھی نہیں
یہ بات آج کی نہیں
بہت دنوں کی بات ہے
شباب پر بہار تھی
فضا بھی خوش گوار تھی
نہ جانے کیوں مچل پڑا
میں اپنے گھر سے چل پڑا
کسی نے مجھ کو روک کر
بڑی ادا سے ٹوک کر
کہا تھا لوٹ آئیے
مری قسم نہ جائیے
نہ جائیے نہ جائیے
مجھے مگر خبر نہ تھی
ماحول پر نظر نہ تھی
نہ جانے کیوں مچل پڑا
میں اپنے گھر سے چل پڑا
میں چل پڑا میں چل پڑا
میں شہر سے پھر آ گیا
خیال تھا کہ پا گیا
اسے جو مجھ سے دور تھی
مگر مری ضرور تھی
اور اک حسین شام کو
میں چل پڑا سلام کو
گلی کا رنگ دیکھ کر
نئی ترنگ دیکھ کر
مجھے بڑی خوشی ہوئی
میں کچھ اسی خوشی میں تھا
کسی نے جھانک کر کہا
پرائے گھر سے جائیے
مری قسم نہ آئیے
نہ آئیے، نہ آئیے
وہی حسین شام ہے
بہار جس کا نام ہے
چلا ہوں گھر کو چھوڑ کر
نہ جانے جاؤں گا کدھر
کوئی نہیں جو ٹوک کر
کوئی نہیں جو روک کر
کہے کہ لوٹ آئیے
مری قسم نہ جائیے
بہت دنوں کی بات ہے
فضا کو یاد بھی نہیں
یہ بات آج کی نہیں
بہت دنوں کی بات ہے