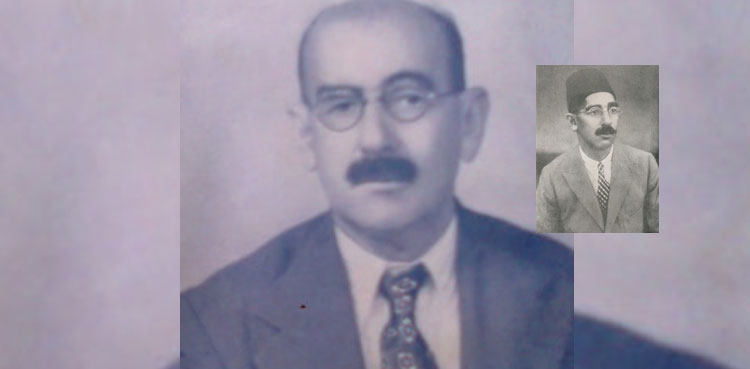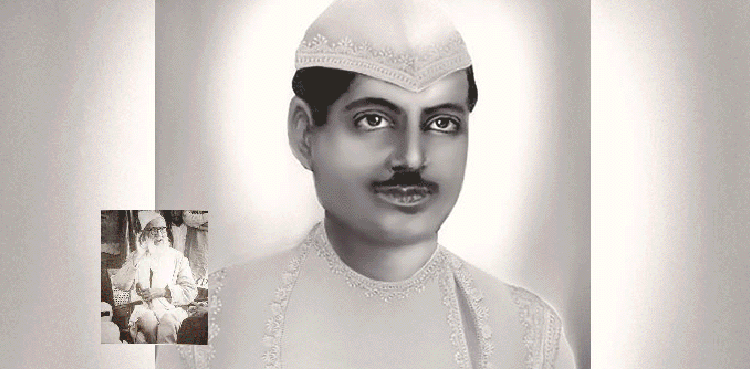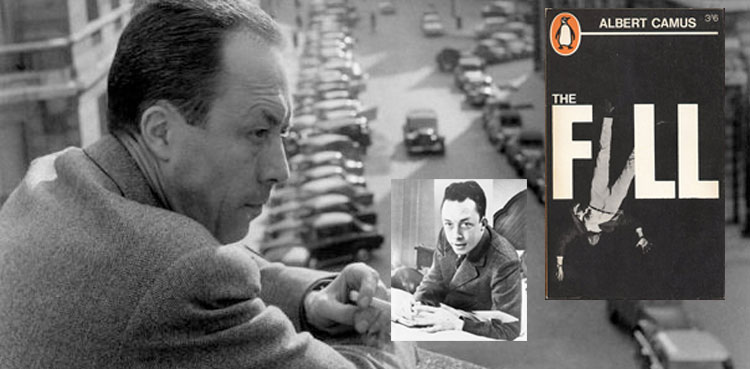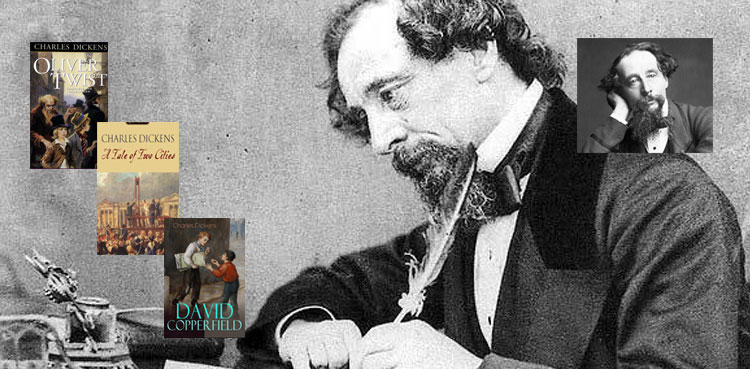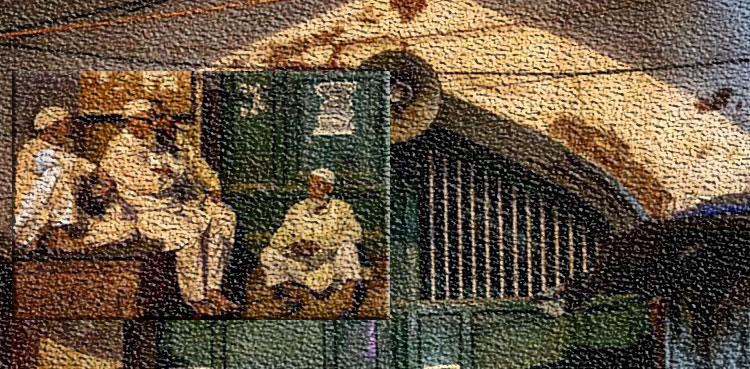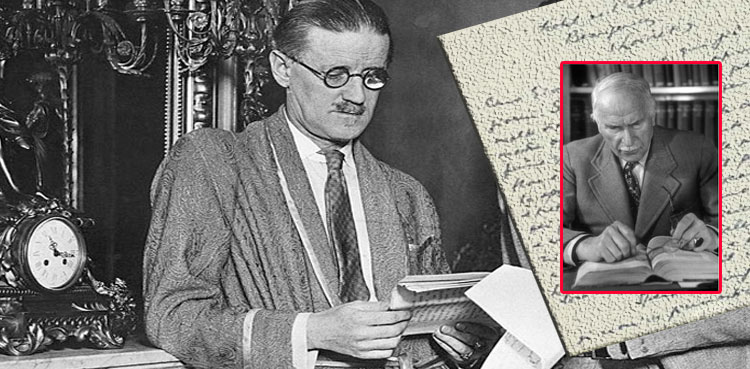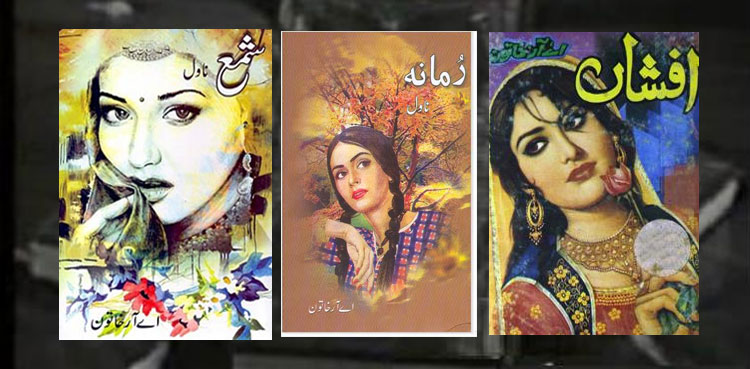حجاب امتیاز علی نے تاریخ، نفسیات، سائنس، علمِ نجوم اور مذاہبِ عالم کا مطالعہ جم کر کیا تھا، اِس لیے وہ کردار نگاری کی سطح پر دادی زبیدہ، جسوتی، سر جعفر، ڈاکٹر گار، زوناش اور چچا لوث جیسے بڑے رومانی کردار خلق کر پائیں۔
یہ سب کردار حجاب کے تخلیق کردہ فنٹاسٹک ماحول میں جیتے ہیں۔ یہ حجاب کی خیالی ریاستوں شموگیہ اور کیباس کے باشندے ہیں جو اکثر چہل قدمی کرتے ہوئے حجاب کے خلق کردہ خیالی جنگل ناشپاس تک چلے جاتے ہیں۔
حجاب امتیاز علی اپنی افتادِ طبع کی تشکیل سے متعلق خود بتاتی ہیں، ’’میری ادبی زندگی کا گہرا تعلق میرے بچپن کی تین چیزوں سے ہے۔ فضا، ماحول اور حالات۔ میرے بچپن کا ابتدائی زمانہ جنوب میں دریائے گوداوری کے ہوش رُبا کناروں پر گزرا۔
ہوتا یہ تھا کہ کالی اندھیری راتوں میں گوداوری کے سنسان کناروں پر ہندوﺅں کی لاشیں جلائی جاتی تھیں۔ جلانے کے دوران ہڈیاں اور سَر اس قدر ڈراﺅنے شور کے ساتھ چیختے تھے کہ انہیں سن کر ہوش اڑ جاتے تھے۔ اس سرزمین پر گوشت پوست سے عاری انسانی ڈھانچے اور ہڈیاں جگہ جگہ پڑی رہتی تھیں اور چیخ چیخ کر انسان کے فانی ہونے کا یقین دلایا کرتی تھیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ جب ان ساحلوں پر رات پڑتی تو ہڈیوں کا فاسفورس اندھیرے میں جل اٹھتا تھا اور میلوں فاصلے سے غولِ بیابانی کی طرح ان ویرانوں میں روشنیاں رقصاں نظر آتی تھیں۔ یہ دہشت خیز منظر ہیبت ناک کہانیوں کے لکھنے کی ترغیب دیتا تھا۔ غرض ان کا حسن اور رات کی خوف ناکی، یہ تھی فضا۔ ایسی فضا میں جو شخص بھی پلے اور بڑھے اس میں تھوڑی بہت ادبیت، شعریت اور وحشت نہ پیدا ہو تو اور کیا ہو۔
تیسری بات حالات کی تھی۔ جنھوں نے مجھے کتاب و قلم کی قبر میں مدفون کر دیا۔ مدفون کا لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا کہ اگر میں نے اس زمانے میں اپنے آپ کو ادبی مشاغل میں دفن نہ کردیا ہوتا تو میں کبھی کی ختم ہوگئی ہوتی۔ وہ زمانہ مرے لیے بے حد حزن و ملال کا تھا۔ مری والدہ ابھی جواں سال ہی تھیں کہ اللہ کو پیاری ہوگئیں۔ ان کی موت مرے خرمن پر بجلی بن کر گری۔ اس زمانے میں میرا ذہنی توازن درست نہ تھا۔ لڑکپن تھا، اس پر شدید ذہنی دھچکا ماں کی موت کا تھا۔ ان دونوں نے مل کر مجھے اعصابی بنا دیا تھا۔‘‘
(ممتاز ادیب حجاب امتیاز علی کی کتاب’’میری ادبی زندگی‘‘ سے اقتباس)