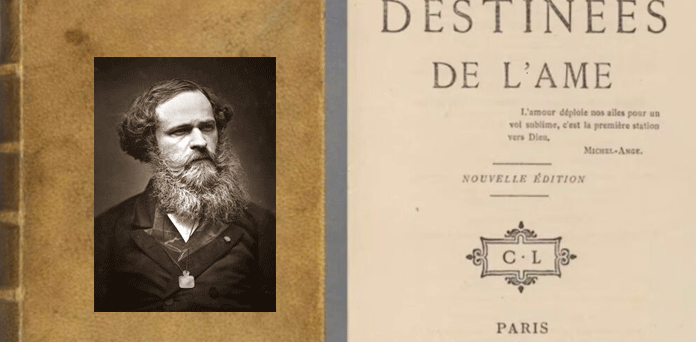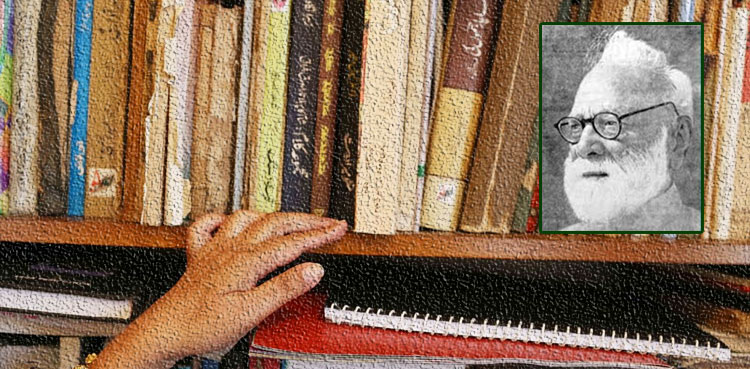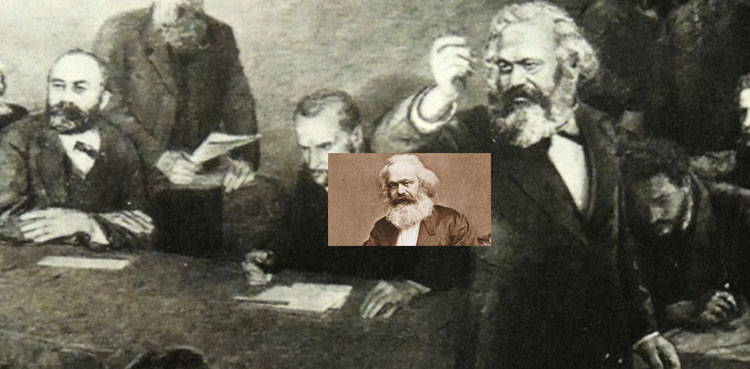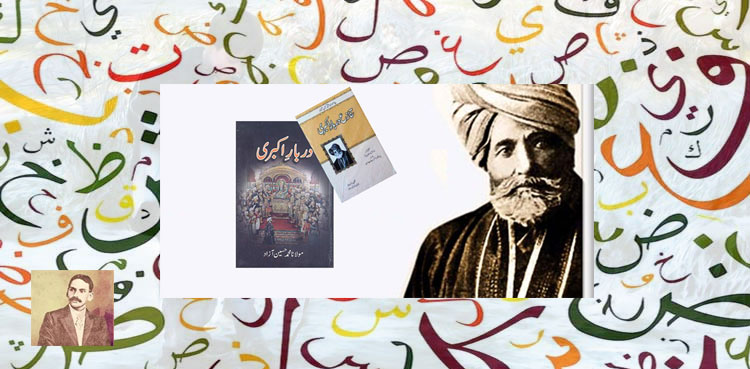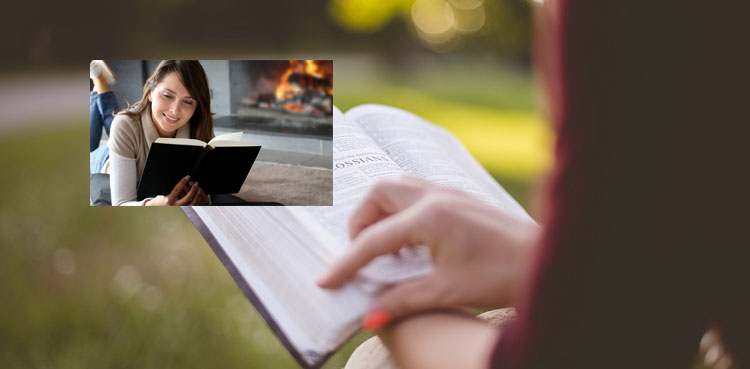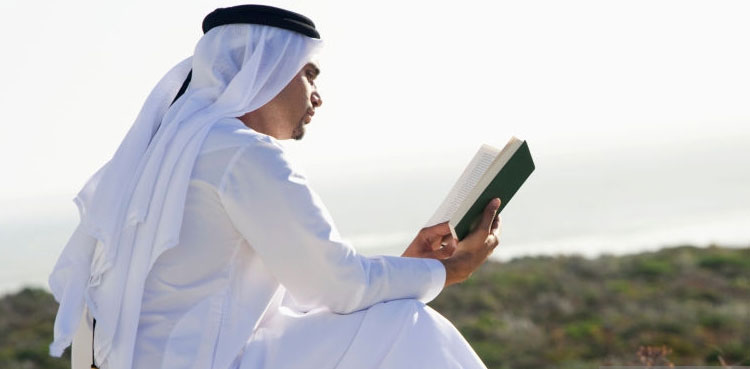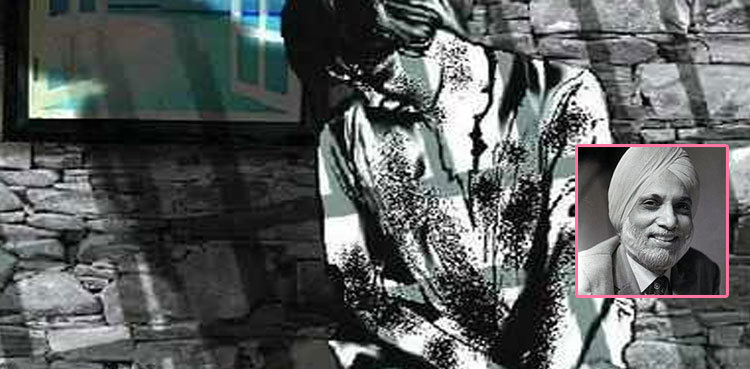’’شہاب نامہ‘‘ ایک اہم اور دل چسپ آپ بیتی ہے۔ یہ ایک ایسی دستاویز ہے جس میں بیسویں صدی کے تمام اہم سیاسی و تاریخی انقلابات کو قید کیا گیا ہے اور نسلِ انسانی پر ان انقلابات کے کیا اثرات مرتب ہوئے اس کی بھی مکمل تصویر کشی کی گئی ہے۔
یہ مصنف کی زندگی کے شب و روز کے حالات و واقعات کی ایک دل چسپ کہانی بھی ہے اور ان کے عہد کی ایک تلخ داستان بھی۔ اس کے اوراق معلومات افزا بھی ہیں اور درد انگیز بھی۔ اس کے صفحات تقسیم ہند کے دوران کے اُن وحشت ناک اور خوں ریز فسادات کی تصویر کشی سے بھرے پڑے ہیں جنہوں نے روئے زمین پر انسانیت کو ہمیشہ کے لیے شرمسار کر کے چھوڑا۔
اس کے مطالعہ سے 1947ء سے قبل کے ہندوستان کی سیاسی و سماجی صورتِ حال کو سمجھنے میں بڑی مدد ملتی ہے۔ اس میں ایک طرف حصول پاکستان کے سلسلے میں کانگریس اور مسلم لیگ کے مابین سیاسی رسہ کشی کا عالمانہ تجزیہ کیا گیا ہے وہیں دوسری طرف قیام پاکستان کے بعد اس کی ابتدائی مشکلات اور وہاں کے سیاست دانوں کے بارے میں دل چسپ معلومات بہم پہنچائی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ مسئلہ کشمیر اور اس کی تاریخ پر بھی تفصیل سے روشنی ڈالی گئی ہے۔ غرض اس کتاب میں مختلف موضوعات کو احاطۂ تحریر میں لیا گیا ہے لیکن قدرت اللہ شہاب نے ان تمام موضوعات کو آپ بیتی کی ہئیت میں اپنی ذات کے وسیلے سے بیان کیا ہے اور یہی اس خود نوشت سوانح عمری کی سب سے بڑی خوبی ہے۔
قدرت اللہ شہاب پاکستان کے نام ور سول سرونٹ اور ادیب تھے جو 1917ء کو گلگت میں پیدا ہوئے تھے۔ وہ انڈین سول سروس میں شامل رہے اور قیام پاکستان کے بعد متعدد اہم انتظامی عہدوں پر فائز رہے۔ یحییٰ خان کے دور حکومت میں وہ اپنے عہدے سے مستعفی ہو کر اقوام متحدہ کے ادارہ یونیسکو سے وابستہ ہوگئے۔ اس زمانے میں انہوں نے مقبوضہ عرب علاقوں میں اسرائیل کی شر انگیزیوں اور زیادتیوں کا پردہ چاک کیا۔ قدرت اللہ شہاب کا ایک اہم کارنامہ پاکستان رائٹرز گلڈ کی تشکیل تھا۔ وہ 1986ء میں وفات پاگئے تھے۔
شہاب نامہ کا آغاز ’’اقبالِ جرم‘‘ سے ہوتا ہے۔ یہ کتاب کا ابتدائیہ ہے جس میں قدرت اللہ شہاب نے اپنی آپ بیتی کے حوالے سے چند اہم معلومات بہم پہنچائی ہیں اور اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ ’’شہاب نامہ‘‘ کا بنیادی مقصد بت شکنی یا بت تراشی کے بجائے ان واقعات، مشاہدات اور تجربات کی روداد کو بے کم و کاست بیان کرنا ہے جنہوں نے انھیں متاثر کیا۔ قدرت اللہ شہاب اپنے اس دعویٰ پر پورا اترتے ہوئے نظر آتے ہیں اور پوری خود نوشت میں کہیں بھی اس بات کا شائبہ نہیں ہوتا کہ وہ کسی کی بت شکنی یا بت تراشی کررہے ہیں۔
قدرت اللہ شہاب نے اپنی خود نوشت سوانح عمری کا باقاعدہ آغاز اپنے بچپن کی حسین یادوں سے کیا ہے۔ اس میں ایسے نقوش دیکھنے کو ملتے ہیں جو ان کی آنے والی زندگی کا پتہ دیتے ہیں۔ اس میں سطحیت اور قناعت پسندی کے بجائے ارتقا کے عناصر نمایاں ہیں اور ایک اونچی پرواز بھرنے کا جذبہ بھی موجزن ہے۔ یہ بچپن شرارتوں، شوخیوں، بے باکیوں، نادانیوں اور رومان بھرے جذبات سے بھی عبارت ہے۔
قدرت اللہ شہاب کا بچپن جموں شہر کے اسکولوں اور وہاں کے گلی کوچوں میں اپنے ہم نواؤں کے ساتھ عیش وعشرت میں گزرا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب جموں و کشمیر ڈوگرا حکمرانوں کے زیرِ نگیں تھا اور ریاست کے مسلمانوں کے حالات ناگفتہ بہ تھے۔ قدرت اللہ شہاب نے جموں شہر کے گلی کوچوں، وہاں کے بازاروں نیز ان اسکولوں اور کالجوں جہاں انھوں نے تعلیم حاصل کی تھی، کا ذکر جس دل چسپ انداز میں کیا ہے وہ جموں سے ان کی گہری عقیدت اور محبت کا مظہر ہے۔
’’شہاب نامہ ‘‘ کے ابتدائی ابواب میں دو کہانیاں ایک ساتھ آگے بڑھتی ہیں۔ ایک کا تعلق مصنف کی نجی زندگی سے ہے اور دوسری اس وقت کے جموں و کشمیر کے سیاسی منظر نامے پر مشتمل ہے۔ یہ دونوں کہانیاں دل چسپ بھی ہیں اور معلومات افزا بھی۔ پہلی کہانی میں مصنّف نے اپنے بچپن کے احوال و کوائف اور تعلیمی زندگی کے نشیب و فراز کے ساتھ ساتھ اپنے خاندانی پس منظر کو بھی دل چسپ پیرائے میں بیان کیا ہے، نیز بچپن کی ایک ناکام محبت کی روداد کو بھی اپنی تمام تر کیفیات کے ساتھ صفحۂ قرطاس پر اتارا ہے۔ اس کہانی میں مصنف نے اپنے والد محمد عبداللہ کا بھی ایک خوب صورت اور جاذب نظر خاکہ کھینچا ہے۔
جموں و کشمیر کا سیاسی و سماجی منظر نامہ پیش کرنے کے بعد قدرت اللہ شہاب نے’’چندراوتی‘‘ کے عنوان کے تحت گورنمنٹ ڈگری کالج لاہور کا ذکر کیا ہے جہاں سے انھوں نے ایم۔ اے کیا تھا۔
اس باب کا مرکزی موضوع قدرت اللہ شہاب اور چندراوتی کی عشقیہ داستان ہے۔چندراوتی ایک ہندو لڑکی تھی جس کے عشق میں قدرت اللہ شہاب مبتلا ہو گئے تھے۔ وہ لیڈی میکلیکن کالج میں پڑھتی تھی۔ دونوں کی پہلی ملاقات پنجاب پبلک لائبریری، لاہور میں ایک ڈرامائی انداز میں ہوئی تھی۔ اس کے بعد ملاقاتوں کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہوا جو دھیرے دھیرے عشق کے گہرے رشتے میں تبدیل ہوگیا۔ لیکن یہ عشق ابھی پروان ہی چڑھ رہا تھا کہ اس پر اداسی کے سائے لہرانے لگے۔ چندراوتی اچانک ٹی۔ بی جیسی بیماری کا شکار ہوئی اور کچھ ہی دنوں میں قدرت اللہ شہاب کو غمِ ہجر کے دائمی درد سے ہمکنار کر کے دنیائے فانی سے کوچ کر گئی۔
قدرت اللہ شہاب نے ’’شہاب نامہ‘‘ میں خارجی دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی داخلی دنیا کی بھی تصویر کشی کی ہے۔ انھوں نے اپنی زندگی کے ان واقعات کو بھی سچائی اور دیانت داری کے ساتھ صفحۂ قرطاس پر اتارا ہے جن کو عام طور پر خود نوشت سوانح نگار مصلحتاً صیغۂ راز میں رکھتے ہیں یا اپنے گرد و پیش کی سماجی اور تہذیبی قدروں کو مدِنظر رکھ کر رمز و کنایہ کا سہارا لے کر بیان کرتے ہیں لیکن قدرت اللہ شہاب نے اپنی زندگی کے ایسے نازک معاملات اور سر بستہ اسرار و رموز کو بے کم و کاست بیان کیا ہے۔ انھوں نے نہ رمز و کنایہ کا سہارا لیا ہے، نہ تشبیہات و استعارات کا اور نہ اپنے معیار و مرتبے کی پروا کی ہے جو عام طور پر ایسے واقعات کو بیان کرنے میں رکاوٹ حائل کرتا ہے۔
قدرت اللہ شہاب نے گورنمنٹ ڈگری کالج، لاہور سے ایم۔اے کر نے کے بعد 1940 میں آئی۔ سی۔ ایس کا امتحان پاس کر کے جموں و کشمیر کا پہلا مسلم آئی۔ سی۔ ایس افسر بننے کا اعزاز حاصل کیا۔ انھوں نے اس کام یابی کا ذکر اپنی آپ بیتی کے ایک مخصوص باب میں ’’آئی۔ سی۔ ایس میں داخلہ‘‘ کے عنوان کے تحت بڑی تفصیل سے کیا ہے۔ اس باب کا سب سے اہم حصہ وہ ہے جس میں انھوں نے سر گورڈن ایرے، سرعبدالرحمٰن اور ڈاکٹر سر رادھا کرشنن کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے جو آئی۔ سی۔ ایس انٹرویو بورڈ کے ممبر تھے۔
قدرت اللہ شہاب نے اپنی ملازمت کا باقاعدہ آغاز بھاگلپور، بہار کے اسسٹنٹ کمشنر کی حیثیت سے کیا۔ انھوں نے بھاگلپور میں اپنے قیام کے دوران کی روداد کو ’’بھاگلپور اور ہندو مسلم فسادات ‘‘ کے عنوان کے تحت بڑے دل چسپ انداز میں تحریر کیا ہے۔ یہاں سے ان کی زندگی کا ایک نیا دور شروع ہوتا ہے اور ان کی خود نوشت سوانح عمری میں بھی ایک نیا موڑ آتا ہے۔ یہی وہ مقام بھی ہے جہاں سے ’’شہاب نامہ‘‘ کی فضاؤں پر سیاسی اور تاریخی عنصر کا گہرا رنگ بھی نمایاں ہونا شروع ہوجاتا ہے۔
قدرت اللہ شہاب نے تقسیم ہند کے ہر پہلو پر روشنی ڈالی ہے۔ انھوں نے حالات و واقعات کا بڑے عالمانہ اور دانش ورانہ انداز میں تجزیہ بھی کیا ہے۔ یہاں یہ بتا دینا ضروری ہے کہ ہر انسان کی طرح ان کا بھی اپنا ایک نقطۂ نظر ہے اور جس کا انھیں حق بھی حاصل ہے۔
دیکھا جائے تو ’’شہاب نامہ‘‘ ایک ایسی کتاب ہے جو قاری کو پاکستان کے ایوانِ اعلیٰ کے اندر کے ماحول سے متعارف کراتی ہے اور اس کے سامنے ایسے راز کھول کر رکھ دیتی ہے جن تک اس کی رسائی ممکن نہ تھی۔ یہ پاکستانی سیاست کے در پردہ رازوں کی سچی عکاس ہونے کے ساتھ ساتھ اس عہد میں پاکستان کے ایوانِ حکومت میں ہونے والی ان خفیہ سیاسی ریشہ دوانیوں کی بھی چشم دید داستان ہے جنہوں نے سیاسی، سماجی، معا شی اور دفاعی معاملات کے ساتھ ساتھ پاکستان کے جغرافیہ پر بھی اپنے منفی اثرات مرتب کیے۔
انھوں نے حکمرانوں کے دل چسپ خاکے بھی کھینچے ہیں اور ان کے مزاج، کردار، عادات و اطوار، مذہبی عقائد اور گھریلو ماحول کے ساتھ ساتھ ان کی عملی زندگی کے خوب صورت نقش بھی ابھارے ہیں۔ نیز صحافت، سیاست، تعلیم، ادب، بیورو کریسی، معاشیات،خارجہ پالیسی اور عوام سے متعلق ان کے نظریات کو بھی مثالوں اور حوالوں کے ساتھ احاطۂ تحریر میں لیا ہے۔
قدرت اللہ شہاب نے شہاب نامہ میں تقسیم ہند، کشمیر اور پاکستانی سیاست کے نشیب و فراز کے حوالے سے جو حالات و واقعات تحریر کیے ہیں وہ اخباری رپورٹوں، سنی سنائی باتوں یا محض کسی جذباتی و انسانی وابستگی کے بجائے آنکھوں دیکھے حالات و واقعات کے ساتھ ساتھ براہ راست مشاہدات پر مبنی ہیں۔
شہاب نامہ کی دنیا میں اگرچہ بہت وسعت، گہرائی، گیرائی ہے، موضوعات کا تنوع ہے، ضخامت ہے لیکن زبان ایسی دل کش ہے کہ پڑھنے والا اس کے سحر میں اس قدر ڈوب جاتا ہے کہ اسے کتاب کے اختتام تک اس وسعت، گہرائی، گیرائی، موضوعات کے تنوع اور ضخامت کا کوئی احساس نہیں ہوتا اور نہ ہی الفاظ، تشبیہات، استعارات اور محاورات کے مناسب استعمال سے پیدا ہونے والی سحر خیزی اس کا احساس ہونے دیتی ہے۔
’’شہاب نامہ‘‘ میں ایسی تحریریں بھی شامل کی ہیں جن کو آپ بیتی میں شامل کرنے کا نہ تو کوئی جواز بنتا تھا اور نہ ہی اس کے امکانات موجود تھے۔ یہ وہ تحریریں ہیں جو ان کی مشہور تخلیقات پر اردو کے نامور ادیبوں اور ناقدین نے لکھی ہیں۔
ہر چند کہ اس کتاب کے مواد اور قدرت اللہ شہاب کے نظریات کی مخالفت میں بہت کچھ لکھا بھی گیا لیکن اس کے باوجود اس کی مقبولیت میں کبھی کمی نہ آئی۔ اردو خود نوشت سوانح نگاری کی تاریخ میں موضوعات کے تنوع کے لحاظ سے اس نوع کی خود نوشتیں اگرچہ نایاب تو نہیں لیکن کم یاب ضرور ہیں۔