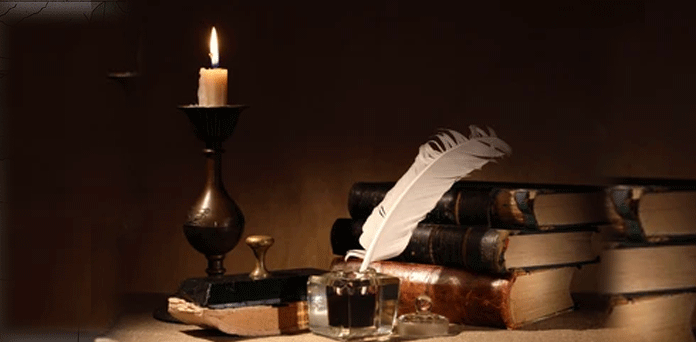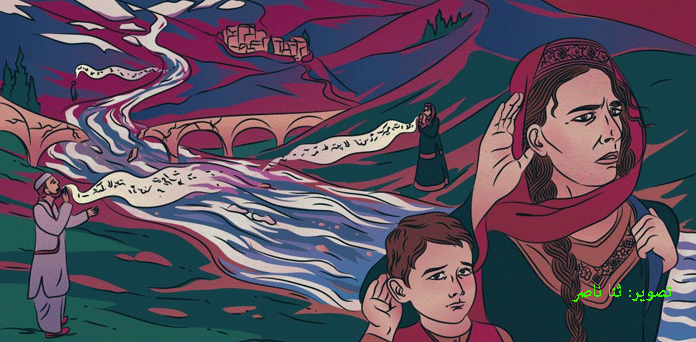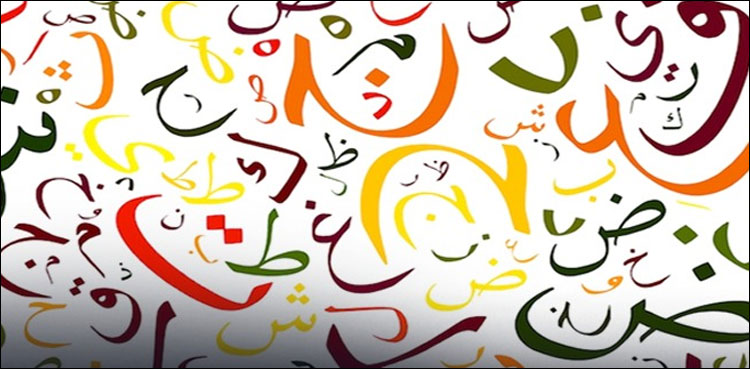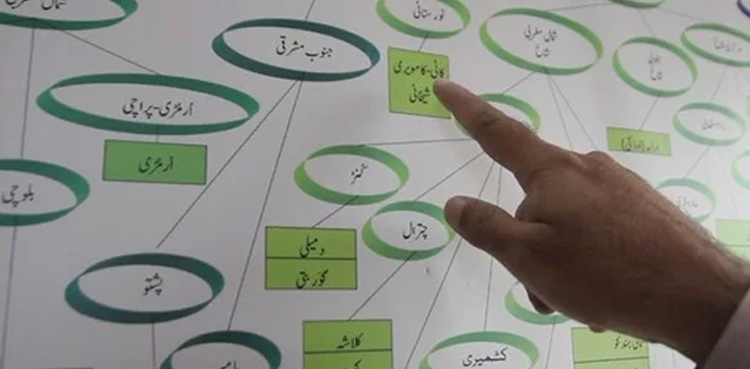برصغیر میں ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش شامل ہیں۔ تینوں ممالک کے درمیان سیاسی تقسیم بیسویں صدی میں ہوئی؛ اس سے قبل سارا خطہ ہندوستان ہی کہلاتا تھا۔
صدیوں تک ہندوستانی معاشرہ تنوع سے عبارت رہا۔ جدید ہندوستان کے لوگ 18 بڑی زبانیں اور کئی چھوٹی زبانیں بھی بولتے ہیں۔ پاکستان کی سرکاری زبان اُردو جبکہ بنگلہ دیش کی بنگالی ہے۔ ساری تاریخ کے دوران مسلسل بیرونی لوگوں کو اپنے اندر جذب کرنے کے باعث ہندوستانی ادب دنیا کا بھرپور ترین ادب بن گیا۔ قدیم ہندوستان میں سنسکرت ہی غالب رہی اور فلسفیانہ و ادبی تحریروں میں استعمال ہوئی۔ چھٹی صدی قبل مسیح میں بدھ مت اور جین مت کے مقبول ہونے پر پالی زبان میں ادب کو فروغ ملا اور سنسکرت کے متعدد لہجے (پراکرت) بھی پیدا ہوئے۔ دریں اثناء دراوڑی زبان تامل جنوب کے علاقے میں اہم ترین زبان بنی۔ تامل زبان میں ریکارڈ شدہ ادب پہلی صدی عیسوی کا ہے۔ تامل، تیلگو، کناڈا اور ملیالم میں بھی ادب لکھا گیا۔
دسویں اور اٹھارہویں صدی کے دوران قدیم زبانوں کے نئے لہجے وجود میں آئے اور ہندوستان کی جدید زبانیں تشکیل پائیں۔ اس کے ساتھ ادبی اصناف اور موضوعات میں بھی تنوع پیدا ہوا،نیز فارسی زبان و ادب نے بھی ہندوستانی ادب کو متاثر کیا۔ اسلامی فلسفہ و روایات کا رنگ بھی موجود ہے۔ ہندوستان کا تیسرا اہم مذہب جین مت تھا جس کی بنیاد مہاویر نے رکھی۔ ابتدائی جین ادب پراکرت لہجوں میں پروان چڑھا۔ بودھی اور جین مصنفین نے سنسکرت زبان میں بھی کئی کتب تصنیف کیں۔ اس کے بعد ہیروئی یا سورمائی ادب کا دور آتا ہے۔ ہندوستان کی مشہور ترین قدیم رزمیہ داستانیں ’’مہا بھارت‘‘ اور ’‘رامائن‘‘ ہیں جو کئی صدیوں کے دوران سنسکرت زبان میں لکھی گئیں۔ ان میں بتایا گیا ہے کہ آریاؤں نے ہندوستان پر کیسے کنٹرول حاصل کیا۔ مہا بھارت کی تحریری صورت کو افسانوی شاعر و مؤلف ویاس سے منسوب کیا جاتا ہے، لیکن اس نے 400 قبل مسیح اور 400 عیسوی کے دوران اپنی شکل اختیار کی۔ مہا بھارت اصل میں بھارت یا بھرت قبیلے کی دو شاخوں کے درمیان تنازع کی کہانی ہے۔ چوتھی صدی عیسوی کے آخر میں جنم لینے والا شاعر کالی داس ممتاز ترین کلاسیکی شعرا میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس کی رزمیہ داستانوں میں ’’رگھو وامس‘‘ اور ’’میگھ دوت‘‘ شامل ہیں۔ البتہ اس کا لکھا ہوا کھیل ’’شکنتلا‘‘ (ابھیجان شکنتلا) سب سے زیادہ مشہور ہوا۔ اس ڈرامے میں ایک بادشاہ اور جنگل باسی دوشیزہ شکنتلا کی محبت کی کہانی سنائی گئی ہے۔ جرمن مصنف گوئٹے اور دیگر یورپی اہل قلم پر بھی اس ڈرامے نے گہرا اثر ڈالا۔ سنسکرت ڈرامہ رقص، موسیقی اور شاعری سے بھرپور تھا۔ کالی داس نے مشہور ڈراموں کے علاوہ قابل ذکر کلاسیکی ڈراموں میں ’’مرچھ کٹکا‘‘ از شدرک اور ’’ملاتی مادھو‘‘ از بھوبھوتی شامل ہیں۔ کلاسیکی سنسکرت فکشن میں ’’پنچ تنتر‘‘ از وشنو شرمن سر فہرست ہے۔ گیارہویں صدی کے مصنف سوم دیو کی ’’کتھا سرت ساگر‘‘ تاجروں، بادشاہوں وغیرہ کے عشقیہ قصوں کا مجموعہ ہے۔ پنچ تنتر اور کتھا سرت ساگر نے الف لیلہ ولیلہ کے لیے بنیاد مہیا کی۔ سنسکرت شاعروں نے قطعات (مکتک) بھی لکھے۔ ساتویں صدی میں بھرتری ہری اور امارو نے مکتک کا استعمال کیا۔ سنسکرت نے درباری ادب کے ساتھ ساتھ ’’پرانوں‘‘ کی روایت کو بھی پروان چڑھایا۔ اٹھارہویں صدی کے سندھی شاعر شاہ عبداللطیف بھٹائی اور پنجابی شاعر بلھے شاہ نے کافی کی صنف کو فروغ دیا۔
البتہ مغل شہنشاہوں اکبر، جہانگیر، شاہ جہاں اور اورنگزیب نے فارسی زبان کو انتظامی، تعلیمی اور ثقافتی سطح پر متعارف کروایا اور متعدد فارسی اصناف سخن کو ہندوستان میں مقبولیت ملی۔ اس کی ایک اہم مثال اکبر کے درباری ابوالفضل کی لکھی ہوئی ’’اکبرنامہ‘‘ ہے۔ داستان کے انداز کو بھی اپنایا گیا۔ ہندوستانی سیاق و سباق میں فارسی ادب کی اہم ترین صنف غزل ہے جس پر الگ سے بات کی گئی ہے۔ مرزا غالب کی کلاسیکی غزلوں کو اعلیٰ ترین مقام حاصل ہے۔ انگریز 1700ء کی دہائی میں ہندوستان آئے اور 1800ء کی دہائی کے اوائل میں زیادہ تر ہندوستان پر قابض ہو گئے۔ 1835ء میں انگریزوں نے بالائی طبقہ کے ہندوستانیوں کے لیے انگریزی تعلیم متعارف کروائی جس کے باعث ہندوستانیوں کو مغربی خیالات، نظریات، ادبی تحریروں اور اقدار کا علم ہوا۔ ساتھ ہی ساتھ ہندوستانیوں کو اپنا ادبی اور ثقافتی ورثہ نئے زاویوں سے دیکھنے کی تحریک ملی۔ اس قسم کا ایک ترجمہ 1789ء میں سر ولیم جونز نے شکنتلا کا کیا۔ ہندوستان میں پرنٹنگ پریس کے تعارف نے اخبارات و جرائد کی اشاعت ممکن بنائی۔ ان ذرائع ابلاغ کی بدولت ہندوستانیوں کو لکھنے اور تحریریں چھپوانے کے نئے مواقع ملے۔ بنگالی نشاۃ ثانیہ اسی عہد کی پیداوار ہے۔
ہندوستان میں جدید تحریر کی اولین مثال شاعری تھی۔ مشہور اور نوبیل انعام برائے ادب یافتہ شاعر و ادیب رابندر ناتھ ٹیگور نے شاعری کی روایتی اصناف سے کام لیا، مگر جدت طرازی کے ساتھ۔ دو بنگالی نژاد خواتین شعرا تورو دت اور سروجنی نائیڈو نے انگلش زبان میں خود کو ممتاز کیا۔ تورو دت اکیس برس کی عمر میں ہی مر گئی، لیکن نائیڈو نے سیاست و ادب میں طویل شاندار کیریئر جاری رکھا۔ تامل زبان میں جدید شاعری اور نثر لکھنے والا ابتدائی ترین شاعر سبرامنیم بھارتی ہے۔ دیگر مشہور شعرا سچدآنند واتسیاین، سوریہ کانت ترپاٹھی اور مہادیوی ورما ہیں۔ ہندوستان ادب میں ناول اور افسانہ دونوں ہی نئی اصناف تھے اور انیسویں صدی کے زیادہ تر ہندوستانی ادیبوں نے انہی میں طبع آزمائی کی۔ نئے اہل قلم کا تعلق انگریزی تعلیم کے حامل ہندوستانی طبقے سے تھا اور بنگالی نشاۃ ثانیہ نے ان پر گہرا اثر ڈالا۔ شاعر رابندر ناتھ ٹیگور نے شاعری کے علاوہ بنگالی ناول اور افسانے میں بھی نام کمایا۔ اس کے ہم عصر بنکم چندر چیٹرجی نے انگلش میں ایک ناول ’’Rajmohan’s Wife‘‘ (1864ء) لکھنے کے بعد بنگالی زبان کو ذریعۂ اظہار بنایا۔ دیگر علاقوں کے مصنفین بھی 1800ء کی دہائی کے آخر میں سرگرم ہونے لگے۔ گجراتی زبان میں گوور دھنرم کا ناول ’’سرسوتی چندر‘‘ (1887ء) اور چندو میمن کی ملیالم ’’اندو لیکھا‘‘ (1889ء) قابل ذکر ہیں۔ ان تحریروں کے مرکزی کردار عموماً عورتیں ہیں۔ خانگی زندگی کے مسائل بنگالی ناول نگاروں، مثلاً شرت چندر چیٹری اور اشاپورن دیوی کی تحریروں کا مرکزی موضوع بنے۔ انیسویں صدی کے آخر میں ہندوستانی متوسط طبقے کی خواتین بھی سامنے آئیں، مثلاً پنڈتا راما بائی سرسوتی اور رقیہ سخاوت حسین۔ پہلی اور دوسری عالمی جنگوں کے درمیانی دور میں تین تحریکوں نے ہندوستانی تحریر کو مہمیز دلائی اور متاثر کیا۔ موہن داس گاندھی کی شروع کی ہوئی عدم تعاون، مارکسزم اور سوشل ازم۔ راجا راؤ نے انگریزی ناول ’’کنٹھ پور‘‘ (1938ء) لکھا، جبکہ ملک راج آنند کے دو ناولوں ’’اچھوت‘‘ اور ’’قلی‘‘ کو شہرت ملی۔ منشی پریم چند کا ناول ’’گئو دان‘‘ (36ء) اور بنگالی بندیوپادھیائے کا ’’پتلی کی کہانی‘‘ (57ء) سماجی حقیقت پسندی اور ناانصافی پر تنقید پر زور دیتے ہیں۔ اسی دور میں سر محمد اقبال نے بطور شاعر اور مفکر مقبولیت حاصل کی۔ آر کے نارائن نے اپنے انگریزی ناول ’’Swami and Friends‘‘ (35ء) کے ساتھ کیریئر شروع کیا اور اس کے ناول اپنے کرداروں کے سماجی پن اور انسانی تعلقات پر زور دینے کی وجہ سے معاصر تحریروں میں الگ مقام رکھتے ہیں۔ 1947ء میں ہندوستان مشرقی و مغربی پاکستان اور ہندوستان میں تقسیم ہوا اور ان علاقوں کے ادب کی تاریخ موزوں عنوانات کے تحت دی گئی ہے، جیسے ’’پاکستانی ادب‘‘ اور ’’بنگالی ادب۔‘‘ آزادی کے بعد ایک طرف جوش وخروش اور ولولہ تھا تو دوسری طرف تقسیم کے فسادات کا دکھ۔ بالخصوص پنجاب اور بنگال تقسیم سے متاثر ہوئے۔ 1947ء سے بعد کا زیادہ تر پاکستانی اور ہندوستانی ادب تقسیم پر ہی مرکوز ہے۔ اس کے علاوہ بڑھتی ہوئی بین الاقوامیت نے بھی برصغیر پر اثر ڈالا۔
(تحریر: یاسر جواد، انسائیکلو پیڈیا ادبیاتِ عالم سے ماخوذ)