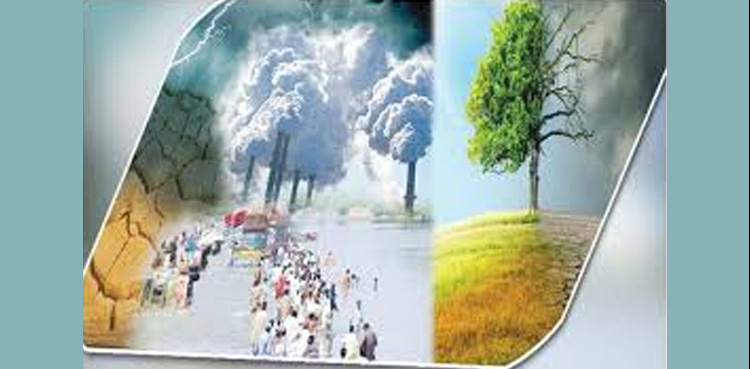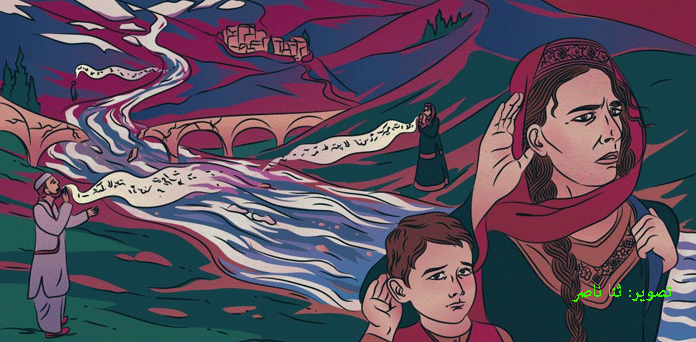تیس سالہ مٹھو کا گھر پاکستان کے دو کروڑ کی آبادی والے سب سے بڑے شہر کراچی میں کے پی ٹی انٹرچینج فلائی اوور کے نیچے ہے۔ مٹھو کے ساتھ اُن کے بیس عزیز و اقربا بھی ساتھ رہتے ہیں جو کئی سال پہلے بہتر معاشی مواقع کی تلاش میں دو سو کلومیٹر شمال مشرق میں واقع ٹنڈو الہ یار سے ہجرت کر کے یہاں آئے تھے۔ آس پاس کے بلند و بالا اپارٹمنٹس اور دفاتر میں رہنے والے لوگوں کے برعکس، اِن کے پاس سخت موسمی حالات سے بچنے کے لئے فی الحقیقت کوئی پناہ گاہ موجود نہیں ہے۔
جولائی کے آخر کی جُھلسا دینے والی گرمی کے ایک دن جب ان کی بہن سوتری سرخ اینٹوں کے عارضی چولہے پر روٹیاں بنا رہی تھیں تو اُس وقت مٹھو نے اپنے ماتھے سے پسینہ پونچھتے ہوئے بتایا کہ “ہمیں رفع حاجت یا غسل کے لئے خالی پلاٹوں پر جانا پڑتا ہے، چاہے اِس طرح کی شدید گرمی ہی کیوں نہ ہو۔ ہم یہاں پانی قریبی کالونیوں سے خالی ڈبوں میں بھر کر لاتے ہیں۔ حکومت ہمارے لئے کیا کرے گی؟ ہمیں حکومت پر بھروسہ نہیں ہے کہ وہ ہمیں شدید گرمی کے دوران یا بارشوں میں ہماری مدد کرے گی۔”
کراچی میں بے گھر افراد کی تعداد کے حوالے سے کوئی قابل اعتماد اعداد و شمار موجود نہیں ہیں، جس کی وجہ سے شدید گرمی اور بارشوں سے نمٹنے میں اِن کی مدد کے لئے کسی قسم کی کوئی منصوبہ بندی نہیں کی گئی ہے
مٹھو کا خاندان، بہت سے دوسرے لوگوں کی طرح، کسی بھی سرکاری اعداد و شمار میں شامل نہیں ہے۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی ڈائریکٹر برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی اسماء غیور نے ڈائیلاگ ارتھ کو بتایا کہ “آپ کو اِن بے گھر افراد کے بارے میں کوئی اعداد و شمار، ڈیٹا، یا منصوبے نہیں ملیں گے۔ زیادہ سے زیادہ، یہ لوگ انتخابات کے قریب ممکنہ ووٹرز کے طور پر کام آسکتے ہیں۔ اِس سے ہٹ کر، اِن کے مسائل کو بڑی حد تک نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔”
1988 میں قائم ہونے والی ایک غیر منافع بخش تنظیم شہری – سٹیزن فار اے بیٹر انوائرنمنٹ (سی بی ای) کی جنرل سکریٹری امبر علی بھائی نے بے گھر افراد کو “اِس بڑے شہر کے کسی کو نظر نہ آنے والے لوگ” قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ “آب و ہوا سے پیدا ہونے والی آفات جیسے سیلاب کے دوران پولیس اِن بے گھر افراد کو پولیس اسٹیشنوں میں عارضی پناہ دے سکتی ہے، لیکن اُن کے پاس بھی مناسب جگہ کی کمی ہوتی ہے، لہذا اِن بے گھر افراد کو عام طور پر کسی دوسرے مقام پر منتقل کر دیا جاتا ہے۔ اِن بے گھر افراد کی نگرانی اور اِن کا ڈیٹا اکٹھا کرنے کے لئے نادرا [نیشنل ڈیٹا بیس اینڈ رجسٹریشن اتھارٹی] کو بھی اِس مربوط عمل میں شامل کرنا ضروری ہے۔”
شہری منصوبہ ساز اور کراچی اربن لیب کے ایسوسی ایٹ ڈائریکٹر محمد توحید نے بے گھر افراد کی مدد کے حوالے سے موجودہ مشکلات پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ ” جب تک بے گھر افراد کی صحیح تعداد اور ان کے مقامات کا علم نہ ہو، وسائل مختص کرنا، ہنگامی ردعمل کی منصوبہ بندی کرنا، اور ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے طویل مدتی حل نافذ کرنا مشکل ہے۔” یہ مسائل شدید گرمی کے واقعات سے کہیں زیادہ ہیں۔ کچھ سول سوسائٹی کی تنظیموں کا کہنا ہے کہ پاکستان میں مجموعی طور پر بے گھر افراد کی آبادی تقریبا 20 ملین (دو کروڑ) یا اِس کی آبادی کا 9 فیصد ہے، لیکن سول سوسائٹی کے شعبے میں بھی کراچی جیسے شہروں کے بارے میں کوئی خاص معلومات موجود نہیں ہیں اور اِن مسائل کو حکومتی سطح پر اُجاگر کرنے کے لئے اعداد و شمار ناکافی ہیں۔
علی بھائی نے کہا کہ بے گھر افراد سے نمٹنے کے لئے موجودہ قوانین، جیسے سندھ ویگرنسی آرڈیننس 1958 اور اس کی 1983 کی ترمیم کے باوجود، کراچی میٹرو پولیٹن کارپوریشن (کے ایم سی) نے “اپنی ذمہ داریوں سےمکمل کنارہ کشی اختیار کر لی ہے۔” انہوں نے مزید کہا کہ جب آب و ہوا سے پیدا ہونے والی آفات، جیسے گرمی کی لہریں یا شہر میں سیلاب آتے ہیں تو متاثرہ افراد کو خیرات دینے والے افراد کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔
رؤف فاروقی، جو 2013 سے 2015 کے درمیان کراچی اور اس کے گرد و نواح کے علاقوں کے لئے کے ایم سی کے سب سے اعلیٰ انتظامی عہدے پر فائز رہے، نے ڈائیلاگ ارتھ کو بتایا کہ بے گھر افراد کے لئے کوئی سرکاری اہتمام نہیں ہے۔ انہوں نے کہا، “زیادہ سے زیادہ، ہم اِنہیں عارضی پناہ کے لئے پولیس کے پاس یا ایدھی فاؤنڈیشن کے پاس لے جاتے تھے۔”
پاکستان کے محکمہ موسمیات کے چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز نے کہا کہ موسم کی شِدّت سے بچاؤ کے لئے انتظامات نہ ہونے کی وجہ سے کراچی کے بے گھر افراد کو اِس موسم گرما میں شدید گرمی کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ 23 سے 30 جون کے دوران اور 16 سے 23 جولائی کے دوران درجہ حرارت اوسط سے 4 سے 6 ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ رہا۔ “1990 کی دہائی کے وسط سے پاکستان میں درجہ حرارت میں مسلسل اضافہ دیکھا گیا ہے۔ اِس میں کوئی شبہ نہیں کہ موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے بے گھر افراد سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔”
ایدھی فاؤنڈیشن، جو پاکستان کی محروم طبقے کی کمیونٹیز کی خدمت کرنے والی ایک سماجی تنظیم ہے، کے کنٹرول روم کے انچارج محمد امین نے بتایا کہ اس سال اموات میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ “15 سے 30 جون کے درمیان، ہمیں اپنے مردہ خانوں میں 1,540 لاشیں موصول ہوئیں جو کہ روزانہ کی اوسطاً 35 سے 40 لاشوں کے مقابلے میں تین گنا زیادہ ہیں۔” اس کے ساتھ ہی انہوں نے متنبہ کیا کہ اِن سب ہلاکتوں کو پوری طرح سے گرمی کے اثرات سے منسلک نہیں کیا جا سکتا۔ تاہم، سول سوسائٹی کی تنظیموں کی جانب سے رپورٹ کی جانے والی ہلاکتوں کی بڑی تعداد نے اس سال جون کے آخر میں آٹھ روز تک چلنے والی گرمی کی لہروں کے دوران سرکاری طور پر 49 اموات کے بارے میں سوالات اٹھائے ہیں۔
ڈاکٹر احمر، جو کراچی کے گنجان آباد علاقے صدر میں واقع کراچی ایڈوینٹسٹ اسپتال کے ایمرجنسی روم میں کام کرتے ہیں نے کہا کہ انکا پورا نام ظاہر نہ کیا جائے۔ انہوں نے بتایا کہ انہیں اس سال گرمی سے متعلق ہر قسم کے کیسز موصول ہوئے اور خاص طور وہ لوگ جو کسی مناسب چھت یا سایہ سے محروم ہیں وہ لُو ، تیز بخار، لو بلڈ پریشر اور چکر جیسی علامات کے ساتھ آئے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ اگر مون سون کی بارشیں جاری رہیں تو آلودہ پانی کی وجہ سے اسپتال گیسٹرو اینٹرائٹس (معدے اور آنتوں کی سوزش) کے مریضوں سے بھر جائے گا۔ جہاں تک بے گھر لوگوں کا تعلق ہے تو میں نے ان کے لئے کوئی خاص انتظامات یا اقدامات نہیں دیکھے ہیں۔ وہ تمام عملی مقاصد کے لئے غیر رجسٹرڈ شہری ہیں حالانکہ وہ واقعی بہت سی مصیبتوں کا شکار ہیں۔
صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی (پی ڈی ایم اے) سندھ کے ڈائریکٹر جنرل سید سلمان شاہ نے کراچی میں 2015 میں گرمی کی لہروں کے بعد کی صورتحال پر روشنی ڈالی، جس کے بعد ہیٹ ویومینجمنٹ پلان تشکیل دیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ ان کے جائزے سے پتہ چلتا ہے کہ گرمی کی لہروں میں بے گھر افراد یا سڑکوں کے کنارے مقیم افراد سب سے زیادہ متاثر ہوئے۔ 2015 میں رمضان المبارک کے موقع پر آنے والی گرمی کی لہروں نے پاکستان بھر سے بہت سے لوگوں کو خیراتی امداد کے لئے کراچی کی طرف راغب کیا جس کی وجہ سے صورتحال مزید خراب ہو گئی تھی۔ انہوں نے مزید کہا کہ “یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس عام طور پر گھر نہیں ہوتے اور وہ غیر سرکاری بستیوں، عارضی خیموں یا فلائی اوورز کے نیچے بیٹھے رہتے ہیں۔ 2024 کے منصوبے میں خاص طور پر شدید گرمی کی لہروں کے دوران بے گھر افراد کو عارضی پناہ گاہیں فراہم کرنا شامل تھا اور اِس کے لئے شادی ہالز اور سرکاری دفاتر جیسی عمارتوں کو استعمال میں لایا جائے گا۔
شاہ کے مطابق، اگرچہ سرکاری محکموں نے اس سال گرمی کی لہروں سے قبل شہریوں کی جانب سے محسوس کئے جانے والے اثرات کو کم کرنے کے لئے کام کیا تھا، لیکن یہ غیر متوقع طور پر طویل ثابت ہوا۔ اُن کا کہنا تھا کہ “صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی (پی ڈی ایم اے) بار بار گرمی کی لہروں کے حوالے سے الرٹ اور روزانہ کی صورتحال کی رپورٹس جاری کرتی ہے لیکن کراچی میں بے گھر افراد کی صحیح تعداد کوئی نہیں جانتا،” حالانکہ انہوں نے توقع ظاہر کی کہ کراچی میں لوگوں کی اصل تعداد زیادہ ہوگی کیونکہ شہر میں بہتر زندگی کی تلاش میں لوگوں کا مسلسل آنا جاری رہتا ہے۔
سیلاب سے نمٹنے کے لئے تین سال قبل نالوں پر غیر قانونی طور پر تعمیر کی گئی عمارتوں کو منہدم کرنے کے لئے انسدادِ تجاوزات مہم شروع کی گئی تھی جس سے نادانستہ طور پر شہر میں بے گھر افراد کی تعداد میں اضافہ ہوا۔ اپریل میں سپریم کورٹ نے صوبائی حکومت کو ہدایت دی کہ اِن عمارتوں کے اِنہدام کی وجہ سے بے گھر ہونے والے لوگوں کو نئے مکانات مہیّا کئے جائیں۔
شہر کے انفرااسٹرکچر(بنیادی ڈھانچے) کے منصوبوں کی نگرانی کرنے والے سول سوسائٹی کے ادارے اربن ریسورس سینٹر کے جوائنٹ ڈائریکٹر زاہد فاروق نے اس طرح کی پالیسیوں کے وسیع اثرات پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے بتایا کہ “گجر اور اورنگی نالوں کے اوپر بنی عمارتوں کو ہٹانے کے نتیجے میں 6،900 ہاؤسنگ یونٹس منہدم ہوئیں اور ہر گھر میں ممکنہ طور پر ایک سے زیادہ خاندان رہائش پذیر تھے۔ بے گھر ہونے کے بعد وہ کسی رشتہ دار کے گھر چلے جاتے ہیں جو کہ خود بھی غریب ہوتے ہیں۔” انہوں نے کہا، “چونکہ ایک بڑی تعداد پہلے ہی تنگ حالات میں رہ رہی ہے، اُس پر بے گھر رشتہ داروں کی آمد، چھوٹے گنجان مکانات یا عارضی پناہ گاہوں میں رہائشی کثافت (کم جگہ میں زیادہ لوگوں کا رہنا) کو مزید بڑھا دیتی ہے۔ یہ بڑھتی ہوئی کثافت موسمیاتی واقعات جیسے گرمی کی لہروں یا شدید بارشوں کے اثرات کو بڑھا دیتی ہے۔” فاروق نے مزید کہا، ” گھروں کا یہ انہدام صرف اِن کے گھروں کو ہی نہیں مِسمار کرتا بلکہ اِن کی معاشی حالت، سماجی شناخت اور روابط بھی بکھر جاتے ہیں۔”
ایک مقامی دائی نیہا منکانی جو غریب کمیونٹیز کے لئے ذہنی صحت کے کلینک چلا رہی ہیں، کے مطابق بے گھر خواتین کی حالت خاص طور پر سنگین ہے۔ انہوں نے کہا کہ “کراچی میں بے گھر خواتین کو سیلاب اور گرمی کی لہروں کے دوران صحت کے حوالے سے مقابلتاً بڑے خطرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آلودہ سیلابی پانی انفیکشن، جلد کی بیماریوں اور ذہنی صحت کے مسائل کے لئے اُن کی حسّاسیت بڑھا دیتا ہے، اور ایسا بے گھر ہونے اور جذباتی صدمے کی وجہ سے ہوتا ہے۔” اس کے علاوہ، جب سیلاب آتا ہے تو لوگ ایک ساتھ ہجوم والی جگہوں پر رہنے کے لئے جاتے ہیں اور ایسے مواقع خواتین کے لئے جنسی تشدد کے خطرے کو بڑھا سکتے ہیں۔ علاوہ ازیں، غیر مستحکم غذائی ذرائع شدید موسم سے مزید متاثر ہوتے ہیں اور نتیجتاّ اِن خواتین کو کھانا بھی اچھی مقدار میں نہیں ملتا اور یہ غذائی قلت اور معدے کے مسائل کا شکار ہو جاتی ہیں۔
منکانی نے گرمی کی شدید لہروں کے دوران خواتین کی صحت کے تحفظ کے لئے مخصوص علاجوں کی ضرورت پر زور دیا، اور محفوظ پانی اور صفائی ستھرائی تک ان کی محدود رسائی کو اجاگر کیا جس سے پانی کی کمی، پیشاب کی نالی کے انفیکشن اور حمل میں پیچیدگیوں کے خطرات میں اضافہ ہوتا ہے جس میں قبل از وقت زچگی اور حمل کا نقصان بھی شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ “یہ تسلیم کرنا بہت ضروری ہے کہ خواتین، خاص طور پر وہ جو مناسب پناہ گاہ سے محروم ہیں، گرمی سے مقابلتاً زیادہ متاثر ہوتی ہیں، اور یہ نکتہ اُن کی صحت اور فلاح و بہبود کے تحفظ کے لئے مخصوص علاجوں اور اُنھیں صحت مند رکھنے کے نظام کی ضرورت کو اجاگر کرتا ہے۔”
(فرح ناز زاہدی معظم کی رپورٹ ڈائلاگ ارتھ پر شایع ہوچکی ہے جس کو اس لنک کی مدد سے پڑھا جاسکتا ہے)