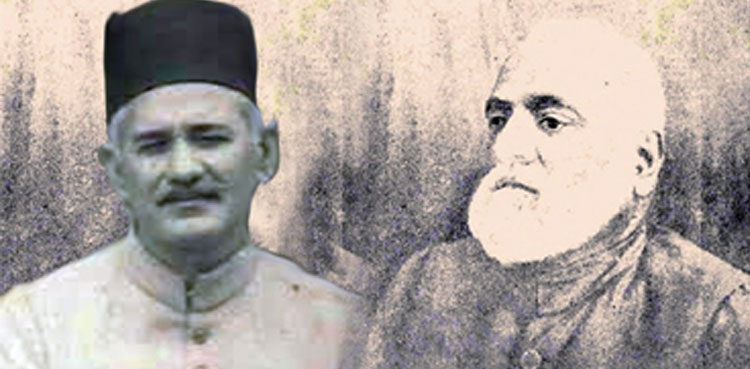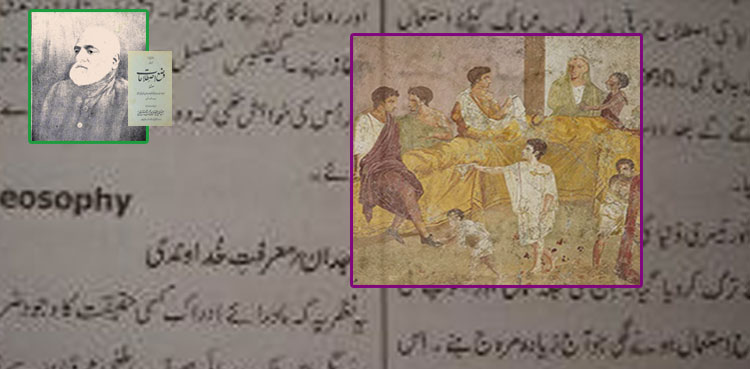خدا بخشے مولوی وحید الدّین ‘سلیم’ بھی ایک عجیب چیز تھے۔ ایک نگینہ سمجھیے کہ برسوں ناتراشیدہ رہا۔ جب تراشا گیا۔ پھل نکلے، چمک بڑھی، اہلِ نظر میں قدر ہوئی۔ اس وقت چٹ سے ٹوٹ گیا۔
شہرت بھی ‘غالب’ کے قصیدے کی طرح آج کل کسی کو راس نہیں آتی۔ ادھر نام بڑھا اور ادھر مرا۔ صف سے آگے نکلا اور تیر قضا کا نشانہ ہوا، چلچلاؤ کا زور ہے۔ آج یہ گیا، کل وہ گیا، مولوی نذیر احمد گئے۔ شبلی گئے، حالی گئے، وحید الدّین گئے۔ اب بڑوں میں مولوی عبدالحق رہ گئے۔ ان کو بھی شہرت کی ریا لگ گئی ہے۔ سوکھے چلے جا رہے ہیں۔ کسی دن یہ بھی خشک ہو کر رہ جائیں گے۔
یہ تو جو کچھ تھا، سو تھا، ایک نئی بات یہ ہے کہ آج کل کا مرنا بھی کچھ عجب مرنا ہو گیا ہے۔ پہلے زندگی کو چراغ سے تشبیہ دیتے تھے، بتی جلتی، تیل خرچ ہوتا، تیل ختم ہونے کے بعد چراغ جھلملاتا، تمٹماٹا، لو بیٹھنی شروع ہوتی اور آخر رفتہ رفتہ ٹھنڈا ہو جاتا۔ اب چراغ کی جگہ زندگی، بجلی کا لیمپ ہو گئی ہے۔ ادھر بٹن دبایا، ادھر اندھیرا گھپ۔ عظمت اللہ خان، اسی طرح مرے، مولوی وحید الدّین اسی طرح رخصت ہوئے، اب دیکھیں کس کی باری ہے۔ اردو کی مجلس میں دو چار لیمپ جل رہے ہیں۔ وہ بھی کسی وقت کھٹ سے گُل ہوجائیں گے۔ اس کے بعد بس اللہ ہی اللہ ہے۔
میں مدت سے حیدرآباد میں ہوں۔ مولوی وحید الدّین بھی برسوں سے یہاں تھے، لیکن کبھی ملنا نہیں ہوا۔ انہیں ملنے سے فرصت نہ تھی۔ مجھے ملنے کی فرصت نہ تھی۔ آخر ملے تو کب ملے کہ مولوی صاحب مرنے کو تیار بیٹھے تھے۔
گزشتہ سال کالج کے جلسہ میں مولوی عبدالحق صاحب نے مجھے اورنگ آباد کھینچ بلایا۔ روانہ ہونے کے لیے جو حیدرآباد کے اسٹیشن پر پہنچا، تو کیا دیکھتا ہوں کہ اسٹیشن کا اسٹیشن اورنگ آباد جانے والوں سے بھرا پڑا ہے۔ طالبِ علم بھی ہیں، ماسٹر بھی ہیں۔ کچھ ضرورت سے جا رہے ہیں، کچھ بےضرورت چلے جا رہے ہیں۔ کچھ واقعی مہمان ہیں، کچھ بن بلائے مہمان ہیں۔ غرض یہ کہ آدھی ریل انہی اورنگ آباد کے مسافروں نے گھیر رکھی ہے۔ ریل کی روانگی میں دیر تھی۔ سب کے سب پلیٹ فارم پرکھڑے گپیں مار رہے تھے۔ میں بھی ایک صاحب سے کھڑا باتیں کر رہا تھا کہ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بڑے میاں بھیڑ کو چیرتے پھاڑتے، بڑے بڑے ڈگ بھرتے، میری طرف چلے آ رہے ہیں۔ متوسط قد، بھاری گٹھیلا بدن، بڑی سی توند، کالی سیاہ فام رنگت، اس پر سفید چھوٹی سی گول ڈاڑھی، چھوٹی چھوٹی کرنجی آنکھیں، شرعی سفید پائجامہ، کتھئی رنگ کے کشمیرے کی شیروانی، سر پر عنابی ترکی ٹوپی، پاؤں میں جرابیں اور انگریزی جوتا۔ آئے اور آتے ہی مجھے گلے لگا لیا۔
حیران تھا کہ یا الٰہی یہ کیا ماجرا ہے۔ کیا امیر حبیب اللہ خان اور مولوی نذیر احمد مرحوم کی ملاقات کا دوسرا سین ہونے والا ہے۔ جب ان کی اور میری ہڈیاں پسلیاں گلے ملتے ملتے تھک کر چور ہو گئیں۔ اس وقت انہوں نے فرمایا:
"میاں فرحت! مجھے تم سے ملنے کا بڑا شوق تھا۔ جب سے تمہارا نذیر احمد والا مضمون دیکھا ہے ۔ کئی دفعہ ارادہ کیا کہ گھر پر آکر ملوں۔ مگر موقع نہ ملا۔ قسمت میں ملنا تو آج لکھا تھا۔ بھئی! مجھے نذیر احمد کی قسمت پر رشک آتا ہے کہ تجھ جیسا شاگرد اس کو ملا، مرنے کے بعد بھی ان کا نام زندہ کر دیا۔ افسوس ہے ہم کو کوئی ایسا شاگرد نہیں ملتا جو مرنے کے بعد اسی رنگ میں ہمارا حال بھی لکھتا۔”
میں پریشان تھا کہ یااللہ یہ ہیں کون اور کیا کہہ رہے ہیں؟ مگر میری زبان کب رکتی ہے، میں نے کہا:
"مولوی صاحب! آپ گھبراتے کیوں ہیں۔ بسم اللہ کیجیے، مر جائیے، مضمون میں لکھ دوں گا۔”
کیا خبر تھی کہ سال بھر کے اندر ہی اندر مولوی صاحب مر جائیں گے۔ اور مجھے ان کی وصیت کو پورا کرنا پڑے گا۔ جب مجھے معلوم ہوا کہ یہ مولوی وحید الدّین سلیم ہیں تو واقعی مجھے بہت پشیمانی ہوئی۔ میں نے معذرت کی، وہ خود شگفتہ طبیعت لے کر آئے تھے، رنج تو کجا بڑی دیر تک ہنستے اور اس جملے کے مزے لیتے رہے۔ سر ہو گئے کہ جس گاڑی میں تُو ہے میں بھی اسی میں بیٹھوں گا۔
شاگردوں کی طرف دیکھا، انہوں نے ان کا سامان لا، میرے درجے میں رکھ دیا۔ ادھر ریل چلی، اور ادھر ان کی زبان چلی۔ رات کے بارہ بجے، ایک بجا، دو بج گئے، مولوی صاحب نہ خود سوتے ہیں اور نہ سونے دیتے ہیں۔ درجۂ اوّل میں ہم تین آدمی تھے۔ مولوی صاحب اور رفیق بیگ۔ رفیق بیگ تو سو گئے، ہم دونوں نے باتوں میں صبح کر دی۔ اپنی زندگی کے حالات بیان کیے اپنے علمی کارناموں کا ذکر چھیڑا، اصطلاحاتِ زبانِ اردو پر بحث ہوتی رہی، شعر و شاعری ہوئی، دوسروں کی خوب خوب برائیاں ہوئیں، اپنی تعریفیں ہوئیں۔ مولوی عبدالحق کو برا بھلا کہا کہ اس بیماری میں مجھے زبردستی کھینچ بلایا۔ غرض چند گھنٹے بڑے مزے سے گزر گئے۔
صبح ہوتے ہوتے کہیں جاکر آنکھ لگی۔ شاید ہی گھنٹہ بھر سوئے ہوں گے کہ ان کے شاگردوں اور ساتھیوں نے گاڑی پر یورش کر دی۔ پھر اٹھ بیٹھے اور پھر وہی علمی مباحث شروع ہوئے، پھبتیاں اڑیں، اس کو بے وقوف بنایا، اس کی تعریف کی، ہنسی اور قہقہوں کا وہ زور تھا کہ درجہ کی چھت اڑی جاتی تھی۔
(ایک وصیت کی تعمیل از مرزا فرحت اللہ بیگ)