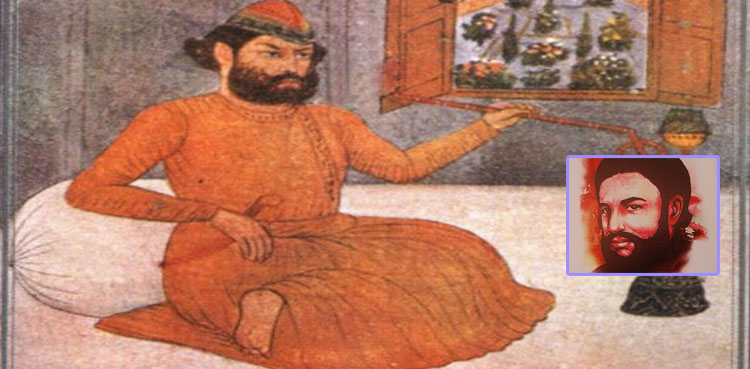کہا جاتا ہے کہ مولانا حسرت موہانی نے سرتاج الشّعرا میر تقی میر کے اُن بہتّر اشعار کا انتخاب کیا تھا جو ان کی نظر میں میر کے بہترین اشعار تھے یہ میر کے بہتّر نشتر کے نام سے مشہور ہیں۔
حسرت نے یہ انتخاب اپنے رسالے اردوئے معلٰی میں شایع کیا تھا، لیکن آج وہ انتخاب کسی کے علم میں نہیں ہے۔ میر تقی میر کو اپنے کلام کی وقعت اور اپنی عظمت کا بہت احساس تھا، سو یہ تعلّی انھیں زیب دیتی ہے:
جانے کا نہیں شور سخن کا مِرے ہرگز
تا حشر جہاں میں مِرا دیوان رہے گا
خدائے سخن کہلانے والے میر تقی میرؔ نے 1810ء میں آج ہی کے دن وفات پائی تھی۔ آج بھی میر اور ان کے بہتّر نشتر اشعار کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ میر کے یومِ وفات کی طرح ان کے جائے مدفن پر بھی اختلاف ہے۔ ان کی آخری آرام گاہ کے بارے میں بھی کسی کو کچھ معلوم نہیں اور لکھنؤ میں ایک جگہ کو ان کی قبر بتایا جاتا ہے۔
میر تقی میر نے مختلف اصنافِ سخن میں طبع آزمائی کی، لیکن غزل میں ان کی غم انگیز لے اور ان کا شعورِ فن اور ہی مزہ دیتا ہے۔ انھوں نے کہا تھا:
مجھ کو شاعر نہ کہو میرؔ کہ صاحب میں نے
درد و غم کتنے کیے جمع تو دیوان کیا
ہوتے ہوئے بھی ایک عمومی رنگ رکھتے ہیں
نام وَر ادیب اور نقّاد رشید احمد صدیقی لکھتے ہیں۔ "آج تک میر سے بے تکلف ہونے کی ہمت کسی میں نہیں ہوئی۔ یہاں تک کہ آج اس پرانی زبان کی بھی نقل کی جا تی ہے جس کے نمونے جہاں تہاں میر کے کلام میں ملتے ہیں لیکن اب متروک ہو چکے ہیں۔ بر بنائے عقیدت کسی کے نقص کی پیروی کی جائے، تو بتایئے، وہ شخص کتنا بڑا ہوگا۔”
میرؔ کے آبا و اجداد کا تعلق حجاز سے تھا۔ وہاں سے نقل مکانی کر کے ہندوستان آئے۔ اس سر زمین پر اوّل اوّل جہاں قدم رکھے، وہ دکن تھا۔ دکن کے بعد احمد آباد، گجرات میں پڑاؤ اختیار کیا۔ میرؔ کے والد کا نام تذکروں میں میر محمد علی لکھا گیا ہے اور وہ علی متّقی مشہور تھے۔ میرؔ کے والد درویش صفت اور قلندرانہ مزاج رکھتے تھے۔ میرؔ نے اکبر آباد (آگرہ) میں 1723ء میں جنم لیا۔ تنگ دستی اور معاشی مشکلات دیکھیں۔ والد کی وفات کے بعد مزید مصائب اٹھائے۔ ان کا زمانہ بڑا پُر آشوب تھا۔ سلطنتِ مغلیہ زوال کی طرف گام زن تھی اور شاہانِ وقت، نواب و امراء سبھی بربادی دیکھ رہے تھے۔ میر نے دلّی چھوڑی اور لکھنؤ پہنچ گئے اور وہیں زندگی بھی تمام کی۔
محمد حسین آزاد اپنی کتاب ’آب حیات‘ میں لکھنؤ کے مشاعرے میں شرکت کے موقع پر اُن کا حلیہ کچھ اس طرح سے بیان کرتے ہیں: ’ان کی وضع قدیمانہ، کھڑکی دار پگڑی، پچاس گز کے گھیر کا جامہ، ایک پورا تھان پستولیے کا کمر سے بندھا، ایک رومال پٹری دار تہ کیا ہوا، ناگ پھنی کی انی دار جوتی، جس کی ڈیڑھ بالشت اونچی نوک، کمر میں ایک طرف سیف یعنی سیدھی تلوار، دوسری طرف کٹار۔
دلّی میں تو میر اپنے اور چند ہم عصروں کا تذکرہ یوں کرتے تھے، ’دلّی میں صرف ڈھائی شاعر ہیں۔ ایک میں، ایک سودا اور آدھا میر درد۔‘ میر نے درد کو آدھا شاعر اس لیے کہا تھا کیوں کہ وہ صرف غزل کے شاعر تھے جب کہ اس دور میں شاعر مثنوی، قصیدہ، رباعیات میں بھی طبع آزمائی کرتے تھے۔
آل احمد سرور لکھتے ہیں، میرؔ کو بچپن ہی میں مہربان ’’چچا‘‘ اور شفیق باپ کی موت کی وجہ سے ایک محرومی کا احساس ہوا۔ بھائی نے ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ چنانچہ محرومی کے احساس میں ظلم کا احساس بھی شامل ہو گیا۔ دہلی میں انہیں خان آرزو جیسے سنجیدہ اور ثقہ آدمی کی صحبت ملی مگر خان آرزوؔ کی شفقت انھیں نصیب نہ ہوئی۔ قصور خاں آرزوؔ کا زیادہ ہے یا میرؔ کا۔ اس کے متعلق کوئی قطعی بات نہیں کہی جا سکتی مگر یہ کہا جا سکتا ہے کہ خاں آرزوؔ میرؔ کے اطوار سے خوش نہ تھے۔ یہ اطوار اخلاقی اعتبار سے کتنے ہی قابل اعتراض کیوں نہ ہوں ان کی شاعری کو سمجھنے کے لیے بہت اہم ہیں۔ مجھے تو کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک عالم اور ایک ’‘رند‘‘ کے مزاج میں جو فرق ہو سکتا ہے وہ یہاں بھی موجود تھا۔ اس فرق نے اپنا رنگ دکھایا۔ میرؔ، خان آرزو سے رخصت ہوئے، ایک گھنے سایہ دار درخت کا سایہ ان کے لیے عذاب ہوگیا۔ انھوں نے کڑی دھوپ کی آزادی پسند کی اور اس سائے میں جو چوٹیں ان کے دماغ پر لگی تھیں انھیں ساتھ لیے ہوئے اپنی انانیت کے سہارے زندگی کے خارزار میں مردانہ وار نکل کھڑے ہوئے۔
مؤرخ رعنا صفوی میر کی قبر کے بارے میں کہتی ہیں کہ لکھنؤ میں میر کی قبر اور قبرستان اب صرف تاریخ کا حصہ رہ گئے ہیں۔ مؤرخین اور مداحوں نے ان کی قبر تلاش کرنے کی کوشش کی تو اس نتیجے پر پہنچے کہ انگریزوں کے زمانے میں اس پر ریل کی پٹری بچھا دی گئی تھی۔ صفوی، جن کی پرورش 1960 کی دہائی میں لکھنؤ میں ہوئی، بتاتی ہیں کہ ان کا گھر ان ہی ریل کی پٹریوں کے سامنے تھا۔ وہ کہتی ہیں کہ ’پٹری کے کنارے وہاں ایک دروازہ ہوا کرتا تھا، جسے بڑے بزرگ کہتے تھے کہ وہاں میر کی قبر ہوا کرتی تھی۔‘
آج وہاں سے کچھ قدم دور میر کے نام سے ’نشانِ میر‘ نامی ایک علامتی ڈھانچہ ہے اور اس کا بھی حال بُرا ہے۔ دستیاب تاریخی ریکارڈ سے ظاہر ہے کہ اکھاڑہ بھیم نامی مقام پر میر کا قبرستان تھا لیکن اب وہ علاقہ اکھاڑہ بھیم کے نام سے جانا بھی نہیں جاتا۔
آل احمد سرور نے میر پر اپنے مضمون میں لکھا ہے، میرؔ بہرحال اپنے دور کی پیداوار ہیں لیکن ان کی شاعری کی اپیل آفاقی ہے، وہ اپنے اظہار میں اپنے دور سے بلند بھی ہو جاتے ہیں اور ذہن انسانی کے ایسے سربستہ رازوں سے بھی پردہ اٹھاتے ہیں جو ہر دور کے لیے کشش رکھتے ہیں۔ کارگہ شیشہ گری کا کام صرف میرؔ کے زمانے میں ہی نازک نہیں تھا، آج بھی نازک ہےاور اگرچہ آج سانس آہستہ لینے کا زمانہ نہیں ہے پھر بھی اس شعر کو پڑھ کر تھوڑی دیر کے لئے ہم سانس روک لیتے ہیں اور ہمیں یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ موجودہ دور کے سارے کمالات کے باوجود جسم و جان کا رشتہ ایک ڈورے سے بھی زیادہ نازک ہے اور زندگی ایک پل صراط کی طرح ہے جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے۔